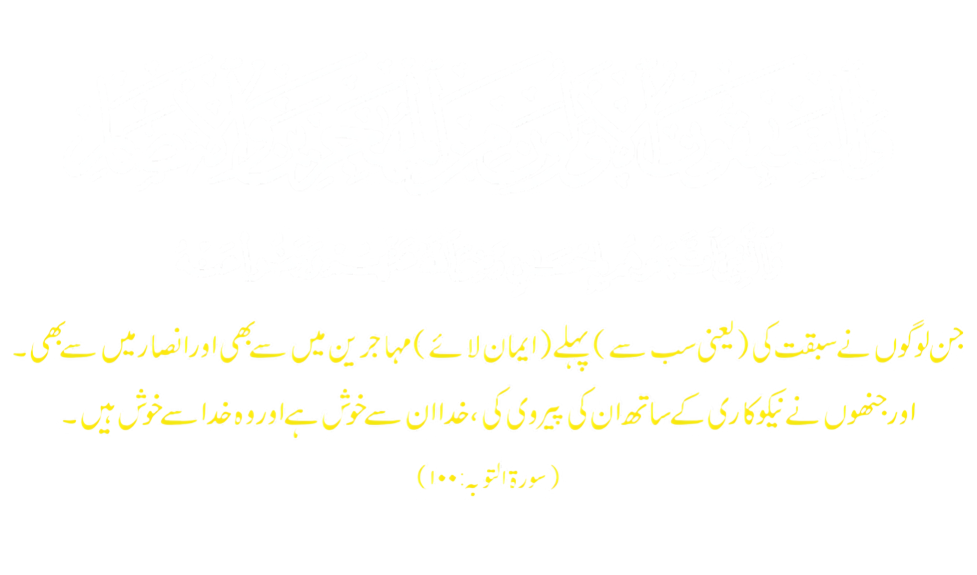فصل:....کافر کا کفر اور اہل سنت پر الزام کا رد
امام ابنِ تیمیہؒفصل:....کافر کا کفر اور اہل سنت پر الزام کا ردّ
[ اہل سنت کے تقدیر کے بارے میں عقیدہ پر رافضی کا کلام کہ کافر کفر کر کے بھی رب تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہے کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی مراد کو بجا لایا ہے]۔
[اعتراض]: شیعہ مصنف لکھتا ہے:’’اہلِ سنت کے افکار و آراء سے لازم آتا ہے کہ: کافر اپنے کفر کے باوصف اطاعت شعار ہو اس لیے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے مطابق کیا ہے۔کیونکہ رب تعالیٰ نے اس سے کفر کا ارادہ کیا اور وہ کفر کر رہا ہے اور وہ اس ایمان کو نہیں لایا جو رب تعالیٰ کو اس سے نا پسند ہے۔ سو اس نے رب تعالیٰ کی طاعت کی ہے اور اسے ایمان لانے کو کہہ کر نبی نا فرمان ٹھہرے گا کیونکہ نبی اسے اس ایمان لانے کو کہہ رہا ہے جو اللہ کو اس کافر سے پسند نہیں اور اس کو اس کفر سے روک رہا ہے جو اللہ اس کافر سے چاہتا ہے۔‘‘[انتہیٰ کلام الرافضی]۔[جواب ]:اس کا جواب کئی طرح سے دیا جاسکتا ہے :
پہلی وجہ:....شیعہ مصنف کا یہ خیال اس امر پر مبنی ہے کہ آیا اطاعت اللہ تعالیٰ امر کے مطابق ہے یا ارادہ کے؟ نیز یہ کہ کیا امر ارادہ کو مستلزم ہے یا نہیں ؟اس میں بحث بہت مشہور ہے۔ اس قدری نے اپنے قول کی صحت ذکر نہیں کی؛ اور نہ اپنے مخالفین کے قول کا فساد بیان کیا ہے۔ بلکہ اس نے صرف دعویٰ کر دیا ہے جو اس بات پر مبنی ہے کہ طاعت ارادہ کے موافق ہوتی ہے۔ سو جب اس کے مخالفین نے اسے یہ کہا کہ ہم تمہارے اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتے تو قدری کے پاس دلیل نہ ہونے کی وجہ سے منازعین کی اتنی ہی بات اس کے دعویٰ کے رد کے لیے کافی ٹھہری۔
دوسری وجہ :....ان کا استدلال اس بات سے ہے کہ امر ارادہ کو مستلزم نہیں کیونکہ اللہ بندوں کے افعال کا خالق ہے ۔ہم قبل ازیں یہ حقیقت واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کو اپنے ارادہ سے پیدا کرتا ہے ۔ اس نے کفر و عصیان اور فسق کا حکم نہیں دیا۔ تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات وہ ایسی چیز کو پیدا کرتا ہے، جس کا وہ حکم نہیں دیتا،یہ بات کتاب و سنت اور علماء کے اجماع سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص حلف اٹھا کر یہ کہے کہ کل وہ اس کا حق ادا کر دے گا، ان شاء اللہ۔ کل کا روز گزر جائے اور وہ قدرت کے باوجود اس کی تعمیل سے قاصر رہے تو وہ حانث نہیں ہوگا۔اور اگر ان شاء اللہ کے الفاظ میں مشیت کا لفظ امر کے معنی میں ہوتا تو وہ حانث ٹھہرتا، کیونکہ وہ اس کا مامور ہوتا۔ علی ہذا القیاس جب کسی فعل مامور پر حلف اٹھا کر اسے مشیت باری تعالیٰ سے معلق کر دیا جائے تو قسم اٹھانے والا اس میں حانث نہیں ہوتا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ وَلَوْ شَائَ رَبُّکَ لَاٰمَنَ مَنْ فِی الْاَرْضِ کُلُّہُمْ جَمِیْعًا﴾ (یونس:۹۹)
’’اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کرۂ ارضی پر بسنے والے سب ایمان لے آتے۔‘‘
حالانکہ اس نے بندوں کو ایمان لانے کا حکم بھی کیا ہے۔ سو معلوم ہوا کہ اس نے بندوں کو ایمان لانے کاحکم تو دیا ہے لیکن اس کو چاہا نہیں ۔ [ اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ امر اور مشیت میں فرق ہے]۔دوسری جگہ ارشاد فرمایا:
﴿ وَمَنْ یُّرِد ْ اَنْ یَّضِلَّہٗ یَجْعَلْ صَدْرَہٗ ضَیِّقًا﴾ (الانعام:۱۲۵)
’’اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کے سینہ کو تنگ کر دیتا ہے۔‘‘
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مگر گمراہ ہونے کا حکم نہیں دیتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
’’رب تعالیٰ کو تمہارے لیے تین باتیں ناپسند ہیں : (۱) قیل و قال (۲) کثرت سوال (۳) اور اضاعتِ مال۔‘‘ [صحیح البخاری، کتاب الزکاۃ، باب قول اللّٰہ تعالیٰ: لا یسئلون الناس الحاف۔]
امت اس بات پر متفق ہے کہ رب تعالیٰ منہیات کو ناپسند فرماتا ہے، تاکہ مامورات کو، اور یہ کہ وہ مقتضین، محسنین اور صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ توابین اور متطہرین سے محبت کرتا ہے۔ مومنوں اور نیک اعمال والوں سے راضی ہے اور یہ کہ وہ کافرین سے غصہ ہے اور ان پر غضب ناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:’’اللہ سے بڑھ کر کسی کو مدح محبوب نہیں اور اللہ سے بڑھ کر کسی کو عذر پیش کرنا محبوب نہیں ۔‘‘
اور فرمایا: ’’اللہ سے بڑھ کر کوئی اس بات میں غیرت مند نہیں کہ اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے۔‘‘[صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الغیرۃ۔]
اور فرمایا: ’’اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔‘‘[ایسے الفاظ متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں ۔ اور یہ الفاظ صحیح مسلم: ۲۰۶۲، ۲۰۶۳ کے ہیں ۔ دیکھیں : کتاب الذکر والدعاء، باب فی اسماء اللّٰہ تعالیٰ۔]
اور فرمایا: ’’اللہ جمال والا ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔‘‘[صحیح مسلم: ۱۹۳۔ کتاب الایمان، باب تحریم الکبرء بیانہ۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔]
فرمایا: اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسا کہ اسے یہ بات ناپسند ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔‘‘[مسند احمد: ۸؍ ۱۷۰۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ، ط: المعارف۔]
فرمایا: ’’بے شک اللہ کو متقی، غنی اور گم نام بندہ پسند ہے۔‘‘
فرمایا: ’’اللہ کو تمہارے لیے تین باتیں محبوب ہیں : (۱) تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ (۲) اور تم سب اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ (۳) اور یہ کہ اللہ نے جس کو تمہارا والی امر بنایا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔‘‘[اس کی تخریج گزر چکی ہے۔]
فرمایا: ’’رب تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کے توبہ کرنے پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی سواری ایک ویران اور ہلاکت آفرین میدان میں گم ہو گئی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا اور اسے ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ سواری نہ ملی تھی اور اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ پھر جب وہ بیدار ہوا تو اچانک اس کی وہ سواری اس کے سامنے تھی۔ پس اللہ اپنے بندے کے توبہ کرنے پر اس کے بندے پر اپنی سواری ملنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔‘‘
یہ حدیث حجاج میں متعدد طرق سے مروی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہے اور اس کی صحت و ثبوت متفق علیہ ہے۔[صحیح البخاری: ۸؍ ۶۸۔ کتاب الدعوات، باب التوبۃ عن عبداللّٰہ ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ بالفاظ مختلفۃ۔]
غرض اس جیسی متعدد احادیث میں تب پھر رب تعالیٰ بندوں سے طاعات کو اس ارادہ کے ساتھ چاہا ہے جو طاعات بجا لانے پر اس کی محبت و رضا کو متضمن ہے۔ چاہے وہ ان کو بجا نہ بھی لائے اور اسے کفر و فسق وغیرہ بندے سے ناپسند ہےاگرچہ اس نے ان کو ایک حکمت کے تحت پیدا بھی کیا ہے جو ان کی پیدائش کو مقتضی تھی اور جب اس نے کفر وغیرہ کو بندے نے ناپسند کیا کیونکہ یہ بندے کے لیے مضر ہے اور اللہ اسے ناپسند فرماتا ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسے ان کا پیدا کرنا بھی ناپسند ہے۔ کیونکہ ان میں اس کی حکمت ہے۔ کیونکہ ایک فعل کبھی ایک سے اچھا تو دوسرے سے برا ہوتا ہے۔ کیونکہ دونوں فاعلوں کا حال جدا جدا ہوتا ہے۔
تب پھر یہ لازم کیسے آ گیا کہ ایک فعل جو بندے سے قبیح ہو وہ رب تعالیٰ سے بھی قبیح ہو گا۔ حالانکہ مخلوق کو اللہ سے کوئی نسبت بھی نہیں اور جب مخلوق بھی بسا اوقات ایک ایسی بات کا ارادہ کر لیتی ہے جو اسے ناگوار ہوتا ہے۔ جیسے مریض کا ایسی دوا پینے کا ارادہ کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ اور کبھی انسان ایسی بات بھی پسند کرتا ہے جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا۔ جیسے مریض کا ایسے کھانے کو پسند کرتا جو اس کے حق میں مضر ہو۔ اور جیسے روزہ دار کا کھانے اور پینے کو پسند کرتا حالانکہ وہ ان کا ارادہ نہیں رکھتا اور بندے کا شہوتوں کو پسند کرنا حالانکہ وہ اپنے عقل و دین دونوں کے اعتبار سے ان کو ناپسند کرتا ہے۔
پس جب ایک بغیر دوسرے کا ثبوت معقول ہے اور یہ کہ مخلوقات میں ایک دوسرے کو مستلزم نہیں ۔ تو بھلا ایک کا ثبوت دوسرے کے بغیر حق تعالیٰ کے حق میں کیونکر نا ممکن ہے۔
کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب امور مراد اور محبوب ہیں ۔ لیکن ان میں مراد لنفسہ ہوتا ہے۔ یہ مراد بالذات ہے اور اللہ کو محبوب اور پسند ہوتا ہے اور کوئی ان میں سے مراد الغیر ہوتا ہے اور وہ مراد بالعرض ہوتا ہے کیونکہ وہ محبوب بالذات اور مراد بالذات تک وسیلہ ہوتا ہے۔
پس انسان عافیت کو بنفسہ چاہتا ہے اور دوا پینے کو اس تک وسیلہ کے اعتبار سے چاہتا ہے۔ البتہ بنفسہ محبوب ہونے کی وجہ سے نہیں چاہتا۔ تو جب مراد کی دو قسمیں ہیں : (۱) ایک مراد لنفسہ، یہ بالذات محبوب ہے۔ (۲) اور مراد لغیرہ، یہ غیر تک وسیلہ کے لیے مراد ہے۔ گو کبھی محبوب لنفسہ نہ بھی ہو۔ تو پھر اس باب میں محبت اور ارادہ میں فرق کرنا ممکن ٹھہرا۔
ارادہ کی دو قسمیں ہیں ۔ جو چیز محبوب ہو، وہ مراد لنفسہ ہوتی ہے اور جو فی نفسہ محبوب نہ ہو وہ مراد لغیرہ ہوتی ہے اور اسی تقسیم پر اس مسئلہ کی بنیاد ہے کہ رب تعالیٰ کا خود اپنے محبت کرنا اور رب تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے محبت کرنا۔ سو جن کے نزدیک محبت و رضا ارادہ عامہ ہے، ان کا قول ہے کہ حقیقت میں رب تعالیٰ محبت نہیں کرتا اور وہ رب تعالیٰ کے اپنے بندوں سے محبت کرنے کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ وہ انہیں ثواب دے گا اور بندوں کا رب تعالیٰ سے محبت کرنا یہ اس کی طاعت کرنے کا ارادہ کرنا ہے اور اس کا تفرب تلاش کرنا ہے۔
ان میں سے اکثر جماعتوں کا یہ قول ہے کہ وہ خود محبوب اور مستحق محبت ہے۔ البتہ اس کا دوسرے سے محبت کرنا یہ مشیئت کے معنی میں ہے۔
رہے اسلاف، حدیث و تصوف کے ائمہ اور اکثر اہل کلام و نظر تو وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ محبوب لذاتہ ہے بلکہ صرف وہی محبوب لذاتہ کہلانے کا حق دار ہے اور یہ الوہیت کی حقیقت ہے اور یہی ملت ابراہیم کی حقیقتہے۔ اور جو اس بات کا اقرار نہیں کرتے، وہ ربوبیت اور الٰہیت میں فرق نہیں کرتے اور وہ رب تعالیٰ کو معبود لذاتہ قرار نہیں دیتے اور نہ وہ اس کی طرف دیکھنے سے تلذذ کو ثابت کرتے ہیں اور نہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ اہل جنت کے نزدیک جنت کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو گا۔
در حقیقت یہ ان لوگوں کا قول ہے جو ملت ابراہیم سے خارج اور اللہ کے اس کے ماسوا سے معبود ہونے کے منکر ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ جب اوائل اسلام میں یہ قول ظاہر ہوا تو اس کے قائل کو قتل کر دیا گیا۔ یہ جعد بن درہم تھا جسے خالد بن عبداللہ قسری نے عیدالاضحیٰ کے دن عید گاہ میں علماء کی مرضی کے عین مطابق ذبح کر دیا تھا اور یہ کہا کہ: اے اہل اسلام! اپنی قربانیاں کرو۔ اللہ تمہاری قربانیاں قبول کرے اور میں جعد بن درہم کو قربان کر رہا ہوں ۔ کیونکہ جعد کا گمان ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل نہیں بنایا اور نہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اللہ جعد کی ان باتوں سے بے حد بلند و برتر ہے۔ پھر منبر سے اتر کر جعد کو ذبح کر دیا۔
ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
’’جب جنت والے جنت میں داخل ہو چکیں گے تو ایک منادی یہ نداء کرے گا۔ اے جنت والو! اللہ کے ہاں تمہارے لیے ایک وعدہ ہے وہ اس وعدہ کو تم لوگوں کے ساتھ پورا کرنا چاہتا ہے۔‘‘ وہ پوچھیں گے: وہ وعدہ کیا ہے؟ کیا اس نے ہمارے چہرے سفید (روشن) نہیں کر دیے اور ہماری تولیں بھاری نہیں کر دیں اور ہمیں جنت میں داخل کر کے جہنم سے بچا نہیں لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں : ’’پس رب تعالیٰ حجاب کو کھول دیں گے اور اہل جنت اسے دیکھیں گے۔ پس رب تعالیٰ انہیں اپنی زیارت سے زیادہ محبوب کوئی شی نہ دے گا اور یہی ’’زیادتی‘‘ ہے (جس کا قرآن میں تذکرہ ہے)۔[صحیح مسلم: ۱؍ ۱۶۳۔ کتاب الایمان: باب اثبات رؤیۃ المومنین فی الآخرۃ ربہم سبحانہ وتعالیٰ۔]
سنن میں متعدد طرق سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے: ’’اور میں تجھ سے تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں ۔‘‘
امام احمد اور امام نسائی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے: ’’میں تجھ سے تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں جو کسی ضرر رساں مضرت کے اور گمراہ کن فتنہ سے خالی ہو۔‘‘[یہ دو طویل احادیث کا جز ہے۔ پہلا حدیث سنن النسائی: ۳؍ ۴۶، ۴۷۔ کتاب السہو باب الدعاء بعد الذکر میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جبکہ دوسری حدیث الفاظ کے اختلاف کے ساتھ پہلی حدیث کے معنی میں ہے جو ’’مسند احمد: ۵؍ ۱۹۱، ط، حلبی۔ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔]
جو لوگ اس کے محبوب ہونے کو اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس کی غیر سے محبت اس کی مشیئت کے معنی میںہے۔ سو ان لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اس نے جو بھی پیدا کیا ہے، وہ اسے محبوب ہے۔ یہ لوگ بسا اوقات ابادیت کی طرف نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے کفر، فسوق اور عصیان محبوب ہے اور وہ اس پر راضی ہے اور عارف جب اس مقام کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو اس کی قیومیت عامہ کے اور اس بات کے مشاہدہ کی وجہ سے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کے نزدیک کوئی شی اچھی یا بری نہیں رہتی۔ صوفیہ اور اہل فکر و نظر کے بے شمار شیوخ اس مغالطہ کا شکار ہوئے ہیں ۔ بلاشبہ یہ ایک عظیم غلطی ہے۔
کتاب و سنت اور اسلافِ امت کا اتفاق بتلاتا ہے کہ رب تعالیٰ کو اس کے انبیاء و اولیاء بے حد محبوب ہیں ۔ اسے اپنا امر بھی محبوب ہے اور وہ شیاطین کو اور منہی عنہ کو ناپسند کرتا ہے۔ اگرچہ یہ سب کچھ اس کی مشیئت سے ہے۔ جنید بن محمد اور اس کے اصحاب کی جماعت کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہوا تھا۔ تو جنید نے انہیں دوسرے فرق کی طرف دعوت دی۔ وہ یہ اس کی مخلوقات میں اور اس کی محبوب اور غیر محبوب چیزوں میں فرق کریں ۔ لیکن انہیں اس میں اشکال ہو، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہر مخلوق اس کی مشیئت سے ہے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی مشیئت سے پیدا ہونے والی مخلوق میں اس کی محبوب مخلوق بھی ہے اور غیر محبوب بھی۔ سو جنید کی بات درست تھی۔
پانچویں وجہ :....یہ کہا جائے گا کہ ارادہ کی دو قسمیں ہیں : (۱) ایک بمعنی مشیئت ہے اور یہ فاعل کا فعل کا ارادہ کرنا ہے یہ ارادہ فعل سے متعلق ہے۔ (۲) اور دوسرا یہ کہ وہ غیر سے اس بات کا ارادہ کر لے کہ وہ ایک فعل کرے یہ غیر کے فعل کا ارادہ کرنا ہے۔
لوگوں میں یہ دونوں معانی ہی معقول ہیں ۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امر یہ ارادہ کو متضمن نہیں ۔ وہ ارادہ کی صرف پہلی نوع کو ہی ثابت کرتے ہیں اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ افعالِ عباد کا خالق نہیں ، وہ صرف دوسرے ارادہ کو ثابت کرتے ہیں ۔
ان فدایہ کے نزدیک پہلے معنی میں رب تعالیٰ کا افعالِ عباد کا خالق ہونا متمنع ہے۔ کیونکہ اس نے ان کو ان کے نزدیک پیدا ہی نہیں کیا اور ان کے بالمقابل دوسرے، ان کے نزدیک رب تعالیٰ کا ارادہ بایں معنی متمنع ہے کہ وہ ارادہ خالق ہے اور جس کے پیدا کرنے کا اس نے ارادہ نہیں کیا اس کی بابت یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کا ارادہ کرنے والا ہے۔ ان کے نزدیک وہ ہر مخلوق کا ارادہ کرنے والا ہے۔ چاہے وہ کفر ہی ہو اور اس نے جس کو پید انہیں کیا، اس کا اس نے ارادہ بھی نہیں کیا چاہے وہ ایمان ہی ہو۔
اگرچہ یہ لوگ حق کے زیادہ قریب ہیں ۔ لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ دونوں قسم کا ارادہ ثابت ہے۔ جیسا کہ آئمہ اسلاف نے اس کو ثابت بھی کیا ہے۔ جیسا کہ جعفر نے کہا: ’’اس نے ان کا ارادہ بھی کیا اور ان سے ارادہ بھی کیا۔‘‘ اب ایک دوسرے کی خیر خواہی کا ارادہ کر کے اسے امرو نہی کرتا ہے اور اس کی نافع شی کو بیان کرتا ہے۔ چاہے اس کے ساتھ اس نے اس فعل پر اس کی اعانت کا ارادہ نہ بھی کیا ہو۔ کیونکہ دوسرے کو کسی بات کے امر و نصیحت کرنے میں مصلحت ہونے سےضروری نہیں کہ اس پر اس کی معاونت میں بھی مصلحت ہو۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ مصلحت اس امر و نصیحت کی ضد میں ہو۔
جیسے اگر ایک آدمی دوسرے سے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجنے کا مشورہ لے اور وہ دوسرا اسے اس عورت سے نکاح کر لینے کو کہے کیونکہ اس مشورہ لینے والے کی مصلحت اسی میں تھی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ خود مشورہ دینے والے کی مصلحت اس میں ہو کہ اس عورت سے شادی وہ خود کر لے نا کہ کوئی دوسرا۔ لہٰذا دوسرے کی خیر خواہی کے اعتبار اسے مشورہ دینا اور بات ہے اور خود اپنے لیے کوئی فعل کرنا دوسری بات ہے۔
تو جب مخلوق کے حق میں یہ فرق ممکن ہے تو خالق کے حق میں تو بدرجہ اولیٰ ممکن ہے۔ وہ خالق و مالک مخلوق کو رسولوں کی زبانی ان کی نافع باتیں بیان کرنا ہے اور انہیں ضرر رساں باتوں سے روکنا ہے۔ پھر ان میں سے کسی کے فعل کے خلق کا تو وہ ارادہ کرتا ہے اور اسے اس فعل کا فاعل بناتا ہے اور کسی کے فعل کے خلق کا ارادہ نہیں کرتا۔ سو رب تعالیٰ کا مخلوق کے افعال کے خلق کا اور دوسری مخلوقات کے خلق کا ارادہ کرنا اور بات ہے، اور اس کا بندوں کو اس اعتبار سے امر کرنا اور بات ہے کہ وہ ان کی مصلحت یا مفسدہ کو بیان کرے۔ رب تعالیٰ نے جب فرعون اور ابو لہب کو ایمان لے آنے کا حکم دیا تھا تو انہیں ان کی اس مصلحت اور منفعت کو بیان کر دیا جو امتثالِ امر میں موجود تھی اور انہیں امر دیتے ہوئے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ ان کی اعانت بھی فرماتا۔ بلکہ بسا اوقات ان کے لیے اس فعل کے پیدا کرنے میں اور اس پر ان کی اعانت میں اس اعتبار سے مفسدہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا فعل ہو۔ کیونکہ وہ جو بھی پیدا کرتا ہے کسی حکمت سے پیدا کرتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جب فعل مامور بہ کے بجا لانے میں مامور کی مصلحت ہو تو اس مامور کے فعل بجا لانے میں آمد کی بھی مصلحت ہو یا وہ مامور کو اس کا فاعل بنائے۔ لہٰذا کہاں خلق کا پہلو اور کہاں امر کا پہلو۔
یہ قدریہ دوسرے کو کسی بات کا امر دینے والے کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ مامور جس فعل کے زیادہ قریب ہو اس کا کرنا لازم ہے۔ جیسے چہرے کی تروتازگی، اور بیٹھنے کی جگہیں تیار کرنا وغیرہ۔
ان لوگوں کو اس کا جواب دو طرح سے دیا جائے گا:
۱۔ ایک یہ کہ آمر[حکم چلانے والے] نے دوسرے کو ایسی مصلحت کا حکم دیا ہو جو اس کی طرف لوٹتی ہو، جیسے بادشاہ کا فوج کو ایسی بات کا حکم دینا جس سے اس کا ملک مضبوط ہوتا ہے اور آقا کا غلام کو ایسی بات کا حکم دینا جس سے اس کے مال کی درستی ہوتی ہو اور آدمی کا اپنے شریک کو ایسی بات کا حکم دینا جس سے ان کے مشترکہ مفاد کی درستی ہوتی ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔
۲۔ دوسرا یہ کہ آمر مامور کی اعانت میں اس کی مصلحت دیکھے۔ جیسے امر بالمعروف کہ جب آمر برّ و تقویٰ میں مامور کی اعانت کر لے۔ کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ اسے طاعت پر معاونت میں اجر دے گا اور یہ کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی اعانت میں رہتا ہے اللہ اس کی اعانت میں رہتا ہے۔
غرض جب فرض کیا گیا کہ آمر مامور کو اس کی مصلحت کے لیے امر دیتا ہے۔ نا کہ اپنے کسی نفع کے لیے جو مامور کےکرنے سے اسے پہنچتا ہو، جیسے ناصح میشر۔ اور فرض کیا کہ جب وہ مامور کی اعانت کرے گا تو اس میں اس کی کوئی مصلحت نہیں ۔ کیونکہ مامور کی مصلحت کے حصول میں آمر کی مضرت ہوتی ہو۔ جیسے کوئی مظلوم کو ظالم سے بھاگ جانے کو کہے کہ اگر وہ اس میں مظلوم کی اعانت کرتا ہے تو اس میں دونوں کی یا کسی ایک مضرت ہے۔ جیسے وہ شخص جو بستی کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور یہ کہا تھا کہ:
﴿اِنَّ الْمَلَاَ یَاْتَمِرُوْنَ بِکَ لِیَقْتُلُوْکَ فَاخْرُجْ اِنِّیْ لَکَ مِنَ النّٰصِحِیْنَo﴾ (القصص: ۲۰)
’’بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں ، پس نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیرخواہوں سے ہوں ۔‘‘
یہاں اس کی مصلحت صرف اسی میں تھی کہ وہ جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو بھاگ جانے کا ہی مشورہ اور امر دے نا کہ بھاگنے میں ان کی اعانت بھی کرے۔ کیونکہ اعانت میں اس کی قوم اسے نقصان پہنچاتی۔
اس کی مثالیں بے شمار ہیں ۔ جیسے آدمی کسی کو اس عورت سے نکاح کرنے کا کہے جس سے وہ خود نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یا اسے وہ سامان خریدنے کو کہے جو وہ خود خریدنا چاہتا ہے، یا اسے وہ مکان کرایہ پر لینے کو کہے جسے وہ خود کرائے پر لینا چاہتا ہے۔ یا اسے ایسی قوم سے صلح کرنے کو کہے جس سے مامور کو نفع پہنچے حالانکہ وہ قوم آمر کی دشمن ہو اور صلح کرنے کے بعد وہ اور زیادہ قوی ہو جاتی ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔ کہ یہ وہ مثالیں ہیں جن میں آمر مامور کی معاونت نہیں کرتا، گو اس بات کے امر میں وہ مامور کے حق میں ناصح ہو اور اس امر کا ارادہ کرنے والا بھی ہو۔
غرض مامور کو ایک ایسے فعل کا امر کرنا جس کی مصلحت اسی کی طرف راجع ہو، یہ آمر کے اس کی اس مامور کو بجا لانے پر معاونت کرنے کے علاوہ ایک بات ہے۔ چاہے وہ مامور کی اعانت کر بھی سکتا ہو۔
پس جب یہ کہا جائے گا کہ رب تعالیٰ نے بندوں کو ان افعال کا امر دیا ہے جن میں ان کی مصلحت ہے اور ان کی مصلحت کا اس نے ارادہ بھی کیا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا وہ مامور بہ میں ان کی معاونت بھی کرے گا۔ بالخصوص قدریہ کے نزدیک، وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کی ایسی اعانت کرے جس سے وہ فاعل بن جائے۔ کیونکہ اگرچہ اس کے افعال معلل بالحکمت نہیں لیکن وہ ایک مراد کی دوسری مراد سے تمیز کے بغیر جو چاہے کرتا ہے۔ اس توجیہ کی بنا پر کسی فعل کی لمیت ہونا متمنع ہے چہ جائیکہ وہ فرق کو طلب کرے۔
اگر اس کے افعال کو معلل بالحکمت کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ لمیت نفس الامر میں ثابت ہے۔ چاہے ہم نہیں بھی جانتے۔ تو بھی یہ لازم نہیں آتا کہ جب نفس الامر میں امر میں حکمت ہو تو مامور بہ کی اعانت میں بھی حکمت ہو گی۔ بلکہ بسا اوقات حکمت اس بات کو مقتضی ہوتی ہے کہ مامور بہ میں اعانت نہ کی جائے۔ کیونکہ جب مخلوق میں یہ بات ممکن ہے کہ حکمت و مصلحت کا مقتضی یہ ہو کہ آدمی غیر کو ایک ایسی بات کا امر دے جس میں اس کی مصلحت ہو جبکہ آمر کی حکمت و مصلحت اسی میں ہو کہ وہ اس کی اس امر میں اعانت نہ کرے، تو رب تعالیٰ کے حق میں اس بات کا امکان بدرجہ اولیٰ ہوگا۔سو رب تعالیٰ کفار کو ایک بات کا حکم دیتا ہے جسے کے بجا لانے میں ان کی مصلحت ہوتی ہے۔ لیکن وہ اس امر میں ان کی معاونت نہیں کرتا اور نہ اس کو پیدا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اس نے متعدد ایسے امور کو پیدا نہیں کیا کہ حکمت و مصلحت کا کمال ان کے پیدا نہ کرنے میں ہی تھا۔
جب مخلوق یہ دیکھتی ہے کہ رعایا کے ایک فرد کی مصلحت اس میں ہے کہ وہ تیر اندازی اور اسباب مملکت کو سیکھے تاکہ ملک کو حاصل کر کے جبکہ خود اپنے بچے مصلحت وہ اس میں دیکھتا ہے کہ وہ شخص قوی نہ بنے کہ مبادا اس کے بچے سے اس کا ملک چھین لے۔ یا اس پر چڑھ دوڑے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس شخص کو تو وہ حکم دے جس میں اس کی مصلحت ہو، جبکہ خود وہ کرے جس میں اس کی اولاد اور رعایا کی مصلحت ہو۔
غرض مصالح و مفاسد نفوس کے مناسب و منافی ہوا کرتے ہیں ۔ پس مامور کے مناسب وہ ہے جس کا اس کے ناصح نے اسے حکم دیا ہے اور آمر کے مناسب یہ ہے کہ اس مامور کو اس کی مراد حاصل نہ ہو۔ کیونکہ اس میں آمر کے مصالح اور مرادات کی تفویت ہوتی ہے۔
یہ نہایت عمدہ نکتہ ہے جسے وہی ثابت کرتا ہے جو رب تعالیٰ کے خلق و امر میں اس کی حکمت کو جانتا ہو اور وہ رب تعالیٰ کو بعض امور کے ساتھ محبت و فرح کے ساتھ متصف کرتا ہو، اور یہ کہ کبھی محبوب کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ مگر جبکہ جب اس کی ضد کو دفع کرے اور اس کے لازم کو موجود کرے۔ کیونکہ اجتماعِ ضدین متمنع ہے اور ملزوم کا وجود لازم کے وجود کے بغیر متمنع ہے۔
اسی لیے رب تعالیٰ ہر حال میں محمود ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریف ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی۔ حکم اسی کا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
سو جو بھی موجود ہے، وہ اللہ اس پر محمود ہے اور وہ چیز جو معلوم اور مذکور ہے وہ اس پر محمود ہے اور وہ اپنی ذات میں اپنے جن اسماء و صفات کے ساتھ متصف ہے، اس پر اس کی حمد ہے اور اس کی حمد ہے اس کے خلق و امر پر۔ وہ اپنی ہر آفرینش پر محمود ہے چاہے اس میں بعض لوگوں کے لیے ایک نوع کا ضرر ہو۔ کیونکہ اس میں اس کی حکمت ہے اور وہ اپنے ہر امر میں محمود ہے، کیونکہ اس میں ہدایت اور بیان ہے۔ اسی لیے اس کی حمد ہے آسمانوں بھر، اور زمینوں بھر اور درمیان کی سب فضاؤں میں اور اس کے بعد جو اس نے چاہا، اس کے بقدر۔ کہ یہ سب اس کی مخلوق ہے اور اس کے بعد وہ جو بھی چاہے گا وہ اس کی مخلوق ہو گی اور وہ اپنی ہر آفرینش پر محمود ہے۔
اب مخلوق میں ذکر کی گئی گذشتہ مثالیں اگرچہ ان کی نظیر رب کے حق میں نہیں ذکر کی جاتی۔ لیکن یہاں یہ مقصود ہے کہ حکیم مخلوق میں یہ بات ممکن ہے کہ وہ غیر کو ایک بات کا امر کر کے خود اس پر اعانت نہ کرے۔ تو خالق و مالک اپنی حکمت کے اس بات کا زیادہ مستحق ہے سو جس کو اس نے امر دیا اور فعل مامور میں اس کی اعانت بھی کی۔ تو اس مامور بہ سے اس کی خلق اور امر متعلق ہو گیا اور اس نے اس کی آفرینش اور محبت کو چاہا۔ سو وہ جہت خلق اور جہت امر دونوں اعتبار سے مراد ہوااور جس کی اس نے فعل مامور میں اعانت نہیں کی، تو اس مامور کے ساتھ اس کا امر تو متعلق ہوا لیکن اس کی آفرینش متعلق نہ ہوئی کیونکہ وہ حکمت معدوم تھی جو خلق کے اس سے متعلق ہونے کو مقتضی تھی اور وہ حکمت حاصل تھی جو اس کی ضد کے خلق سے متعلق تھی۔
دو ضدین میں سے ایک کا خلق دوسری ضد کے منافی ہے۔ کیونکہ بندے میں اس بیماری کا پیدا کرنا جس سے اس میں اپنے رب کے آگے ذلت و زاری، گریہ و دعا، توبہ و انابت پیدا ہوتی ہو، گناہوں کی تکفیر ہوتی ہو، دل مر جائے، ؟؟ اکڑ نکل جائے، سرکشی و فعلی جاتی رہے ک یہ اس صحت کے خلق کے منافی ہیں جس کے ہوتے ہوئے یہ مصالح و منافع حاصل نہیں ہو سکتے۔
اسی طرح ظالم کے ظلم کو پیدا کرنے سے مظلوم میں وہی صفات پیدا ہوتی ہوں جو مرض کی وجہ سے پیدا ہوتی ہوں یہ اس عدل کو پیدا کرنے کے منافی ہیں جس کے ذریعے یہ مصالح و منافع حاصل نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ اس کی مصلحت اس میں ہو کہ عدل ہو۔
بندوں کی عقلیں اس بات کے سمجھنے سے قاصر و درماندہ ہیں کہ انہیں رب تعالیٰ کے خلق و امر کی حکمتیں معلوم ہوں ان قدریہ نے فاسدہ طریقہ سے تعلیل کے میدان میں قدم رکھا اور اس باب میں انہوں نے رب تعالیٰ کو اس کی خلق سے تشبیہ و تمثیل دے ڈالی اور وہ حکمت ثابت نہ کی جو اس کی طرف لوٹتی ہے۔ ان لوگوں نے رب تعالیٰ کی صفاتِ کمال جیسے حکمت و قدرت اور محبت وغیرہ رب تعالیٰ کے حق میں سلب مان لیا۔ پھر ان کے مد مقابل جھمیہ جبریہ وہ طریق اپنایا کہ انہوں نے نفس الامر حکمت و تعلیل کو ہی باطل کہہ ڈالا۔ جیسا کہ انہوں نے حسن و قبیح کے مسئلہ میں نزاع کیا کہ ان لوگوں سے اس کو اس طریق سے ثابت کیا کہ اس میں اللہ اور مخلوق کو ایک صف میں کھڑا کر دیا اور ایسا حسن و قبیح ثابت کیا جو محبوب و مکروہ کو متضمن نہیں ۔ بے شک یہ قول بے حقیقت ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اس تعلیل کو ثابت کیا جس کا حکم فاعل کی طرف سے لوٹتا۔
تو ان کے مقابلوں نے جملہ افعال ایک کر دیے اور انہوں نے اللہ کے لیے نہ مکروہ ثابت کیا اور نہ محبوب۔ ان کا گمان ہے کہ اگر تو حسن فعل کی صفتِ ذاتیہ ہے تو اس کا حال مختلف نہیں ۔ لیکن یہ ان کی خطا ہے۔ کیونکہ موصوف کی صفتِ ذاتیہ سے کبھی اس کا لازم مراد ہوتا ہے۔ یہ منطقی لازم کو ذاتی اور عرضی میں تقسیم کرتے ہیں ۔ اگرچہ یہ تقسیم غلط ہے۔ اور کبھی صفتِ ذاتیہ سے مراد وہ صفت ہوتی ہے جو ثبوتی اور موصوف کے ساتھ قائم ہو تاکہ امورِ نسبتیہ اضافیہ سے احتراز ہو جائے۔
اس باب میں یہ لوگ احکام شرعیہ میں شدید اضطراب کا شکار ہو گئے۔ سو حسن و قبیح عقلیہ کے نفاۃ کا گمان یہ ہے کہ یہ نہ تو افعال کی صفتِ ثبوتیہ ہے اور افعال کی صفتِ ثبوتیہ کو مستلزم ہے۔ بلکہ یہ صفاتِ نستبیہ اضافیہ میں سے ہے۔ سو حسن کے بارے میں صرف یہ کہا جائے گا کہ اسے کر لے۔ یا یہ کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں اور قبیح کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اسے مت کر۔ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قول سے متعلق قول کی کوئی صفتِ ثبوتیہ نہیں اور یہ لوگوں اپنے منازعین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ: احکام یہ افعال کی صفتِ ذاتیہ ہیں ۔ لیکن انہوں نے اس کی نقیض یہ پیش کی ہے ک جنس کے ایک ہونے کے باوجود احکام میں تغیر تبدل ہو سکتا ہے۔
اس کی تحقیق یہ ہے کہ افعال کے احکام صفاتِ لازمہ میں سے نہیں ہیں ۔ بلکہ یہ افعال کی صفتِ عارضہ ہیں ۔ جو ان ی مناسبت اور منافرت کے اعتبار سے ہیں ۔ لہٰذا حسن اور قبیح اس اعتبار سے ہو گا کہ ایک شی محبوب یا مکروہ، نافع یا ضار، یا مناسب اور غیر مناسب ہو، اور یہ موصوف کی صفتِ ثبوتیہ ہے۔ لیکن اس میں شی کے احوال کے تنوع سے تنوع آتا ہے۔ البتہ یہ اسے لازم نہیں ۔
جس نے یہ کہا ہے کہ افعال میں ایسی کوئی صفت نہیں ہوتی جو حسن و قبیح کو مقتضی ہو۔ تو یہ اس کے اس قول کے بمنزلہ ہے کہ اجسام میں ایسی کوئی صفات نہیں جو تسخین (گرم کرنا) اور تبرید (ٹھنڈا کرنا) کو اور اِشباعِ (پیت بھرنا) اور راء واء (پیاس بجھانا) کو مقتضی ہو۔ پس اعیان کی ان صفات کا سلب جو آثار کو مقتضی ہوں ، یہ افعال کو ان صفات کے سلب کے جیس اہے جو آثار کو مقتضی ہوں ۔
البتہ اعیان کی صفات اور طبائع و آثار کو ثابت کرنے والے جمہور مسلمان ہیں ۔ اسی طرح وہ اشیاء میں حسن و قبیح کو بھی ثابت کرتے ہیں ۔ جو ان کی مناسبت اور منافرت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:
﴿یَاْمُرُہُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ یَنْہٰہُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَہُمُ الطَّیِّبٰتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْہِمُ الْخَبٰٓئِثَ﴾ (الاعراف: ۱۵۷)
’’جو انھیں نیکی کا حکم دیتا اور انھیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔‘‘
یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ فعل فی نفسہ معروف بھی ہوتا ہے اور منکر بھی اور مطعوم طیب بھی ہوتا ہے اور خبیث بھی اور اگر اعیان میں اور افعال میں کوئی صفت نہیں ہوتی مگر جب امرو نہی اس کے متعلق ہو۔ تو پھر اس آیت کی تقدیری عبارت یوں ہوتی: ’’وہ انہیں امر دیتا ان باتوں کا جن کا وہ حکم دیتا ہے اور انہیں ان باتوں سے روکتا ہے جن سے روکتا ہے اور ان کے لیے وہ حلال کرتا ہے جو ان کے لیے حلال کرتا ہے اور ان پر وہ حرام کرتا ہے جو ان پر حرام کرتا ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ ایسے کلام سے منزہ اور پاک ہے اسی طرح ارشاد ہے:
﴿وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓی اِنَّہٗ کَانَ فَاحِشَۃً وَ سَآئَ سَبِیْلًاo﴾ (الاسراء: ۳۲)
’’اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔‘‘
اور فرمایا:﴿اِنَّ اللّٰہَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَآئِ﴾ (الاعراف: ۲۸)
’’بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔‘‘اور اس کی نظائروامثال بے شمار ہیں ۔