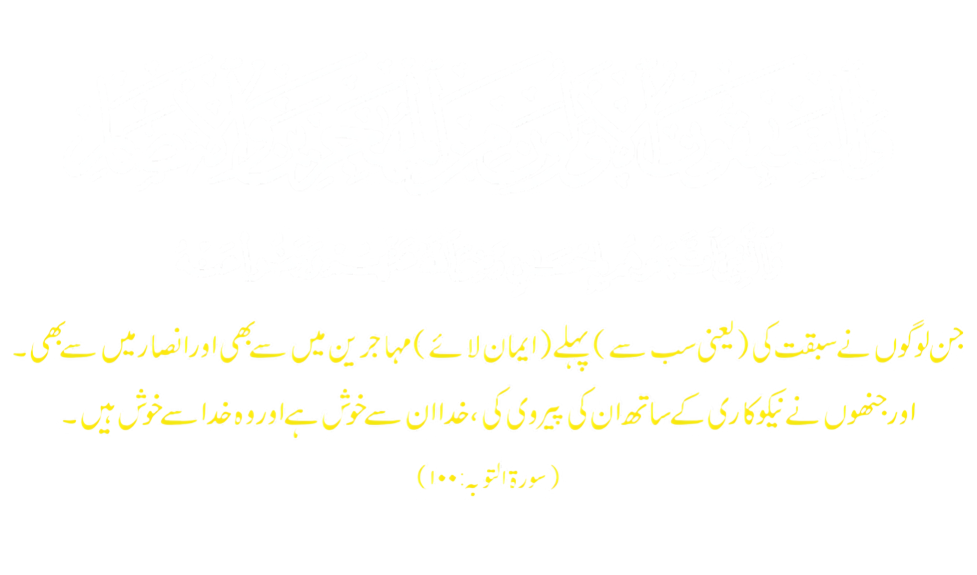اللہ تعالیٰ کے عدل اور حکمت کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ:
امام ابنِ تیمیہؒاللہ تعالیٰ کے عدل اور حکمت کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ
چوتھی بات: [الزام]: ابن المطہر کا یہ عقیدہ کہ:’’ اہل سنت ذات باری تعالیٰ کے لیے عدل و حکمت کا اثبات نہیں کرتے۔ ان کی رائے میں اللہ تعالیٰ افعال قبیحہ اور اخلال بالواجب کا مرتکب ہو سکتا ہے۔‘‘
[جواب]: (یہ بات ) دو لحاظ سے باطل ہے۔
پہلی وجہ یہ ہے کہ بہت سے اہل سنت والجماعت جو خلافت کے بارے میں منکر نصوص ہیں ؛ اور بارہ اماموں کو بھی نہیں مانتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عدل و انصاف کا اثبات ایسے ہی کرتے ہیں جیسا کہ شیعہ مصنف کی تحریر میں بیان ہوچکاہے۔مصنف اور اس کے شیوخ اور دیگر لوگوں نے یہ عقیدہ معتزلہ سے لیا ہے۔ متاخرین روافضہ بھی اس عقیدہ میں ان کے ہم نوا بن گئے ہیں ۔پس اس عقیدہ کو تمام اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کرنا سوائے شیعہ کے ‘ یہ اس مصنف کی طرف سے ایک جھوٹی بات ہے ۔
دوسری وجہ : وہ تمام اہل سنت والجماعت جو تقدیر کا اقرار کرتے ہیں ‘ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ عادل نہیں ‘یا پھرحکیم نہیں ۔ اور ان میں سے کوئی ایک ترک واجب کے جواز کا بھی نہیں کہتا۔ اور کوئی بھی اسے قبائح کا مرتکب نہیں ٹھہراتا۔ ، اہل اسلام میں جو شخص علی الاطلاق ایسا عقیدہ رکھتا ہو اور وہ بالاتفاق مباح الدم ہے۔ لیکن مسئلہ قدر اور اس طرح کے دیگر مسائل میں مسلمانوں کے مابین اختلاف بڑا مشہور و معروف ہے۔
مسئلہ تقدیراور شیعہ امامیہ :
[تقدیر کا مسئلہ متنازع فیہا ہے]۔ جب کہ قدر کی نفی کرنے والے جیسے معتزلہ اور ان کے ہم نوا؛ان کا وہی عقیدہ ہے جو متاخرین امامیہ کاہے۔جب کہ قدر کوثابت کرنے والے جمہورائمہ اہل اسلام صحابہ و تابعین اور اہل بیت اور دوسرے لوگوں کے مابین یہ امر اختلافی ہے کہ خداوندی عدل و حکمت اور اس ظلم سے کیا مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا منزہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال و احکام کے معلل ہونے میں بھی اختلاف ہے:
۱۔ ایک گروہ کا نقطۂ نظریہ ہے کہ اللہ سے ظلم کا صدور ممکن نہیں اور وہ جمع بین الضدین کی طرح ذات باری کے لیے محال لذاتہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیز ممکن ہو اور قدرت الٰہی کے دائرہ میں داخل ہو اسے ظلم سے تعبیر نہیں کر سکتے۔
ان لوگوں کا کہنا ہے : مثلاً اللہ تعالیٰ اگر اطاعت شعار کو عذاب میں مبتلا کر دے اور عاصی پر انعامات کی بارش کرے تو بقول ان کے یہ ظلم نہیں ۔ وہ کہتے ہیں : ظلم اس تصرف کا نام ہے جس کا حق حاصل نہ ہو، جب کہ اللہ تعالیٰ جملہ اختیارات سے بہرہ ور ہے۔یا پھر ظلم وہ ہے جس میں کسی کے حکم کی مخالفت ہو۔ اللہ تعالیٰ تو خود حکم دینے والا ہے۔ تو اس کا یہ فعل ظلم کیوں کر ہوا؟ عقیدہ قدر پر ایمان رکھنے والے بہت سے متکلمین اور فقہاء اور اصحاب ائمہ اربعہ یہی رائے رکھتے ہیں ۔
۲۔ دوسرے گروہ کی رائے ہے کہ ظلم قدرت الٰہی کے احاطہ میں داخل ہے۔ اور وہ ممکنات میں سے بھی ہے ؛چونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اس لیے وہ ظلم کا ارتکاب نہیں کرتا، اس نے خود اپنی ذات کی مدح ان الفاظ میں فرمائی ہے:
﴿ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا﴾ (یونس۴۴)
’’بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا۔‘‘
ظاہر ہے کہ مدح اسی کام کے چھوڑنے پر کی جا سکتی ہے جس کے کرنے پر قدرت رکھتا ہو؛ نہ کہ وہ کام ترک کرنے پر جس پر کوئی قدرت ہی نہ ہو۔ان لوگوں کا کہنا ہے : اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ وَمَنْ یَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَہُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا یَخَافُ ظُلْمًا وَّلَا ہَضْمًا﴾ (طہ:۱۱۲)
’’جو حالت ایمان میں نیک کام کرے وہ ظلم اور کمی سے نہیں ڈرے گا۔‘‘
ان کا کہنا ہے کہ : ظلم یہ ہوگا کہ کسی پر دوسرے کی برائیوں کا بوجھ ڈال دیا جائے۔اور ہضم یہ ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا اجر نہ دیا جائے۔ جب کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
﴿ذٰلِکَ مِنْ اَنْبَآئِ الْقُرٰی نَقُصُّہٗ عَلَیْکَ مِنْہَا قَآئِمٌ وَّ حَصِیْدٌoوَ مَا ظَلَمْنٰہُمْ وَ لٰکِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَہُمْ ﴾ [ھود۱۰۰۔۱۰۱]
’’یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ کیلئے بیان کرتے ہیں ، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں ۔اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن انھوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔‘‘
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خبر دی ہے کہ اس نے جب ان لوگوں کوہلاک کیا توان پرکوئی ظلم نہیں کیا ؛ بلکہ انہیں ہلاک کرنا ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا ۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ِ باری تعالیٰ ہے :
﴿ وَجِیئَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَائِ وَقُضِیَ بَیْنَہُمْ بِالْحَقِّ وَہُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ﴾ [الزمر۶۹]
’’اور نبی اور گواہ لائے گئے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ۔‘‘
یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان بغیر حق کے فیصلہ کرنا ظلم ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے منزہ ہے ۔ جیساکہ ارشاد ربانی ہے :
﴿وَ نَضَعُ الْمَوَازِیْنَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیٰمَۃِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا ﴾ [انبیاء۴۷]
’’اور ہم بروز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے ، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔‘‘
مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا۔ اورنہ ہی کسی کو بغیر گناہوں کے سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے افعال سے منزہ و مبرا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :
﴿ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَیَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِِلَیْکُمْ بِالْوَعِیْدِ oمَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ ﴾ (ق: ۲۹)
’’میرے پاس جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں نے تو تمھاری طرف ڈرانے کا پیغام پہلے بھیج دیاتھا ۔میرے ہاں بات بدلی بھی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ہرگز کوئی ظلم ڈھانے والا بھی نہیں ۔‘‘
مذکورہ [بالا] آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس امر سے منزہ قرار دیا ہے، جس پر وہ قدرت رکھتا ہے نہ کہ ایک محال بات سے جس پروہ سرے سے قادر ہی نہیں ۔اس طرح کے قرآن مجید میں کئی ایک مواقع ہیں جن سے واضع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان انصاف کریگا۔اور ان کے مابین عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور عدل سے فیصلہ نہ کرنا ظلم ہوگا ‘ جب کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے بری ہے ۔ اور کسی ایک پر دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
﴿ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَۃٌ وِّزْرَ اُخْرٰی﴾ [الانعام۱۶۴]
’’اور کسی جی پر کسی دوسرے کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔‘‘
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نامناسب چیزوں سے اپنے آپ کو منزہ و بری قرار دیتے ہیں ۔ بلکہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے خود کیا ہو۔ اور اسی گناہ کا بوجھ اس پر لادا جائے گا جو اس نے خود کمایا ہو۔
صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
’’اے میرے بندو ! میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے؛ اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کرتا ہوں ‘ پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔‘‘ [صحیح مسلم۔ کتاب البروالصلۃ۔ باب تحریم الظلم (حدیث:۲۵۷۷)۔]
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے جس طرح اس نے رحمت کو اپنے لیے ضروری قرار دے رکھا ہے، قرآن کریم میں فرمایا ہے:
﴿ کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃَ﴾ (الانعام:۱۲)
’’اس نے رحمت کو اپنی ذات پر لکھ رکھا ہے۔‘‘[واجب کردیا ہے]
صحیح حدیث میں وارد ہے:’’اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک کتاب میں جو عرش پر رکھی ہے یہ الفاظ تحریر کیے: ’’ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔‘‘
ظاہر ہے کہ جس چیز کو ذات باری نے اپنے لیے واجب یا حرام کر رکھا ہے، وہ اس پر قادر ہے اس لیے کہ جو چیز ممکنات میں سے نہیں وہ اللہ کی ذات پر حرام یا واجب کیوں کر ہو سکتی ہے؟اکثر اہل سنت محدثین و مفسرین نیز فقہاء صوفیا اور متکلمین اور ائمہ اربعہ کے ماننے والے؛ جو تقدیر کے قائل ہیں یہی عقیدہ رکھتے ہیں ۔[جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدرت کو ثابت مانتے ہیں ۔ ]
پس اس عقیدہ کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور احسان کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں ۔ اس میں وہ قدریہ شامل نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ : کبیرہ گناہ کے مرتکب کا ایمان ضائع ہوجاتا ہے۔ اور اس قسم کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پاکیزگی اور تقدیس و نزاہت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ فَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ خَیْرًا یَّرَہٗ 0وَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ شَرًّا یَّرَہٗ﴾ [الزلزلۃِ: 7 ۔8 ]
’’پس جو کوئی ذرا بھر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا؛ اور جو ذرا بھر برائی کرے گا؛ اسے دیکھ لے گا۔‘‘
جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ مومن کو ہدایت یاب کر کے اس پر احسان دھرنا اور کافر کو اس سے محروم رکھنا ظلم ہے، اس کا یہ عقیدہ دو اعتبار سے جہالت پر مبنی ہے۔
پہلی وجہ : چونکہ مومن کافر پر فضیلت رکھتا ہے بنا بریں وہ اس اعزاز کا مستحق ہوا،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ بَلِ اللّٰہُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ اَنْ ہَدَاکُمْ لِلْاِیْمَانِ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ﴾ (الحجرات: ۱۷)
’’بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی جانب راہ دکھائی اگر تم سچے ہو۔‘‘
دوسری جگہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زبانی ارشاد ہوا:
﴿ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ وَ لٰکِنَّ اللّٰہَ یَمُنُّ عَلٰی مَنْ یَّشَآئُ مِنْ عِبَادِہٖ﴾ (ابراہیم: ۱۱)
’’ہم تو صرف تمہاری طرح کے انسان ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا احسان فرماتا ہے۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ وَ کَذٰلِکَ فَتَنَّا بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لِّیَقُوْلُوْٓا اَھٰٓؤُلَآئِ مَنَّ اللّٰہُ عَلَیْھِمْ مِّنْ بَیْنِنَا اَلَیْسَ اللّٰہُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰکِرِیْنَ ﴾[الأنعامِ: 53]۔
’’اوریونہی ہم نے ان کے بعض کو بعض آزمایا؛ تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ۔‘‘
پس اس گروہ کو ایمان کے لیے خاص کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو علم و قوت اور صحت و جمال اور مال میں مزید عنایت سے بہرہ ور کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے:
﴿اَہُمْ یَقْسِمُوْنَ رَحْمَۃَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَہُمْ مَعِیْشَتَہُمْ فِی الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَہُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُہُمْ بَعْضًا سُخْرِیًّا﴾[الزخرفِ: 32 ]
’’کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں ؟ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا، تاکہ ان کا بعض، بعض کو تابع بنالے‘‘
جب اللہ تعالیٰ نے دو اشخاص میں سے کسی ایک کو قوت کے ساتھ خاص کیا ہو؛ اور اس کے ساتھ ہی ایسی طبیعت دی ہو؛ جو کہ عمدہ اور مناسب غذا کا تقاضا کرتی ہے؛ تو اسے اس چیز کے ساتھ خاص کیا ہے جو اس کی صحت و عافیت کے لیے مناسب ہے ۔اور جب دوسرے کو یہی چیز نہیں ملتی؛ اور اس میں نقص آتا ہے۔ اور کمزوری پیدا ہوجاتی ہے۔ یا بیمار ہوجاتا ہے۔
ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ : کسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھا جائے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ پس اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی کسی ایسے کو سزا نہیں دیتے جو اس کا مستحق نہ ہو۔ وہ کبھی بھی احسان کرنے والے کو سزانہیں دیتے۔
، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
’’ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اس کو رات اور دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ جب سے آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے کس قدر خرچ کیا ہے اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس میں کمی نہیں ہوئی اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے کہ کسی کے لئے اس کو جھکا دیتا ہے اور کسی کے لئے اونچی کر دیتا ہے۔‘‘ [البخارِی9؍122۔ِکتاب التوحِیدِ ؛ مسلِم 3؍690 ۔کتاب الزکاۃِ، باب الحثِ علی النفقۃِ؛ سنن ابن ماجہ 1؍71۔المقدِمۃ، باب فِیما أنکرتِ الجہمِیۃ۔]
پس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ عدل بھی کرتے ہیں احسان بھی کرتے ہیں ۔ اور اس کا فعل عدل اور احسان سے باہر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی کو سزا دیتا ہے جو اس کا مستحق ہو؛ نیز نیکوکار کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔اسی لیے یہ مثل مشہور ہے:
’’کُلُّ نِعْمَۃٍ مِّنْہُ فَضْلٌ وَکُلُّ نِقْمَۃٍ مِنْہُ عَدْلٌ۔‘‘
’’ ہراحسان اس کا فضل ہے اور ہر سزا اس کا عدل ہے۔‘‘
یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتے ہیں ۔ اور ان پر اس کی نعمتوں کا ہونااس کا احسان محض ہے ۔ جیسا کہ صحیح حدیث قدسی میں ہے: ’’ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے اللہ عزوجل نے فرمایا:
’’ اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو........ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لئے اکٹھا کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔‘‘ [مسلِم۴؍۱۹۹۴۔کتاب البِرِ والصِلۃِ والآدابِ، باب تحرِیمِ الظلمِ ؛ سنن التِرمِذِیِ۴؍۶۷۔کتاب صِفۃِ القِیامۃِ، باب۱۵؛حدِیث رقم۲۶۱۳۔ سنن ابن ماجہ ۲؍۱۴۲۲۔]
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿مَآ اَصَابَکَ مِنْ حَسَنَۃٍ فَمِنَ اللّٰہِ وَ مَآ اَصَابَکَ مِنْ سَیِّئَۃٍ فَمِنْ نَّفْسِکَ﴾[النِساء:79]
’’آپ کو جو بھلائی پہنچے سو اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے۔‘‘
یعنی تمہیں جو بھی اچھائی ملتی ہے؛ جسے تم لوگ پسند کرتے ہو؛ جیسے فتح و نصرت؛ رزق وغیرہ۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی تم پر انعام کرتے ہیں ۔ اور جو کچھ تمہیں آزمائش آتی ہے جسے تم نا پسند کرتے ہو؛ تو وہ بھی تمہارے گناہوں کی اور غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ نیکیاں اور بدیاں یہاں پر ان سے مراد نعمتیں اور مصائب ہیں ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافرمان گرامی ہے:
﴿ وَبَلَوْنَاہُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّیِّـئَاتِ ﴾ (الاعراف:۱۶۸)
’’ہم نے ان کو بھلائی و عافیت اور تکلیفات سے آزمایا۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ اِنْ تُصِبْکَ حَسَنَۃٌ تَسُؤْہُمْ﴾ (التوبہ:۵۰)۔
’’اگر تجھے آرام پہنچتا ہے تو انہیں برا محسوس ہوتا ہے۔‘‘
مزید ارشاد فرمایا:
﴿ اِنْ تَمْسَسْکَ حَسَنَۃٌ تَسُؤْہُمْ وَاِنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَۃٌ یَّفْرَحُوْا بِہَا﴾(آل عمران: ۱۲۰)
’’اگر تمہیں خوش حالی نصیب ہوتی ہے تو انہیں برا محسوس ہوتا ہے اور اگر تمھیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں ۔‘‘
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے :
﴿وَ اِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَۃً فَرِحُوْابِھَا وَ اِنْ تُصِبْھُمْ سَیِّئَۃٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَیْدِیْھِمْ اِذَاھُمْ یَقْنَطُوْنَ ﴾[الرومِ: 36]
’’اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں ۔‘‘
اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ لوگوں کو جو کچھ خیر و بھلائی ملتی ہے؛ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو وہ اپنے بندوں پر احسان فرماتے ہیں ۔ اور جو کچھ ان پر مصیبت آتی ہے؛ وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور یہ پوری گفتگو دوسری جگہ پر تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔
اور یہی حال حکمت کے بارے میں بھی ہے۔ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت سے موصوف ہیں ۔ لیکن اس کی تفسیر میں اختلاف اور تنازعہ ہے۔
ایک گروہ کا کہنا ہے کہ حکمت کا افعال العباد سے متعلق اس کا علم ہے۔ کہ ان افعال کا ایسے ہی واقع ہوننا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے ۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف علم ارادہ اور قدرت کی صفات کو ثابت مانتے ہیں ۔
کیا افعال الٰہی معلل ہیں ؟:
مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف بالحکمت ہے۔مگر اس کی تفسیر میں ان کے مابین اختلاف ہوا ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک حکمت کے معنی یہ ہے کہ اسے افعال العباد کا علم ہے اور وہ حسب ارادہ ان کو وجود میں لاتا ہے۔یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف علم ‘ ارادہ اور قدرت کی صفات کو ثابت مانتے ہیں ۔
جمہور اہل سنت کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلق و امر میں حکیم ہے، حکمت سے مشیت علی الاطلاق مراد نہیں ، اگر ایساہوتا تو ہر صاحب ارادہ حکیم بھی ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ارادہ کی دو قسمیں ہیں :
۱۔محمود ۲۔مذموم
اللہ تعالیٰ کے خلق و امر میں جواچھے انجام کار اور بہترین نتائج پائے جاتے ہیں اسی کو حکمت کہتے ہیں ۔ان الفاظ میں حکمت کا اثبات معتزلہ اور ان کی موافقت رکھنے والے شیعہ کا قول نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان گروہوں میں سے جمہور کا یہی قول ہے ۔مفسرین ‘محدثین ؛ صوفیاء؛ اہل کلام ‘ اور دوسرے لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں ۔ ائمہ فقہاء احکام شریعت میں اللہ تعالیٰ کے لیے حکمت ‘ اور مصلحت کے اثبات پر یک زبان اور متفق ہیں ۔اس میں تنازعہ کرنے والے فقط تقدیر کے منکر اورکچھ دوسرے لوگ ہیں ۔ اور ایسے ہی اس کی تخلیق میں بندوں کے لیے جو مصلحتیں اور حکمتیں ہیں وہ معلوم شدہ ہیں ۔
پہلے نظریہ کے قائلین جہم بن صفوان اور اس کی موافقت رکھنے والے مثلاً ابو الحسن اشعری اور ان کے ہم خیال فقہاء ‘ امام مالک ‘ امام شافعی ‘ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے اصحاب کا قول ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ :
[صحیح بخاری۔ کتاب بدء الخلق۔ باب ما جاء فی قول اللّٰہ تعالیٰ﴿ وَ ہُوَ الَّذِیْ یَبْدَئُ الْخَلْق....﴾ (ح:۳۱۹۴) صحیح مسلم، کتاب التوبۃ۔ باب فی سعۃ رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ (ح:۲۷۵۱)۔]
قرآن کریم میں جن افعال الٰہیہ کا ذکر آیا ہے ان میں لام تعلیل نہیں بلکہ لام عاقبت ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال معلل نہیں ہیں )۔
بخلاف ازیں جمہور کے نزدیک لام تعلیل اللہ تعالیٰ کے افعال و احکام میں داخل ہے۔ قاضی ابو یعلیٰ ؛ ابو الحسن بن الزاغونی اور ان کے ہم نوا و ہم خیال امام احمد رحمہ اللہ کے ساتھی اگرچہ پہلے قول کے قائل ہیں ‘ لیکن کئی ایک مقامات پر ان سب سے یہ دوسرا قول بھی منقول ہے۔ اور امام شافعی ‘ امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں اور دیگر فقہاء سے بھی اس طرح کا قول منقول ہے۔
اب ابن عقیل، قاضی (بعض مواقع پر) ابوخازم بن القاضی ابی یعلی اور ابو الخطاب وغیرہ رب تعالیٰ کے افعال میں حکمت اور تعلیل کی تصریح کرتے ہیں جو اس باب میں اہل نظر کے قول کے موافق ہے اور منفیہ جو اہل سنت ہیں اور تقدیر کے قائل ہیں ، ان کے جمہور کا قول تعلیل اور مصالح کا ہے۔
ادھر کرامیہ بھی تعلیل کے قائل ہیں ، جوتقدیر مانتے ہیں اور جو جنابِ ابوبکر، جناب عمر اور جناب عثمان رضی اللہ عنہم کے لیے تفضیل خلافت کے قائل بھی ہیں کہ یہ بھی تعلیل اور حکمت کا قول کرتے ہیں ۔
پھر امام مالک امام شافعی اور امام احمد کے اکثر اصحاب تعلیل، حکمت اور عقلی تحسین و تقبیح کے قائل ہیں جیسے ابوبکر قفّال ابو علی بن ابی ہریرہ وغیرہ اصحاب شافعی اور اصحاب احمد میں سے ابو الحسین تمیمی اور ابو الخطاب وغیرہ۔
غرض خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے افعال و احکام کی تعلیل میں اختلاف کا امامت کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں ۔ اکثر اہل سنت تعلیل و حکمت کے اثبات کے قائل ہیں ۔ البتہ اہل سنت میں سے جنھوں نے اس بات کا انکار کیا ہے، ان کا استدلال دو باتوں سے ہے:
۱۔ اس سے تسلسل لازم آتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ جب کسی فعل کو کسی علت کے لیے کرے گا تو وہ علت بھی حادث ہو گی اور ایک اورعلت کی محتاج ہو گی، کیونکہ یہ بات واجب ہے کہ ہر حادث کی ایک علت ہو اور اگر یہ سمجھا جائے کہ اِحداث بدون علت کے ہے تو علت کے اثبات کی ضرورت ہی نہ رہے اور یہ عبث نہ ہو گا اور احداث کا وجود علت کی بنا پر ہے تو پھر حدوثِ علت کی بابت قول حدوثِ معلول کی بابت قول کے جیسا ہو گا اور اس سے تسلسل لازم آتا ہے۔
۲۔ ان کا دوسرا استدلال اس بات سے ہے کہ جو کسی علت کی بنا پر کوئی فعل کرتا ہے تو اس ذات کا استعمال بھی اسی علت سے ہو گا۔ کیونکہ اگر علت کا حصول اس کے عدم سے اولیٰ نہ ہو، تو وہ علت ہی نہ ہو اور غیر کے ساتھ مکمل ہونا ناقص بنفسہٖ ہوتا ہے اور یہ بات رب تعالیٰ کے حق میں ممتنع ہے۔
ان لوگوں نے معتزلہ اور ان کے ہم نوا شعبوں پر ایسا اعتراض کیا ہے جو ان کے اصول کی بنا پر انھیں لاجواب کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ علت جس کی بنا پر رب تعالیٰ نے ایک فعل کیا ہے۔
اگر تو رب تعالیٰ کی طرف نسبت کے اعتبار سے اس علت کا عدم اور وجود برابر ہے تو اس علت ک اعلت ہونا ممتنع ٹھہرا اور اگر اس کا وجود اولیٰ ہے، پھر اگر وہ علت باری تعالیٰ کی ذات سے منفصل ہے تو لازم آیا کہ اللہ اس غیر کے ساتھ کامل ہو اور اگر وہ علت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو ذاتِ باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آیا۔
اب تعلیل کو جائز کہنے والوں میں نزاع ہے۔ چنانچہ معتزلہ اور ان کے خوشہ چین شیعہ ایسی علت ثابت کرتے ہیں جو غیر معقول ہے۔ وہ یہ کہ اللہ ایسی علت کی وجہ سے فعل کرتا ہے جو اس کی ذات سے منفصل ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس کی طرف نسبت کے اعتبار سے علت کا عدم اور وجود برابر ہے۔
رہے علت کے قائل اہل سنت تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے جیسا کہ کتاب و سنت کی اس پر دلالت ہے، ان کا قول ہے کہ محبت و رضا یہ ارادہ سے اخص ہے۔
ادھر معتزلہ اور اصحاب اشعری کہتے ہیں : محبت، رضا اور ارادہ سب ایک جیسا ہے۔ جمہور اہل سنت کا قول ہے اللہ کفر اور فسق و عصیان کو نہ محبوب رکھتا ہے اور نہ ان چیزوں سے راضی ہے۔ چاہے یہ چیزیں اس کی مراد میں داخل بھی ہیں ۔ جیسا کہ جملہ مخلوقات اس کی مراد میں داخل ہیں ۔ کیونکہ اس میں حکمت ہے۔ چاہے یہ چیزیں اس کی مراد میں داخل بھی ہیں ، جیسا کہ جملہ مخلوقات اس کی مراد میں داخل ہیں ۔ کیونکہ اس میں حکمت ہے۔ چاہے وہ فعل فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے شر ہو، کیونکہ یہ بات نہیں کہ کسی شخص کی طرف نسبت کے اعتبار سے اگر ایک بات شر ہو تو وہ شخص حکمت سے خالی بھی ضرور ہی ہو گا۔ بلکہ اللہ کی اپنی مخلوقات میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ جن کو کوئی تو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔
[تسلسل کا جواب ]
یہ لوگ تسلسل کے دو جواب دیتے ہیں :
۱۔ ایک یہ کہ یہ تسلسل حوادثِ مستقبلیہ میں ہے نہ کہ حوادثِ ماضیہ میں ، کیونکہ رب تعالیٰ جب کسی فعل کو کسی حکمت سے کرتا ہے تو وہ حکمت فعل کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ پھر جب اس حکمت کے بعد اس حکمت سے ایک اور حکمت طلب کی جائے تو یہ تسلسل مستقبل میں ہو گا اور وہ حکمت حاصلہ اسے محبوب ہو گی اور دوسری حکمت کے حصول کا سبب بھی ہو گی۔ پس رب تعالیٰ ایسی حکمتوں کو پیدا فرماتے رہتے ہیں جو اسے محبوب ہوتی ہیں اور انھیں اپنی محبوبات کا سبب بناتے رہتے ہیں ۔
ان کا کہنا ہے کہ مستقبل میں تسلسل میں جمہور مسلمانوں اور دوسری تمام ملتوں کے نزدیک جائز ہے۔ کیونکہ جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب دونوں دائمی ہیں حالانکہ دونوں میں حوادث کا تجدد بھی ہوتا ہے۔ اس بات کا انکار صرف جہم بن صفوان نے کیا تھا۔ جس کا گمان تھا کہ جنت اور جہنم دونوں فنا ہو جائیں گے اور ابو ہذیل علاف[یہ ابو ہذیل محمد بن ہذیل بن عبداللہ بن مکحول العبدی العلاف ہے، بصرہ کے معتزلہ کا شیخ اور ہذلیہ فرقہ کا بانی مبانی ہے۔ بصرہ میں ۱۳۵ھ میں پیدا ہوا اور ۲۲۶ھ میں وفات پائی۔ (ایک قول، ۲۲۷ھ میں اور ایک قول ۲۳۶ھ میں وفات پانے کا بھی ہے) شہرستانی ’’الملل و النحل‘‘ (۱؍۵۴) کہتے ہیں : ابو ہذیب نے جملہ معتزلہ سے جس بات میں تفرد کیا ہے، وہ اس کا یہ قول ہے: ’’جنت اور جہنم والوں کی حرکات ختم ہو جائیں گی اور وہ دائمی بے حسی اور سکون و خمود میں آ جائیں گے۔ پھر اسی سکون میں اہل جنت کی جملہ لذتیں اور اہل نار کے جملہ آلام جمع ہو جائیں گے۔‘‘ لیکن یہ جہم کے قول کے قریب قریب قول ہے جو جنت اور جہنم کے فنا ہو جانے کا قائل ہے۔ ابوہذیل کے ترجمہ و مذہب کی۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیں : لسان المیزان: ۵؍۴۱۳۔۴۱۴۔ ابن خلکان: ۳؍۳۹۶۔۳۹۷۔ تاریخ بغداد: ۳؍۳۶۶۔۳۷۰۔ الملل و النحل: ۱؍۵۳۔۵۶)]اس بات کا قائل ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کی حرکات ختم ہو جائیں گی اور وہ دائمی سکون میں آ جائیں گے۔ کیونکہ ان لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ تسلسل حوادثِ ماضیہ و مستقبلیہ دونوں میں ممتنع ہے۔ ان لوگوں کے اسی قول کی بنا پر ائمہ اسلام نے انھیں گمراہ قرار دیا ہے۔
پھر حوادث ماضیہ میں تسلسل کی بابت بھی اہل اسلام (اہل حدیث اور اہل کلام وغیرہ) کے دو اقوال ہیں ۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہمیشہ سے جب چاہے متکلم ہے اور جب چاہے فعال ہے جو افعال کے اس کی قدرت و مشیت کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں جو ایک کے بعد ایک ہیں ۔ چنانچہ وہ اپنی مشیت سے ہمیشہ سے متکلم ہے اور اپنی مشیت سے ایک کے بعد ایک فعل میں اپنی مشیت کے ساتھ فعال ہے اور اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اللہ کے سوا ہر چیز حادیث ہے مخلوق ہے اور عدم سے وجود میں آئی ہے اور اس جہان میں اللہ کے ہم پلہ کوئی شے قدیم نہیں ہے جیسا کہ فلاسفہ جو افلاک کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور یہ کہ یہ افلاک اپنے وجود میں اللہ کے مساوی ہیں ۔ بلاشبہ اہل اسلام میں سے یہ عقیدہ کسی کا بھی نہیں ۔