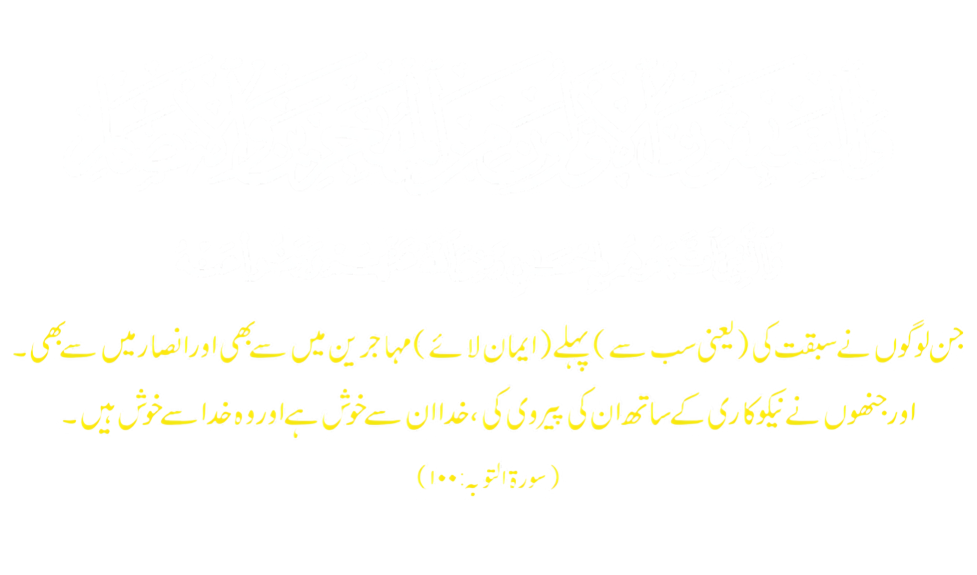عالم کا فاعل اصولِ عالم کے لیے علتِ تامہ ہے نہ کہ حوادث کے لیے پر رد
امام ابنِ تیمیہؒعالم کا فاعل اصولِ عالم کے لیے علتِ تامہ ہے نہ کہ حوادث کے لیے پر رد
اگر کہا جائے کہ وہ عالم کے اصول کے لیے علتِ تامہ تو ہے لیکن حوادث کے لیے نہیں یا یہ کہا جائے کہ وہ ایک ایسے ارادہ ازلیہ کے ساتھ ارادہ کرنے والا ہے جو کہ ازل میں اس کی مراد کے اقتران کو مستلزم ہے لیکن وہ ارادہ ازلیہ جو مراد کو مقارن اور متصل ہے وہ اصولِ عالم کے ساتھ متعلق ہے نہ کہ اس کے حوادث سے۔‘‘
تو ان کوجواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات کئی وجوہ سے باطل ہے :
اول : ان میں سے: مفعولِ معین کا اپنے فاعل کے ساتھ مقارنہ خاص طور پر اس کے ساتھ ازلاً اور ابداً مقارنہ صریح عقول کے اعتبار سے ممتنع ہے بلکہ عقل اوّلی میں بھی تصورِ تام کے بعد یہ ممتنع ہے۔ اوراگر وہ یہ کہیں کہ علومِ ضروریہ کے انکار پر ان عقلاء کا کوئی بھی گروہ متفق نہیں جن کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہے ۔
[جواب ]: تو ان کو جواب میں کہا جائے گا کہ کوئی حر ج نہیں کیونکہ یہ تو ایسا قول ہے جس پرعقلاء میں سے کوئی بھی گروہ متفق نہیں بلکہ جمہورِ عقلاء اگلے پچھلے وہ سب انتہائی درجے کی نکیر کرتے ہیں ،اس کا صرف ایک ہی گروہ قائل ہے جواس قول کو آپس میں بعض بعض سے تقلیدا اور اندھا اعتماد کرتے ہوئے نقل کرنے والے ہیں باہم ایک دوسرے کی موافقت کر تے ہوئے ۔جب اس گروہ کے افراد اس قول کو دوسرے کی موافقت میں اختیار کرنے والے ہیں تو اس صورت میں عمداً جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنے پر اتفاق اور امور مشتبہ پر اتفاق ایک ممکن امر ہے (یعنی باہمی گھٹ جوڑ کرکے کسی باطل پر متفق ہونا )؛جیسے کہ وہ مذاہب ِ باطلہ جن کا فساد بدیہی عقل سے معلوم ہے۔ بخلاف ان اقوال کے جس کا لوگ اتفاقی طور پر اقرار کرتے ہیں ۔ یعنی بغیر تقلید کے اور دوسروں کی دیکھا دیکھی کے پس ان میں سے کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جس کا بدیہی عقل سے فساد معلوم ہو اسی وجہ سے تو کفار کے عام اقوال اور اسی طرح اہل بدعت جو کہ مشرکین اور نصاریٰ اور روافض اور جہمیہ ہیں ان کے عام اقوال ایسے ہیں جن کا فساد بدیہی عقل سے معلوم ہے لیکن وہ ایسے اقوال ہیں کہ ان میں سے صرف ایک گروہ اس کا قائل ہے اور وہ آپس میں بعض بعض سے نقل در نقل حاصل کر رہے ہیں ۔
دوم : یہ کہا جائے گاکہ یہ بات حق ہو تو پھر عالم میں حوادث کا حدوث ممتنع ہو جائے گا اور حوادث کے لیے کوئی بھی محدث اور موجب اور پیدا کرنے والا نہیں ہوگا اور یہ ان امور میں سے ہے جن کا فساد عقلِ بدیہی کے ساتھ نسبتاً زیادہ ظاہرہے کیوں کہ علت جب علتِ تامہ ازلیہ ہوئی اور اس کا معلول اس کے ساتھ مقارن ٹھہرا تو جو شے حادث ہے اگر وہ اس کا معلول ہے تو بتحقیق وہ معلول متاخر ہوا یا بعض معلول کے علتِ تامہ سے متاخر ہوا اور علتِ تامہ کے بارے میں یہ بات ممکن نہیں کہ وہ معلول سے متاخر ہو جائے نہ کل معلول سے اور نہ بعض معلول سے ،پس جو بھی شے حادث ہے ،پیدا ہونے والی ہے وہ علتِ تامہ ازلیہ کی وجہ سے حادث نہیں ہوتی اور واجب الوجود ذات تو ان کے نزدیک علتِ تامہ ازلیہ ہے پس یہ بات لازم آئی کہ اس سے کوئی بھی شے حادث نہ ہو نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ ۔
اس مقام پر جس بات کے ذریعے وہ عذر پیش کرتے ہیں یعنی ان کا یہ کہنا کہ حوادث کا تاخر بوجہ استعداد کے تأخرکے ہے یا اس کے امثال دوسرے فاسد اقوال تو بے شک یہ بات تو اُس چیزوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے جن کے وجود کی علت اور استعداد و قبول کی علت الگ الگ ہو ں جس طرح کہ سورج سے روشنی پیدا ہوتی ہے بتحقیق وہ کبھی نرم کرنے والی اور کبھی تر کرنے والی ہوتی ہے یعنی وہ پھلوں کو خشک ہونے کے بعد ان کو نرم کرتی ہے اُس رطوبت کی وجہ سے جو اس میں پائی جاتی ہے پس پانی کی رطوبت اور سورج کی گرمی آپس میں جمع ہو جاتی ہیں پس وہ پھلوں کو پختہ کر دیتی ہے اور نرم کر دیتی ہے اور کبھی ان کو خشک بھی کرتی ہے اور جس طرح کہ پھلوں کے پکنے کا عمل مکمل ہونے کے بعد ان سے رطوبت کا استمداد منقطع ہو جاتا ہے (یعنی پھر زمین سے رطوبت حاصل نہی کرتے )پس صرف حرارت رہ جاتی ہے جو کہ رطوبت میں اثر کرتی ہے پس وہ ان کو خشک کر دیتی ہے جس طرح کہ سورج اور آگ اور ان کے علاوہ دیگر گرم اجسام دوسرے اشیا ء کو خشک کر تی ہیں ۔
مقصود تو یہ ہے کہ ان جیسی امثال میں کبھی کبھی فاعل کا فعل قابل (اثر قبول کرنے والا)کے عدم استعداد کی وجہ سے متاخر ہو جاتا ہے اور اگر یہ بات فرض کر لی جائے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں یعنی عقلِ فعال کہ اس کی کوئی حقیقت ہے تو پس بتحقیق اس کے فیض کا تاخر قوابل کے استعداد پیدا ہونے تک اس باب میں سے ہوگا ۔
رہا واجب الوجود جو کہ اپنے ماسوا سب کے لیے فاعل ہے اور وہ فاعل جس کا فعل کسی دوسرے امر پر موقوف نہیں ہے نہ اس کا استعداد نہ اس کا امداد یعنی دوسرے میں اضافہ کرنا اور اثر کرنا نہ اس کا قبول اور اس کے علاوہ تاثیرات بلکہ اس کی خود ذات ہی فعل کو مستلزم ہے پس اگر یہ بات فرض کر لی جائے کہ وہ علتِ تامہ ازلیہ ہیں تو یہ بات ضروری ہوگئی کہ اس کے پورے کا پورا معلول اس کے ساتھ مقارن ہو اور اس کے مفعولات میں سے کوئی شے بھی کوئی جز بھی اس سے مؤخر نہ ہو اور جب یہ بات مشاہدہ سے ثابت ہے کہ اس کے مفعولات میں سے کوئی شے (لاعلی التعیین )اس سے مؤخر ہے اگرچہ وہ مفعول بالواسطہ ہو تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ ازل میں علتِ تامہ نہیں اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ وہ علت بنا ہے بعد اس کے کہ وہ علت نہیں تھا ۔
اگر کہا جائے کہ حرکتِ فلکیہ ہی حوادث کے حدوث کا سبب ہیں ۔
تو جواب میں کہا جائے گا کہ: یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کا بطلان معلوم ہے کیوں کہ وہ حرکت جو دھیرے دھیرے حادث ہے اس کے بارے میں یہ بات ممتنع ہے کہ وہ اس کی علت کے ساتھ ازل میں مقارن ہو پس یہ بات معلوم ہو گئی کہ حوادث کے حدوث کا موجب اورسبب وہ علت تامہ ازلیہ نہیں بلکہ ضروری ہے کہ رب تعالیٰ ہی افعال کے ساتھ متصف ہیں اور وہی اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے دھیرے دھیرے بسبب اس ارادے کے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اوراس سے وہی اشیاء پیدا ہوتی ہیں جو حادث ہوتی ہیں جیسے کہ اس کی وہ مشیت جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کے وہ کلمات جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور اس کے وہ افعال جو اختیاریہ اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں ۔
سوم: یہ ہے کہ حوادث کے لیے کسی محدث (پیدا کرنے والا)کا ہونا ضروری ہے اور یہ امر ممتنع ہے کہ اِن کو اُس کے علاوہ کوئی اور حادث پیدا کرے کیوں کہ اُس کے علاوہ اور کوئی رب نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شک اس حدوث کے بارے میں قول تو بعینہ اس کی ذات میں اِس قول کی طرح ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ دو حال سے خالی نہیں :
یا تو یہ کہ اس کی ذات ازل میں علتِ تامہ ازلیہ ہوگی یا نہیں ہوگی اور پھر وہ تقسیم لوٹ کر آئے گا اور اگر وہ یہ کہیں کہ دوسرا اس وجہ سے متاخر ہے کہ اثر قبول کرنے والے کا حدوث متاخر ہے اسی طرح وہ شروط متاخر ہیں جو فیض اور تاثیر سے پہلے اس کی ذات کے ساتھ قائم تھی۔
تو ان کو جواب میں کہا جائے گا کہ یہ تو ان چیزوں سے سمجھ میں آتاہے جب قوابل یعنی تاثیر قبول کرنے کی استعداد غیر کی طرف سے مستفادہو۔ جیسے شعاع کا حدوث شمس سے ہے۔ اور جس طرح وہ عقلِ فعال کے بارے میں کہتے ہیں ۔ اور رہی یہ صورت کہ وہ کہتے ہیں : وہی ایک ذات ہی قابل (اثر قبول کرنے والا) اور مقبول(یعنی اثر) دونوں کا خود وہی اکیلافاعل ہو ۔ اسی طرح شرط اور مشروط کا بھی وہی فاعل ہواور وہی علتِ تامہ ازلیہ ہو ان افعال کا جو اس کی ذات سے صادر ہو رہے ہیں تو یہ بات واجب اور ضروری ہے کہ اس کا معلول پورے کا پورا اس کے ساتھ مقارن ہو اور یہ بات ممکن نہیں کہ ا س سے کوئی جزء متاخر ہو کیوں کہ یہ امرممتنع ہے کہ وہ بغیر کسی شے کے پیدا کرنے کے فاعل بنے بعد اس کے کہ وہ فاعل نہیں تھا اور اس کی ذات کا کسی شے کو پیدا کرنا باوجود یہ کہ وہ علتِ تامہ ازلیہ ہو یہ ممتنع ہے اور اس کا نوعِ حوادث کے لیے علت بننا ساتھ باوجودیکہ اس سے کوئی بھی ایسا فعل اس سے صادر نہ ہو جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو ، یہ ممتنع ہے ۔
دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً عالم کا دو مختلف فاعلوں سے صدور ممتنع ہے خواہ وہ پورے کے پورے عالم کے احداث میں باہم شریک ہوں یا ایک ذات بعضِ عالم کا فاعل ہو اور دوسرا باقی کا فاعل ہو جس طرح کہ اس جگہ کے علاوہ ایک اور مقام پر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں کوئی نزاع نہیں کیوں کہ عقلاء میں سے کسی نے بھی اس کو ثابت نہیں کیا کہ عالم دو ایسی ذاتوں سے صادر ہوا ہے یعنی پیدا ہوا ہے۔ جوصفات اور افعال میں باہم بالکل مساوی ہیں اور عقلاء میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ عالم کے قدیم اصول (یعنی افلا ک وغیرہ )ایک ہی ذات سے صادر ہیں اور اس کے حوادث دوسری ذات سے صادر ہیں کیوں کہ عالم تو حوادث سے کسی بھی زمان میں خالی نہیں ہوا اور ملزوم کا فعل (حدوث اور وجود )بغیر لازم کے ممتنع ہے اور اگر لوازم کا فاعل (ملزوم کے فاعل کے علاوہ ) کوئی اور ذات قرار پائے تو یہ بات لازم آئے گی کہ ایک ہی فعل دوذاتوں سے تب ہی تام ہوا کہ ہر ایک نے دوسرے کی مدد کی پس دو ذاتوں میں دور لازم آئے گاپس یہ بات کہ ان دونوں ربوں (خداؤں )میں سے ہر ایک رب تب ہی بنا جب دوسرے نے اس کی مدد کی اور اعانت سے اور وہ قادر نہیں بنا مگر دوسرے کی وجہ سے ،وہ فاعل نہیں بنا مگر دوسرے کی وجہ سے پس یہ ایک قادر نہیں بنے گا جب تک کہ دوسرا اسے قادر بنائے اور یہ دوسرا قادر نہیں بنے گا یہاں تک کہ پہلا اسے قادر بنائے اور یہ امرممتنع ہیکیونکہ پہلے سے مفروض تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک (دوسرے کی طرف احتیاج کے بغیر )قادر ہے اور یہ اپنے مقام پر یہ بات تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔
جب یہ بات بالکل واضح ہے کہ حوادث کے لیے اس رب کے علاوہ اور کوئی فاعل نہیں تو ایسی صورت میں اگر اس کی ذات سے بغیر سبب ِ حادث کے حوادث پیدا ہوں تو بغیر کسی سبب ِ حادث کے حوادث کا پیدا ہونا لازم آئے گا ۔اور اگر یہ بات جائز اور ممکن ٹھہرے تو بغیر کسی سبب ِ حادث کے پورے عالم کا حدوث (پیدا ہونا )ممکن ٹھہرے گا تو یہ بات بھی کہ یہ لازم آئے گا کہ یہ عالم قدیمِ اور ازلی بنے اور حوادث سے خالی قرار پائے اور یہ بھی کہ بغیر کسی سببِ حادث کے اس میں حوادث پیدا ہوئے بعد اس کے کہ وہ موجود نہیں تھے اور یہ تو بالاتفاق ممتنع ہے اور اس کے امتناع کی بہت سی وجوہ ہیں :
مثلاً اس کا تقاضہ یہ ہے کہ عالم میں ایک ایسی قدیم ذات نہ پائی جائے جو واجب بنفسہ یا بغیرہ ہو اس لیے کہ جب یہ بات فرض کر لی گئی کہ کوئی معلول ایسا پایا جا سکتا ہے جو قدیمِ ازلی ہے اور پھر وہ بعد میں حادث ہوا تو پھر اس میں حوادث پیدا ہوئے تو یہ بات ضروری قرار پائی کہ وہ ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف تبدیل ہوگا اور اس سے وہ صفت زائل ہو گی جو پہلے موجود تھی اور وہ پیدا ہو گی جو پہلے سے موجود نہیں تھی تو ایک موجود شے کا زوال ممتنع ہوا کیوں کہ قدیم تو قدیم تب بنتا ہے جب وہ واجب بنفسہ یابغیرہ ہو بلکہ قدیم پس جب یہ بات معلوم ہے کہ قدیم واجب بنفسہ یابغیرہٖ ہے تو اس کے عدم کے امتناع کا علم بہت ہی زیادہ مؤثر اور بہت زیادہ پختہ اور پکا ہے اور جب عالم میں کوئی شے اس حال میں قدیم اور ازلی بنے جب اس میں کوئی بھی شیٔ حادث نہ تھا اور پھر اس میں کوئی حادث پیدا ہو جائے تو پس بتحقیق اس نے اس کو اس حالتِ قدیمہ سے تبدیل کر دیا جو ازلیہ تھی جس کی وجہ سے وہ واجب بنفسہ اور بغیرہ تھا ایک دوسرے حالت کی طرف جو اول حال کے مخالف ہے اور یہ باوجود یکہ ممتنع ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کسی سببِ حادث کے بغیر ہو تو یہ ممتنع ہے (دونوں وجہوں سے )۔
اس وجہ سے بھی اور اس سے بھی اور یہ بھی کہ عالم کا حوادث کے ساتھ مقارنت سے جدائی متصور ہی نہیں اس لیے کہ یقیناً اجسام حوادث کے اتصال سے خالی نہیں ہوتے مثلاً حرکت اور علاوہ ازیں باتفاق عقلاء عالم میں کوئی شے ایسی نہیں مگر صرف وہی ہیں جو بذاتِ خود قائم ہیں یا غیر کی وجہ سے قائم ہیں اور اعیان (اجسام )تو حوادث کے اتصال سے خالی نہیں ہوتے اس لیے کہ اگروہ (کسی وقت میں )ان سے خالی ہوں اور پھر ان کے ساتھ متصل ہو جائیں تو بغیر کسی سبب حادث کے حوادث کا حدوث لازم آئے گا اور یہ باطل ہے ۔
اگر یہ بات نہ ہو تو پھر توبغیر سبب کے حوادث کا حدوث لازم آئے گا پس عالم کے قدم کا قول باطل ہوا پھر بہت سے اہل نظر تو یہ کہتے ہیں کہ عالم میں تو صرف اور صرف جسم یا عرض ہی پایا جاتا ہے اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو مشار الیہ کے ساتھ جسم کی تخصیص کرتے ہیں یعنی جس کی طرف حسی اشارہ کیا جا سکے صرف وہی جسم ہوتا ہے اور اس بات کو ممنوع سمجھتے ہیں کہ ہر جسم جوہرِ فرد یا مادہ اور اس صورت سے مرکب ہو پس اُن پر تو وہ اشکال نہیں ہوتا جو دوسروں پر ہوتا ہے ۔
اگر یہ بات فرض کر لی جائے کہ عالم میں ایسی اشیاء بھی ہیں جو اس سے خارج ہیں یعنی جوہر اور عرض میں داخل نہیں جس طرح کہ وہ لوگ جو عقول اور نفوس کو ثابت کرنے والے ہیں ،کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اجسام نہیں بلکہ نفوس تو جسم کے ساتھ متصل ہی ہونگے اس سے جدا نہیں ہوتے بلکہ وہ تو اس کے ساتھ مقارن اور متصل ہیں اور اس کی تدبیر اور انتظام کرنے والے ہیں پس وہ حوادث سے جدا نہیں ہو سکتے ۔
نیز یہ بھی کہ نفوس تصورات اور حادث ارادوں سے جدا نہیں ہوتے پس وہ حوادث کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مقارن ہیں اور عقول تو اس کے لیے علت ہیں جواپنے معلولات کومستلزم ہیں اور زمان کے کسی بھی جزء میں اس پر مقدم نہیں ہوتے پس یہ امرممتنع ٹھہراکہ عالم میں کوئی ایسی شے ہو جو حوادث سے سابق ہو پس یہ بات بھی ممتنع ثابت ہوئی کہ اس میں سے کوئی شے قدیمِ ازلی بنے جو کہ حوادث پر سابق ہو اور ایسی صورت میں عالم میں سےکسی بھی شے کو پیدا کرنے والی ذات کے بارے میں یہ بات ممتنع ہے کہ وہ اس کو اس کے لوازم کو وجود دینے کے بغیراز سرِ نو(ابداع) وجود دے اور اس کے لوازم کے بارے میں یہ بات ممتع ہے کہ اس کا وجو د ازل میں پایا جائے پس عالم میں کسی بھی شے کاا زل میں وجود ممتنع ٹھہرا ۔
اگرکہا جائے کہ وہ فلک کے لیے بشمول اس کی حرکت کے علتِ تامہ ازلیہ ہیں ؛ تو یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ فلک کے لیے بمع حرکت کے علتِ تامہ ازلیہ ہوپس اس کی حرکت ازلی ٹھہرے گی اور حرکت تو دھیرے دھیرے وجود میں آتی ہے لہٰذا یہ ممتنع ہوا کہ اس کی ساری حرکت ازلی ہو اور اگر کہا جائے کہ وہ صرف فلک کے لیے علتِ تامہ ازلیہ ہیں نہ کہ اس کی حرکت کے لیے اور اس کی حرکت تو ایک دوسرے مبدع(ازسر نو پیدا کرنے والے ) کی طرف محتاج ہے حالانکہ اُس اللہ کے علاوہ اور کوئی مبدع نہیں ہے ۔
اگر کہا جائے کہ وہ حرکت کے لیے علت رفتہ رفتہ یعنی شیئا ًفشیئاً بنتے ہیں اور وہ ازل میں حرکت کے لیے علتِ تامہ نہیں ہیں یعنی وہ ازل میں حرکت کے لیے علتِ تامہ بنتے ہیں اس کے وجود کے اعتبار سے یعنی جتنا جتنا وجود میں آتا ہے اس کے لیے علت بنتا ہے پس اس کا علت بننا اور اس کی فاعلیت اور اس کا ارادہ یہ حادث ہوا بعد اس کے کہ وہ نہیں تھا یعنی معدوم تھا پس یہ بات ممتنع ہو ئی کہ وہ ازل میں علتِ تامہ بنے اور یہ قول یہ ایسا ظاہر اور واضح ہے کہ اس میں وہ شخص اختلاف نہیں کر سکتا جو اس کو سمجھے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہے اس بات کو بیان کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ اس ذات کا علتِ تامہ ازلیہ ہونا ممتنع ہے ہر ہر موجود کے حق میں اور یہ کہ اس کا علتِ تامہ ہونا فلک کے لیے سمیت اس کی حرکت کے ممتنع ہے اور وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ ازل میں ہر موجود کے لیے علت ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ازل میں ان اشیاء کے لیے علت ہیں کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے قدیم تھے جیسے کہ افلاک اور وہ ہمیشہ نوعِ حوادث کے لیے علت بنتے ہیں اور وہ حادث معین کے لیے علتِ تامہ بنتا ہے بعد اس کے کہ وہ علتِ تامہ نہیں تھا یہی ان کے قول کی حقیقت ہے ۔
پس ان کو جواب میں کہا جائے گا کہ اس کا کسی شے کے لیے عدم (ناپید ہونے )کے بعد علتِ تامہ ہونا بغیر کسی ایک ایسے سببِ حادث جس کی وجہ سے وہ پیدا ہواہو یہ بذاتِ خود ممتنع ہے کیوں کہ حوادث کے لیے تو اس (اللہ تعالیٰ )کی ذات کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں لہٰذایہ امرممتنع ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ذات ہوجو اس کی فاعلیت(تاثیر) اور علت بننے کو وجود دے اور اس کا کسی معین شے کے لیے فاعل بننے کو وجود نہیں دیتا مگر اس کی ذات ہی ،پس لازم آیا کہ وہی محدث اور پیدا کرنے والے ہیں کیوں کہ معین اشیاء کے لیے وہی علت ہے اور فاعل بھی وہی ہیں اور یہ فاعلیت موجود ہوئی بعد اس کے کہ وہ نہیں تھی (معدوم تھی )پس یہ بات ممتنع ہوئی کہ وہ کسی علتِ تامہ ازلیہ سے صادر ہوں کیوں کہ علتِ ازلیہ تو اپنے معلول کے ساتھ مقارن ہوتی ہے پس یہ بات واضح ہوگئی کہ یہ امر ممتنع ہے کہ وہ کسی شے کے لیے فاعل بنے بعد اس کے کہ وہ نہیں تھا حالانکہ وہ علتِ تامہ ازلیہبھی ہوں اور وہ احوال اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو ں جو اس کے حوادث کے لیے فاعل ہونے کو ثابت کرتے ہیں تو خواہ وہ بالواسطہ حادث ہوں یا بغیر واسطہ کے (یعنی ان دونوں امور کا اجتماع ممتنع ہے )نیز یہ بھی کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اس (پیدا کرنے والی ذات )کا حال حادثِ معین کو پیدا کرنے سے پہلے اور اسی طرح معین شے کو پیدا کرتے وقت اور اسی طرح معین شے کو پیدا کرنے کے بعد تینوں احوال میں اس کی حالت ایک جیسے ہے تو پھر تو کسی معین چیز کا احداث ممتنع ہوا اور یہ بات ممتنع ہوئی کہ وہ کسی بھی شے کو پیدا کر لے ۔اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس کا اول کو پیدا کرنا دوسرے کے احداث اور اس کو پیدا کرنے سے اولیٰ اور احق نہیں (یعنی دونوں حادث اس کی صفت احداث کے ساتھ ایک ہی نسبت رکھتے ہیں کسی ایک کو دوسرے پر اولویت یا فوقیت حاصل نہیں )اور تخصیص کا کوئی سبب بھی نہیں پایاجارہایعنی اس کی قدرت اور اس کی وصف کے ساتھ اول کی تخصیص دوسرے کی بہ نسبت اولیٰ نہیں بشرطیکہ فاعل سے کوئی ایسا سبب صادر نہ ہو جو (مقدار یا وصف کیساتھ )تخصیص کو ثابت کرتا ہو ۔
انہوں نے تو ان لوگوں پرنکیر کی ہے جو اہل نظر میں سے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فیض صادر ہوا بعد اس کے کہ وہ فاعل نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ بدیہی عقل سے یہ بات معلوم ہے کہ جس ذات نے کوئی فعل انجام دیا بعد اس کے کہ وہ فاعل نہیں تھا تو یہ امرضروری ہے کہ اس کے لیے (پیدا کرنے کے واسطے ) اسباب میں سے کوئی سبب دھیرے دھیرے جدت کو اختیار کرتا ہو؛ خواہ وہ قدرت یا ارادہ ہو یا علم یا مانع کا زوال یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی سبب ۔
پس ان کو جواب میں کہا جائے گا کہ بدیہی عقل کے ذریعے تو یہ بات بھی معلوم ہے کہ جس نے کسی ایک حادث کو پیدا کرلیا بعد اس کے کہ اس کا وہ فاعل نہیں تھا تو یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا سبب متجدد ہو جو اس کے فعل (احداث )کا تقاضہ کرتا ہو جبکہ تم نے تو دوسروں پر اس بات میں نکیر کی ہے کہ وہ بغیر کسی سببِ حادث کے فعل کی ابتدا کے امکان کے قائل تھے یعنی سبب کے بغیر کسی فعل کی ابتدا ہو سکتی ہے اور اب تم نے خود بغیر کسی سبب حادث کے مفعولاتِ حادثہ کے دوام کا التزام کر لیا (یعنی اس کے قائل ہو گئے )پس جس بات کے تم قائل ہوئے ہو اور تم نے اس کا التزام کیا ہے یعنی بغیر کسی سبب کے حوادث کا حدوث یہ تو اس بات سے بہت بڑا اور زیادہ شنیع ہے جس کی تم نے نفی کی ہے بلکہ تمہارا قول تو اس بات کو مستلزم ہے کہ حوادث کے لیے ابتداء ً کوئی فاعل ہی نہیں بلکہ بغیر فاعل کے حادث ہوتے ہیں کیوں کہ حوادث کو پیدا کرنے والی ذات تمہارے نزدیک حرکتِ فلک ہے اور حرکتِ فلک تو ایک نفسانی حرکت ہے جو ان امور کی وجہ سے متحرک ہوتی جو اس میں دھیرے دھیرے پیدا ہوتی ہیں یعنی تصورات اور یکے بعد دیگرے پیدا ہونے والے ارادے اور اگرچہ وہ ایک تصورِ کلی اور ارادہ کلیہ کے تابع ہیں پھر تمہارے قول کی بنیاد پر وہ تصورات ، ارادے اور حرکات بغیر کسی موجد (وجود دینے والا)اور محدث کے پیدا ہوتے ہیں کیوں کہ تمہارے نزدیک واجب الوجود کی ذات میں کوئی ایسی صفت نہیں پائی جاتی جو کسی فعلِ حادث کے لیے موجب بنے بلکہ اس کی حالت تو حادث کے وجود سے پہلے ،اس کے حادث ہوتے وقت اور اس کے حدوث کے بعدتینوں احوال میں برابر ہے اور کسی فاعل کا امورِ حادثہ مختلفہ کو اس طرح وجود ینا کہ اس فاعل کی حالت ان حوادث کے موجود ہونے سے پہلے ،ان کے وجود میں آتے وقت اور اس کے بعد رتینوں حالتوں میں برابر ہوتو یہ اس بات سے زیادہ أبعد ہے کہ وہ صرف کسی ایک حادث کو پیدا کرے باوجود یکہ اس کی حالت تینوں حالتوں میں برابر ہو ۔
٭ اگر کہا جائے کہ اس کے فعل کا تغیر مفعولات کے تغیرات کی وجہ سے ہے۔
٭ تو جواب میں کہا جائے گا کہ اس کا فعل (یعنی احداث )اگر تمہاری رائے کے مطابق وہی مفعولات ہیں جس طرح کہ ابن سیناا ور اس کے امثال دیگر فلاسفہ جہمیہ اس کے قائل ہیں جو صفات اور فاعل کی نفی کرنے والے ہیں تو پھر تو متغیر شے اس سے منفصل اور جدا ہونے والی اشیاء ہیں اور وہی تو مفعولات ہیں اور یہاں مفعولات کے علاوہ کوئی ایسا فعل نہیں پایا جاتا جس کو تغیر کے ساتھ موصوف کیا جائے پس اس کے تغیر کاسبب کیا بنا اور اس کے اختلاف کا سبب کیا بنا اور اس طرح ان حوادث کے حدوث کا سبب کیا بنا باوجود یکہ فاعل حالتِ واحدہ پر قائم ہے اور صریح عقل کے اعتبار سے اس قول کا فساد دوسروں کے اس قول کے فساد سے زیادہ ظاہر ہے جس پر تم نے نکیر کیا ہے ۔
اگر اس کا فعل اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے جس طرح کہ افعالِ اختیاریہ کے مثبتین کہتے ہیں یعنی اہل ملل کے بعض آئمہ اور فلاسفہ متقدمین اور متاخرین میں سے ہیں تو یہ بات معلوم ہے کہ مفعولات کا تغیر ہی ان افعال کا سبب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام مفعولات (کی ذوات )اور ان کے تغیرات کو پیدا کرنے والے ہیں پس یہ بات ممتنع ہے کہ وہی (مفعولات )خود مؤثر ہوں اس کے فعل کے تغیر میں جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس لیے کہ یہ تو اس امرکو مستلزم ہے کہ وہ معلول جومخلوق اور مصنوع ہے وہی اس خالق ذات میں مؤثر بنے جو کہ صانع ہے یعنی بنانے والا ہے جس کو وہ علتِ تامہ کہتے ہیں اور یہ تو دورِ ممتنع کو مستلزم ہے اس لیے کہ دو شئین میں سے ہر ایک کا دوسرے میں مؤثر ہونا بغیر اس کے کہ وہاں کوئی ایسا امر ثالث پایا جائے جو ان کے غیر ہو اور ان دونوں میں مؤثر ہو اور یہ وہ دور ہے جو ممتنع ہے اس لیے کہ دو فاعلین میں سے کوئی ایک دوسرے میں تاثیر اور عمل نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ دوسرا اس میں تاثیر اور عمل کرے جس طرح کہ اس صورت میں ہے تو لہٰذا وہ تغیر جو حادث ہے وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرا اس کو پیدا کرے بوجہ اس کے کہ وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے ۔
اگر وہ فعل اس کی ذات کے ساتھ قائم نہ ہو یہاں تک کہ وہ دوسرا فاعل اس کو پیدا کرے تو یہ بات لازم آئے گی کہ وہ موجود نہ ہو یہاں تک کہ خود وہ موجود ہو جائے اور وہ دوسرا موجود نہ ہو یہاں تک کہ پہلا موجود ہو جائے یعنی ہر ایک کا وجود دوسرے کے وجود پر موقوف ہو جائے گا لہٰذا یہ اس کو مستلزام ہوا کہ ان دنوں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو یہاں تک کہ دوسرا موجود ہوجائے قبل اسکے کہ پہلا موجود ہو تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔
اگر کہا جائے کہ وہ متغیر ہونے والا مفعول جو کہ اول ہے اُس نے فاعل کے اندر ایک تغیر پیدا کیا اور اس تغیر نے تغیر ثانی کو پیدا کر لیا تو جواب میں کہا جائے گا کہ وہی اول تو ایک ایسے فعل سے پیدا ہواہے جو فاعل کے ساتھ قائم ہے پس فاعل اپنے ما سوا تما م حوادث متغیرہ کا فاعل ہے اولاً بھی اور آخراً بھی اور اس میں اس کے غیر نے ہر گز کوئی تاثیر نہیں کی ۔
اگر کہا جائے کہ اس کا مفعولِ ثانی تو مشروط ہے مفعولِ اول کے ساتھ پس وہ اول اور ثانی دونوں کے لیے فاعل ہے لہٰذاوہ اپنے فعل میں غیر کی طرف بالکل محتاج نہیں ہے ۔
نہ اس میں اس کی ذات کے علاوہ کسی شے نے اثر کیاہے اور یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ اسے پکاریں اور اس سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا کو قبول کریں گے اور ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اس کی اطاعت کریں تو وہ ان کی اطاعت کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کو ثواب دیتے ہیں اجر دیتے ہیں پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجابت( دعا قبول کرنے )اور اثابت (ثواب دینے )کے فاعل ہیں جس طرح کہ اس نے پہلے بندوں کو دعا مانگنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے بنا دیا اور اس وقت وہ قطعاً کسی غیر کی طرف محتاج نہیں تھا اور جس نے بھی ان امور میں بغور سوچا تو اس کے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ان افعالِ اختیاریہ کے ذریعہ جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں ،تمام اعیان ، صفات اور افعال میں سے ہر شے کے خالق ہیں جس طرح انبیاء کے بہت سے نصوص اس پر دال ہیں اور امت کے سلف اور آئمہ اس پر متفق ہیں اور ان کے ساتھ موافقت کی ہے فلاسفہ قدماء کے بڑے بڑے آئمہ نے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ کی ذات کے ماسوا ہر شے کے حدوث کو واضح کرتی ہے اور اس بات کو بھی (واضح کرتی ہے )کہ یہ معلولِ قدیم کے لیے علتِ ازلی نہیں ہے باوجود کہ وہ فاعلیت کے اعتبار سے بالکل دائم ہے اور اس کے فاعل کے دوام سے یہ امر لازم نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کوئی مفعولِ معین قدیم بھی ہو بلکہ یہ تو انتہائی درجے کی باطل بات ہے اور وہ فلاسفہ جو ایک ایسی ذات سے عالمِ قدیم پیدا ہونے کے قائل ہیں جو عالم کیلئے موجب بذاتہ ہے جس کو یہ علتِ تامہ ازلیہ کہتے ہیں ،وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ازل میں ہر حادث کے لیے علت تامہ نہیں اس لیے کہ اس کا تو کوئی شخص بھی قائل نہیں ہے کیوں کہ علتِ تامہ تو وہی ہے جو اپنے معلول کو مستلزم ہو اور اسکے متصل بعد ہو پس جب معلول حادث ہوا بعد اس کے معدوم تھا تو اس کا مستلز م بھی تو پھر ازلی نہیں رہا کیوں کہ اس میں تو پھر معلول کا اپنی علت سے زمان کے اعتبار سے تاخیر لازم آئے گی ایسی تراخی جس کی کوئی انتہاء نہیں ہے یعنی علتِ تامہ ازلیہ سے تراخی اور یہ امر نا ممکن ہے کیوں کہ ہر حادث تو عالم کے اندر ہی وجود میں آتا ہے اور وہ ازل سے ایک ایسے تاخر کے ساتھ متاخر ہوتا ہے جس کی کوئی انتہاء نہیں ۔
پس اس کی اگر اس کی علتِ تامہ ازل میں ثابت ہو جائے تو معلول اپنی علتِ تامہ سے ایسے تاخر کے ساتھ متاخر ہو گا جس کی کوئی انتہاء نہیں اور علت تامہ اور اس کے معلول کے اندر تو اصلا کوئی فصل اور جدائی نہیں ہوتی بلکہ نزاع تو اس میں ہے کہ کیا اس کے ساتھ کوئی زمان یا اس کے بعد کوئی زمان پایا جاتا ہے یا وہ زمان کے اعتبار سے اس کے ساتھ ہوتا ہے یا زمان کے اعتبار سے اپنی علت کے بعد ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ایک جزکی طرح ہوتاہے تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ لوگ اس میں کلام کرتے ہیں کیوں کہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اس پرتاخرعقلی کے ساتھ متاخر ہے اور اس پربھی (متفق ہیں )کہ وہ اس سے منفصل نہیں ہوتا یعنی معلول علت سے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ زمان کے اعتبار سے متصل ہے اور اقتران زمانی اس کو حاصل ہے تو یہ لوگوں کے ہاں محل نظر ہے اور محل خلاف ہے ، مقصود تو یہاں یہ بات ہے کہ عالم میں جو شے بھی حادث ہے تو اس کی وہ علتِ تامہ جو اس کو مستلزم ہوتی ہے وہ اس سے پہلے تام نہیں ہوتی اس طور پر کہ ان کے درمیان کوئی انفصال پایا جائے پس وہ کیسے اس پر ایسے تقدم کے ساتھ متقدم ہوگی جس کی کوئی انتہاء نہیں بلکہ جو بات یہ کہتے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ان اشیاء کے لیے علت تامہ ازلیہ ہیں جو عالمِ میں قدیم ہیں جیسے کہ افلاک ۔
رہی وہ اشیاء جو عالم میں حادث ہیں تو ان کے لیے وہ ان کے حدوث کے وقت علتِ تامہ بنتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اول کا حدوث دوسرے کے حدوث میں شرط ہے جیسے چلنے والا شخص زمین کے ایک حصے کو دوسرے کے بعد طے کرتا ہے جیسے کہ حرکتِ شمس جس کے ذریعے تو ایک مسافت دوسرے کے بعد طے کرتا ہے اسی طرح کوئی بھی متحرک جسم مسافتِ ثانیہ کو اس وقت تک طے نہیں کرتا جب تک کہ مسافتِ اولیٰ کو طے کرے ،یعنی مسافت ِ اولیٰ کو اپنی حرکت کے ساتھ طے کرنا مسافت ثانیہ طے کرنے میں شرط ہے اور ثانی مسافت کے طے کرنے کے لیے جو علتِ تامہ ہے وہ تو پہلی مسافت کیلئے بننے والی علت تامہ کے بعد وجود میں آئی اور یہی ان کے اقوال کا انتہائی درجے کا مقصود ہے اور اس کو وہ مختلف عبارات سے تعبیر کرتے ہیں تبھی تو یہ کہتے ہیں کہ علت اولیٰ کا فیض ،مبدِء اولی کا فیض اور واجب الوجود یعنی اللہ کا فیض سب دائم ہیں لیکن وہ متاخر ہوتا ہے تاکہ استعداد اور فیض کا اثر قبول کرنے کے لیے ایک قابل (اثر قبول کرنے والا)پیدا ہو جائے ۔
اس طرح استعداد کا سبب پیدا ہو جائے یہ اکثروں کی رائے ہے اور اکثر تو اس کے قائل ہیں کہ یہ حرکتِ فلک ہے پس ان لوگوں کے نزدیک عالم کے تغیرات کے لیے سوائے حرکتِ فلک کے اور کوئی سبب نہیں جیسے کہ ابن سینا اور ان کے امثال کہتے ہیں اور یہ ارسطوکے اصحاب کے ہاں معروف ہے ۔
وہ فلاسفہ جو ان کے علاوہ ہیں اوران سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں جیسے ابو البرکات اور ان کے علاوہ دیگرفلاسفہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تغیرات کا سبب تو وہ اارادات متجددہ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں یعنی وہ ارادات جو دھیرے دھیرے وجود میں آتی ہیں بلکہ ادرکات بھی؛ جیسے کہ اس نے اپنی کتاب ’’المُعْتَبَرْ‘‘ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔
ابن سینا اور ان کے امثال تو کہتے ہیں کہ :وہ عالم کے لیے بذات خود علتِ تامہ ازلیہ ہیں بشمول ان حوادث ِ متجددہ کے جو عالم میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ کہ حادثِ اول شرط ہے اور اس نے حادثِ ثانی کے لیے استعداد اور قابل (اثر قبول کرنے والا) کو پیدا کر دیا اور یہ اانتہائی درجے کا فاسد قول ہے اور یہ قول ان کے اصول کیساتھ انتہائی درجے کے تناقض اور تصادم پر مشتمل ہے اور وہ (قول یہ ہے کہ )حادثِ ثانی کی جو علت ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس کے وجود کے وقت بتما مہ موجود ہو اور حادثِ ثانی کے وجود کے وقت تو فاعلِ اول کے ہاں کوئی ایسا امر متجدد نہیں تھا جس کو وہ کرتا سوائے اول کے عدم کے اور محض اول کے عدم (ناپیدا ہونے )نے تو ان کے نزدیک فاعل کے لیے کوئی قدرت اور ارادہ پیدا نہیں کیا اس لیے کہ اول تو ان کے نزدیک اس کے ساتھ صفات اور افعال میں سے کوئی شے بھی اس کی ذات کیساتھ قائم نہیں اور نہ اس کے لیے مختلف قسم کے احوال ثابت ہیں پس کیسے یہ بات متصور اور ممکن ہو سکتی ہے کہ اس سے ثانی صادر ہو جائے بعد اس کے کہ اس کا صدور اس سے ممتنع تھا اور اس کا حال متجدد نہیں ہوا بلکہ وہی حال رہا(یعنی جو حال اول کے احداث کے وقت تھا وہی ثانی کے احداث کے وقت بھی ہے ) صرف ایک امر عدمی نیا وجود میں آیا جس نے اس کے لیے کوئی قدرت یا ارادہ یا علم کا اضافہ یا اس کے علاوہ اور کوئی شے پیدا نہیں کیا۔
یہ اس صورت کے بخلاف ہے جس کی یہ مثال دیتے ہیں انسان کی حرکت کے ساتھ جو کہ ارادۃً یا طبعاً ہو اس لیے کہ بے شک جب کوئی متحرک مسافتِ اولیٰ کو طے کرتا ہے تو اس کو ایک ایسی قدرت حاصل ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے اس کو حاصل نہ تھی اور اس کے ہاں ایک ایسا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس حال سے پہلے نہ تھا جس طرح کہ انسان اپنی ذات میں پاتا ہے جب کہ وہ چلنے لگتا ہے اس لیے وہ اپنے نفس میں مسافتِ بعیدہ کو طے کرنے سے عجز پاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو پہنچ جائے اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے اس کے طے کرنے کا پختہ ارادہ کرنے والا ہوتا ہے جب وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اس حال میں اس مسافت کے طے کرنے کا ارادہ کرنے والا نہیں ہوتا پس جب وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کے طے کرنے کا ارادہ کرنے والا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے طے کرنے پر قادر بھی بن جاتا ہے اور پکے ارادے اور قدرتِ تامہ کی صورت میں مراد کا پایا جانا ضروری ہے۔ پس ایسی صورت میں جو کچھ مسافت کو طے کیا جاتا ہے وہ محض اس حرکت کے معدوم (متلاشی )ہونے کی وجہ سے نہیں جس کے ذریعے مسافتِ اولیٰ کو طے کیا تھا بلکہ (مسافت ثانیہ کو )اس قدرت اور ارادے کی وجہ سے (طے کیا )جو دھیرے دھیرے نئے پیدا ہو رہے ہیں ۔ پس یہ قدرت اور ارادے جو متجدد ہیں اور ہر آن اور لحظہ میں نئے پیدا ہو رہے ہیں اور تقاضہ کر رہے ہیں اس مسافت کے طے کرنے کا تو یہ وہ کلی ارداے اور استعداد ہیں جو اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور پہلی مسافت کا طے کرنا اس (مسافت ثانیہ کے طے کرنے )سے مانع تھا پس جب وہ مانع زائل ہوا تو مقتضی نے اپنا عمل کر لیا پس اس کا ارادہ اور اس کی قدرت مکمل ہو گئی اور اس نے پھر مسافت کو طے کر لیا۔
یہی حال ہے پتھر کی اوپر سے نیچے کی طرف حرکت کا؛ جب بھی وہ نیچے آتا ہے تو اس کے اندر ایک ایس نئی قوت پیدا ہوتی ہے جو اس سے پہلے اس میں نہیں تھی۔یہی حال سورج اور ستاروں کی حرکت کا ہے ۔خصوصاً اس لیے کہ وہ کہتے ہیں : ’’ اس کی حرکت اختیاری ہے؛ بوجہ ان تصوراتِ جزئیہ اور اراداتِ جزئیہ کہ جو دھیرے دھیرے پیدا ہوتے ہیں ۔ اسی طرح ان کے آئمہ نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے؛ یعنی ارسطواور اس کے دیگر اتباع نے اس لیے کہ اس کی حرکت ان کے نزدیک حرکتِ ثانیہ ہے۔ پس حرکت کے جزء ثانی کا مقتضی تام حرکت ِ اولیٰ کے بعد پایا گیا جبکہ اس سے پہلے مقتضی تام موجود نہیں تھا اور وہ تو متحرک کی ذات کے ساتھ قائم ہے یا محرک کے ساتھ قائم ہے۔ اور یہ وہی نفس ہے جس کے اندر تصورات اور جزئی ارادات اور قوتِ جزئیہ یہ نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے اور جس کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے حرکت کرتا ہے جیسے کہ چلنے والے شخص کی حرکت پس ان کے لیے یہ بات ممکن نہیں کہ وہ کسی ایسے محرک یا متحرک کو ذکر کریں جس کی حالت حرکت سے پہلے اور حرکت کے بعد دونوں حالتوں میں برابر ہو اور اس کی حرکت بھی شیئاً فشیاً صادر ہو اس لیے کہ یہ ایسا امر ہے جس کے لیے کوئی خارج اور نفس الامر میں کوئی وجود نہیں اور عقلِ صریح اس بات کو محال سمجھتا ہے اس لیے کہ کوئی بھی حادث صرف اسی وقت وجود وجود میں آتا جب اُس کا موجب تام اور علتِ تامہ موجودہوتی ہے ۔
اگر تو چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کے وجود کو عدم پر ترجیح حاصل نہیں ہوتی مگر اس کی صورت میں کہ اس کا مرجح تام وجود میں آجائے جو اس کے وجود کو مستلزم ہو اور مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے تو وہ موجود ہو جاتا ہے اور جس کو نہ چاہیں تو وہ موجود نہیں ہوتا پس اگر حرکت ثانیہ کا مرجح تام حرکتِ اولیٰ کے وقت حاصل تھا تو اس کا حصول حرکتِ اولیٰ کے وقت بھی ضروری تھا بلکہ اس کا حصول کسی مرجح تام کے حصول کے وقت ہی تام ہوتا ہے اور یا خواہ وہ زماناً اس کے ساتھ متصل ہو اور جب مرجح تام کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ وجود میں آجائے بعد اس کے کہ وہ موجود نہیں تھا تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ حرکت کے لیے کوئی ایسا سببِ حادث بھی پایا جائے جو اس امرکو ثابت کرتا ہو کہ وہ اس کو پیدا کرنے والا بنے بعد اس کے کہ وہ معدوم تھا یہی حال اس سببِ اول کا ہے جو حرکت کے قریب ہے ۔
اگرآہستہ آہستہ حادث ہونے والی حرکت کے لیے فاعل ارادہ تامہ اور کلیہ ہے تو وہ اکیلے ہی کافی ہے۔ بلکہ ایک ایسے دوسرے ارادہ جزئیہ کا ہونا بھی ضروری ہے جو اس کے ساتھ مقارن اور متصل ہو یعنی حادث کے ساتھ جس طرح کہ انسان اپنی ذات میں اس کو پاتا ہے جب سفر میں چلتا ہے مثلا مکہ کی طرف یا کسی اور مکان کی طرف تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک مقتضِی عام کا مقتضیٰ بھی کبھی عام ہوتا ہے لیکن استعدادات اور اثر کو قبول کرنے والے قوابل کے تاخر کی وجہ سے وہ متاخر ہوتا ہے جبکہ وہ غیر سے صادر ہوں یعنی ذات سے خارج ہوں جس طرح کہ طلوعِ شمس میں اس لیے کہ شمس کی طرف سے فیض عام ہے لیکن وہ موقوف ہے اثر قبول کرنے والے قوابل کے استعداد پر اور موانع کے ختم ہونے پر اسی وجہ سے اس کی تاثیر مختلف ہوتی ہے اور قوابل اور شروط کے اعتبار سے متاخر ہوتی ہے اور یہ (اثر کا اختلاف اور کمی زیادتی اور تقدم وتاخر )اس کی ذات میں سے نہیں (بلکہ اثر قبول کرنے والے محل کے قبولیت کی صفت کے اختلاف کی وجہ سے ہے )
اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل فعال دائم الفیض ہے یعنی اس کا فیض اور تاثیر دائم ہے اسی سے وہ تمام اشیاء جواس سے فیض حاصل کرتی ہیں جو کہ عالم میں ہیں یعنی جسمانی اور نفسانی صورتیں ۔پس اسی سے علوم اور ارادات کا فیض مستفاد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر امور کا اوروہ ان کے نزدیک قمر کے فلک کے ماتحت جتنا کچھ ہے اس کا رب ہے لیکن وہ ان کے ہاں مستقل نہیں بلکہ اس کا فیض استعدادات اور ان قوابل کے حصول پر موقوف ہے جو حرکاتِ افلاک کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اور وہ حرکات جو قمر کے فلک سے سے بھی اوپر ہیں وہ اس کی ذات سے مستفاد نہیں بلکہ اس کے غیر سے ہیں اوران کے نزدیک یہ عقل ہی رب البشر ہیں اور اسی سے وحی اور الہام کا فیضان ہوتا ہے تبھی تو اس کو جبریل کا نام دیتے ہیں اور کبھی جبریل کو وہ ذات قرار دیتے ہیں جو پیغمبر کے نفس کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی صورتِ خیالیہ اوریہ سارا کلام انتہائی درجے کا باطل کلام ہے جس طرح کہ اس کو اپنے مقام پر تفصیل سے بیان کیا گیا ۔
لیکن یہاں تو مقصود یہ ہے کہ وہ واجب الوجود کے فیض کی مثال اس عقلِ فعال اور سور ج کی فیض کے ساتھ دیتے ہیں حالانکہ یہ باطل تمثیل ہے ا س لیے کہ یہاں فیضان کرنے والا اپنے فیض میں اور اثر پہنچانے میں مستقل بذاتہ نہیں بلکہ اس کا فیض تواس شے پر موقوف ہے جواس کی ذات ایک غیر اس کے اندر پیدا کرتا ہے یعنی استعداد اور قبول اور اس کے غیر کا جو احداث ہے وہ تو اس کی ذات کے علاوہ اورشے کی تاثیر ہے اور رب العالمین کے حق میں تو وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ مخلوق پر فیضان میں اور تاثیر میں اس کے لیے کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی بھی فیض غیر کے فعل پر موقوف نہیں بلکہ وہ قابل (اثر قبول کرنے والے )کا بھی رب ہے اور جو اثر قبول کیا جائے یعنی مقبول اس کا بھی رب ہے ،مستعد اور مستعد لہ دونوں کا رب ہے اور اُسی کی ذات سے استعداد ہے اور اسی کی ذات سے امداد یعنی فیض ہے اور جب اس قول کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ علتِ تامہ ازلیہ ہے اور اس کا فیض عام ہے لیکن وہ (اس کا فیض )قوابل اور استعدادات کے پیدا ہونے پر موقوف ہے چاہے وہ فلکی اشکال یا اختلافِ کوکبیہ کے ساتھ ہو یا س کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہو ۔ تو ان سے جواب میں کہا جائے گا کہ اگر تم کہتے ہو کہ وہ اس حادث کے لیے علتِ ازلیہ ہیں تو پھر اس کا ازل میں وجود لازم آئے گا اور گر تم یہ کہتے ہو کہ وہ علتِ تامہ تب ہی بنتا ہے جب قوابل اور استعدادت پیدا ہوں تو جواب میں تمہیں کہا جائے گا کہ جب قوابل کا پیدا کرنا بھی اسی کی ذات سے (مستفاد)ہے تو وہ دونوں کے لیے محدث (پیدا کرنے والے )ہیں پس ان دونوں کے احداث سے پہلے وہ نہ اس کے لیے علتِ تامہ ہے اور نہ اس کے لیے ،پس تم ان دونوں کو اُس نے پیدا کیا قابل اور مقبول کو پس جب اس نے ان دونوں کو پیدا کر دیا کسی چیز کے تجدد کے بغیر تو یہ بات لازم آئی کہ وہ ان دونوں کے لیے ازل ہی سے علتِ تامہ تھا یا وہ ان دونوں کے لیے علت تامہ نہیں تھا پس یہ بات لازم آئے گی کہ یہ دونوں حادث اشیاء قدیم ہوں یا حادث ہوں اس لیے کہ یقیناً ان دونوں کی علتیں اگر ازلی ہیں تو پھر ان کا قدم لازم آئے گا۔ اور اگر وہ حادث نہیں ہیں تو پھر ان کا عدم لازم آئے گا اور تم تو ان دونوں حادثین یعنی قابل او مقبول کی علت کو حادث قرار دیتے ہو بعد اس کے کہ وہ معدوم تھا یعنی وہ بتمامہ معدوم ہونے کے پیدا ہوا اوریہاں کوئی بھی ایسی شے نہیں جس نے تمام کے حدوث کو ثابت کر دیا اس لیے کہ تمام کے لیے جو فاعل ہوتا ہے اس کی حالت قبل التمام اور بعد التمام برابر ہے پس یہ امر ممتنع ہے کہ وہ اس دونوں حالتوں میں سے کسی ایک کے لیے علتِ تامہ ہو ،دوسرے کے لیے نہ ہو اور وہ سارے امور جس کو وہ فرض کرتے ہیں جس سے تمام علت حاصل ہوتا ہے وہ بھی اول کے بعد ہی حادث ہے پس تمہارے قول کی حقیقت یہ ہوئی کہ عالم کے حوادث اس کی ذات سے پیدا ہوتے ہیں باوجود یہ کہ وہ ازل سے علتِ تامہ ہیں یا یہ کہ اس کے باوجود وہ علتِ تامہ نہیں باوجود یہ کہ علتِ تامہ تو اپنے معلول کے ساتھ تامہ بنتی ہے نہ کہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد اور یہی بات تو حوادث کے عدم کا یااُن کے قدم کاتقاضہ کرتی ہے او ریہ دونوں امر مشاہدے کے خلاف ہیں اسی وجہ سے ان کے قول کی حقیقت تو یہ ہے کہ حوادث تو بغیر کسی محدث کے پیدا ہوتے ہیں ۔
ان کا حرکتِ فلک کے بارے میں قول حرکتِ حیوان کے بارے میں قدریہ کے قول کے مشابہ ہے اس لیے کہ قدریہ تو یہ کہتے ہیں کہ حیوان قادر ہے اور ارادہ کرنے والا ہے اور وہ بغیر کسی ایسے سبب کے جو فعل کے لیے موجب ہو ،فعل صادرکرتا ہے بلکہ ان اسباب کی نسبت کے باوجود جو کہ حدوث کے لیے موجب ہیں یعنی حدوث کے لیے سبب ہیں تو ان کے ساتھ ہی وہ فعل کرتا ہے بلکہ ان کے نزدیک تو اِس حادث اور اُس حادث کی طرف ان اسباب کی نسبت برابر ہے جو کہ حدوث کے لیے موجب ہے اس لیے کہ بے شک ان کے نزدیک وہ تمام امور جس پر مومن ایمان لاتا ہے اور اس کے ذریعے وہ کوئی اطاعت گزار مطیع کہلاتا ہے بتحقیق وہ ہر اس شخص کے لیے حاصل ہے جس کو ایمان اور طاعت کا حکم دیا گیا ہے لیکن فرمان بردارمومن نے ایمان اور طاعت کو ترجیح دی بغیر کسی ایسے سبب کے جس کے ساتھ وہ مختص ہے اور اس کے ذریعے رجحان (ایمان کو کفر پر)حاصل ہوا ہے اور کافر (کی شان )تو (مومن کے )بالعکس ہے ۔یہ وہی بات ہے جولوگ حرکتِ فلک کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے شک وہ اس کے ارادے اور قدرت کے ساتھ صفتِ دوام کے ساتھ متحرک ہے بغیر کسی ایسے سبب کے جو اس کے مرید بننے اور قادر بننے کا تقاضہ کرتا ہو باجود یکہ اس کا ارادہ اور اس کی قدرت اور اس کی حرکات حادث ہیں بعد اس کے کہ وہ موجود نہیں تھے بلکہ معدوم تھے اور وہ بغیر کسی ایسے شے پیدا ہونے والا ہے جس نے اس کو مرید اور متحرک بنایا پس ایک ممکن چیز حاصل ہوا بغیر ایسے مرجح تام کے جس نے اس کے رجحان کو ثابت کیا اور حادث حاصل ہوا بغیر کسی ایسے سببِ تام کے جس نے اس کے حدوث کو ثابت کیا ۔
پھر بے شک وہ لوگ قدریہ پر اس بات کی نکیر کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قادر ذات وہ اپنے دو مقدورین میں سے ایک کوبلا مرجح کے ترجیح دیتا ہے۔ بلکہ اپنے ارادے ہی سے وہ اسے پیدا کرتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے لیے کوئی اس ارادے کے علاوہ کوئی اور شے اس کی ذات میں حادث ہو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ارادے کو پیدا کر لیا بغیر کسی ارادے کو اور یہ لوگ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ابلغ ہے حرکتِ فلک میں اور وہ ان کے اصول صحیحہ میں بھی مناقض اور متصاد ہے پس یہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حادث ارادے اور حرکاتِ حادثہ صرف اور صرف ایک ایسے سبب کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں جو اس کی حدوث کی تقاضا کرنے والا ہو اور کمالِ سبب کے پائے جانے کی صورت میں اس کا حدوث واجب ہے اور اس کے نقص کی صورت میں اس کا حدوث ممتنع ہے تو بتحقیق انہوں نے اس بات کو جان لیا جو انہوں نے قدمِ عالم اور سببِ حادث کے بارے میں کہی وہ باطل ہے ۔
اس لیے یقیناً ان کے نزدیک تو فلک سے اوپر کوئی ایسا سبب نہیں پایا جاتا جو اس کے حادث ہونے والے تصورات اور ارادات کے حدوث کا موجب ہو سوائے ان ارادوں اور تصورات کے جو اس مخلوقِ کے لیے ثابت ہیں جو واجب الوجود کی طرف محتاج ہے اور یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہے کہ جو شے بالقوۃ ہو وہ فعل (وجود حسی اور حقیقی ) کی طرف نہیں منتقل نہیں ہوتا مگر کسی مخرج ذات کی وجہ سے یعنی جو اس کو قوتِ فعل کی طرف نکالے پس ضروری ہے کہ فلک سے اوپر کوئی ایسی شے ہو جو اس کی حرکت کے حدوث کا موجب ہو ۔
ارسطواور اس کے متبعین نے جو بات ذکر کی ہے کہ اول ذات وہی ہے جو فلک کو حرکت دیتا ہے اسی طرح جیسا معشوق کا عاشق کو حرکت دینا ہے اور یقیناً فلک اس کے ساتھ تشبہ (اس کے مثل ہونے کی وجہ سے )کی وجہ سے متحرک ہے اور اسی وجہ سے وہ علل کے لیے علت بنتا ہے اور اسی وجہ سے فلک کا قوام اور اس کی بقاء ہے کیوں کہ فلک کا قوام اس کی حرکت سے ہے اور اس کی حرکت کا قوام اس کے ارادے اور شوق کی وجہ سے اور اس کے ارادہ اور شوق کا قوام تو اس موجود کی وجہ سے جو کہ اس مراد پر سابق ہے جس کے ساتھ تشبہ کی وجہ سے اس کو حرکت حاصل ہوئی پس یہ کلام باوجود یکہ اس میں وہ باطل کلام پایا جاتا ہے جس کو ماقبل میں کئی مقامات پر بیان کر دیا گیا تو اس کی زیادہ سے زیادہ حد یہ ہے کہ وہ حرکتِ فلک کے لیے علت غائیہ ثابت ہو جائے گی اور اس میں حرکت فلک کیلئے علت غائیہ ثابت ہونے کی سوائے اس کے کوئی اور دلیل نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ اس کے تصورات اور حرکات کو وہی پیدا کرنے والا ہے ،اس واجب الوجود کی طرف احتیاج کے بغیر اور اس کے فاعل بننے میں علت اولیٰ کی طرف احتیاج کے بغیر جس طرح کہ محبت کرنے والا عاشق معشوق طرف حرکت کرنے کے لئے فاعل ہونے کے جہت سے محبوبِ معشوق کی طرف محتاج نہیں ہوتا بلکہ اس کے مراد اور مطلوب بالحرکۃ ہونے کی جہت سے وہ محتاج ہوتا ہے اور اس کا مطلب تو یہ ہو کہ حرکاتِ محدثہ اور تمام متحرکات رب العالمین سے مستغنی ہیں نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ ان حوادث میں کسی شے کے لیے بھی فاعل نہیں اور نہ وہ انکار ب ہے ۔
اگر وہ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اس نے فلک کو پیدا نہیں کیا بلکہ وہ (فلک)تو قدیم واجب الوجود بذاتِ خود ہے اور وہ عالم میں سے کسی شے کا رب نہیں تو اگر وہ کہیں کہ یہ وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے تو یہ ان کی طرف سے ایک ایسا تناقض ہے جیسے کہ قدریہ کے اقوال میں تناقض پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس ذاتِ فلک کو اور اس کی صفات کو پیدا کرنا یہ اس امرکو ثابت کرتا ہے کہ اس میں سے کوئی شے بھی حادث اورموجود نہ بنے مگر رب تعالیٰ کے فعل اور اس کے احداث کے ساتھ جس طرح کہ باقی حیوانات بھی تب ہی حادث ہوتے ہیں جب رب تعالیٰ ان کو پیدا کرتا ہے اور ان کا احداث کرتا ہے پس یہ قول اس تعطیل عام اور اس تعطیل خاص کے درمیان متردد ہے جس میں وہ قدریہ سے زیادہ بد تر ہیں اور رہا ان کا قدریہ پررد کرنا تو یہ بالکل باطل ہے کیونکہ وہ (قدریہ )ہر تقدیر پر حالانکہ اِن سے بہتر ہیں۔
بتحقیق اِس مقام پراُس کلام کو ذکر کر دیا گیا ہے جو انہوں نے ارسطوکی طرف نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے اور اس خطاء اور گمراہی کو بیان کیا ہے اس کے علاوہ مقام بھی اور بتحقیق یہ قوم اللہ کی معرفت ،اس کے مخلوق کی معرفت ،اس کے امر اور اس کی صفات ،ان تمام کی معرفت سے بہت زیادہ دور ہیں اور یقیناً یہود و نصاریٰ تو ان سے اس باب میں بدرجہا بہتر ہیں اور یہ وہ طریقہ ہے جس پر علت اولیٰ کے اثبات میں ارسطواور اور قدمائے فلاسفہ چلے ہیں اور وہ حرکتِ فلک کے لیے حرکتِ ارادیہ کے اثبات کا طریقہ ہے اور انہوں نے علتِ غائیہ کو ثابت کیا ہے جس طرح کہ ذکر کر دیا گیا ہے پس ابن سینا اور متاخرین میں سے ان کے امثال نے دیکھا کہ اس میں گمراہی پائی جاتی ہے تو وہ وجود اور امکان کے راستے کی طرف منحرف ہوئے اور انہوں نے متکلمین کے طریقے سے اسے چوری کیا جو کہ معتزلہ تھے پس یقیناً انہوں نے محدث (خالق )کے لیے محدث (مخلوق )کی ذات سے استدلال کیا پس ان لوگوں نے ایک ممکن سے واجب پر استدلال کر لیا اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو واجب الوجود ذات کی اثبات پر دلالت کرتا ہے رہا اس کے تعین کا اثبات تو اس میں یہ ایک اور دلیل کی طرف محتاج ہیں اور وہ پھر ترکیب کے طریقے پر چلے ہیں اور یہ بھی معتزلہ کے کلام سے چوری کیا ہوا ہے ورنہ تو ارسطوکا کلام الٰہیات میںباوجود کثرتِ اخطاء کے انتہائی کم ہے لیکن ابن سینا اور اس کے امثال نے اس میں توسع پیدا کیا اورالہیات اور نبوات اور آیات کے اسرار اور عارفین کے مقامات (مراتب )میں انہوں نے کلام کیا بلکہ ارواح کے معاد (روح کا جسم کی طرف واپس لوٹنا )میں بھی ایک ایسا کلام انہوں نے پیش کیا جو ان لوگوں کے ہاں نہیں ملتا اور اس میں جو کچھ ٹھیک باتیں پائی جاتی ہیں تو اس میں وہ انبیائے کرام کے طریقے پر چلے ہیں اور جو خطا ء ہیں تو اس میں انہوں نے اپنے سلف کے اقوال پر اپنی بنیاد رکھی ہے اسی وجہ سے ابن رشداور اس کی دیگر فلاسفہ کہتے ہیں کہ ابن سینا نے وحی ،منامات ،مستقبلات پر علم کے اسباب اور ان کے امثال کے بارے میں انہوں نے جو بات ذکر کی ہے وہ ایک ایسا امر ہے جوانہوں نے اپنی طرف سے اس کو ذکر کیا ہے اور اس سے پہلے مشایخ جو کہ ان کے سلف ہیں انھوں نے ایسی بات نہیں کہی۔