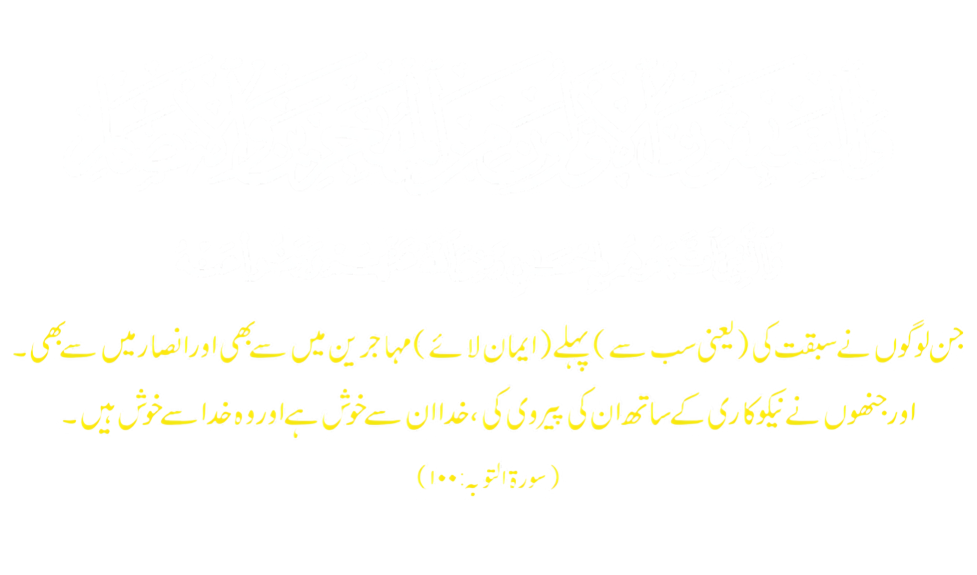ابن ملکا اور اس کے متبعین کا فلاسفہ کے اسلاف پر رد
امام ابنِ تیمیہؒابن ملکا اور اس کے متبعین کا فلاسفہ کے اسلاف پر رد
رہے ابو البرکات یعنی صاحب ’’المعتبر‘‘ اور اس کے امثال تو وہ لوگ اس باب میں ان دونوں فریقین کی بہ نسبت اچھے قول کو اختیار کرنے والے ہیں اس لیے کہ ایک تو وہ لوگ ان کی تقلید نہیں کرتے دوسرے وہ عقلی نظر کے طریقے پر چلے ہیں بغیر تقلید کے اور انوارِ نبوت سے بھی ان کو استفادہ حاصل ہے پس اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جزئیات کا علم ثابت کیا اور اپنے سلف پراس نے اچھے طریقے سے رد کیا ،ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال کو بھی ثابت مانا اور اس کے سلف میں سے جو خطا کرنے والے تھے ان کی خطا کو واضح طور پر بیان کر دیا اور اسبابِ حوادث میں ان کے قول کے فساد کے وہ قائل ہوئے پس وہ ان لوگوں کے طریقے سے اس بات کی طرف پھر گئے کہ اس نے رب تعالیٰ کے لیے ایسے ارادات کو ثابت کر دیا جو حوادث کے لیے موجب ہیں یعنی حوادث کو پیدا کرنے والے ہیں اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور ان کا قول اس مقام کے علاوہ اور کسی جگہ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے ۔
یہ لوگ کہتے ہیں کہ :بے شک حوادث دھیرے دھیرے وجود میں حادث ہوئے بوجہ ان اسبابِ موجبہ کے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں پس وہ ایسے امور کو ثابت نہیں کرتے جو دھیرے دھیرے حادث ہوں ،مختلف الحقائق ہوں اورایک ذاتِ بسیطہ سے صادر ہوں جس کے لیے نہ کوئی صفت اور نہ کوئی فعل ثابت ہو جس طرح کہ اگلوں نے کہا تھا بلکہ وہ فلاسفہ کے بڑے بڑے آئمہ کے قول کے موافق ہیں وہ آئمہ جو ارسطوسے پہلے تھے جو اللہ کی ذات کے لیے صفات اور افعال کو ثابت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حادثِ معین اسی وقت پیدا ہواجب اس کی علت تامہ موجود ہوئی جو کہ صرف اور صرف اس کے حدوث کی حالت میں تام بنتی ہے اور علت کا تمام بوجہ اس کے ارادہ اور افعال کے ہے جو رب تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے ،اسی وجہ سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عالم کے لیے مدبر بنیں مگر اس کے ارادوں اور اس کے علوم کے حدوث کے قول پر (یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادوں اور علوم کو حادث مانے بغیر اس کو اس عالم کامدبر یعنی انتظام سنبھالنے والا نہیں کہا جاسکتا )۔
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے یا دوسرے طوائف کے لوگوں میں سے جس شخص نے بھی اس بات کی نفی کی ہے تو اس نے کسی دلیلِ عقلی کے ذریعے نفی نہیں کی جو اس پر دلالت کرے بلکہ محض اللہ کی ذات کی تنزیہ اور اس کے اجلال اور توقیر کے لیے کی ہے جوکہ بالکل ایک مجمل اور ناتمام بات ہے اور یقیناً اللہ کے ذات کی تنزیہ اور اس کا اجلال تو واجب ہے پس ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ حادثِ ثانی کے وجود کے وقت تو علت ِ تامہ کا وجود ضروری ہے اور صرف اول کا عدم کافی نہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ارادہ جاز مہ اور قدرت تامہ کا کمال تو حاصل ہو چکا ہے جس نے مقدور کے حدوث کو ثابت کر دیا ۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ فاعل کی حالت (حادثِ ثانی کے حدوث سے )پہلے اور (حادثِ ثانی کے حدوث کے )بعد میں ایک طرح ہے اور اس میں ایک ایسے امر کا کوئی تجدد نہیں آیا جس کے ذریعے وہ حادثِ ثانی کو وجود دے بلکہ فاعل کے احوال متنوع اور مختلف ہوتے رہتے ہیں اور خود اس کی ذات ہی تو ان احوال کے لیے موجب ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے لیکن حالتِ ثانیہ کا وجود اس حال کے عدم کے ساتھ مشروط ہے جو اس کے ضد اور مخالف ہے اور نفسِ فاعل ہی امورِ وجودیہ کا موجب ہے جو کہ حادث ثانی کے لیے موجب ہے پس واجب الوجود ذات احداث کی صفت میں غیر کی طرف محتاج نہیں ہے جیسے کہ ممکنات کا حال ہے بلکہ خود اس کی ذاتِ واجبہ ہی ہر حادث کے لیے موجب اور محدث ہے ۔
حق سبحانہ وتعالیٰ ملزوم اور اس کے لوازم دونوں کا فاعل ہیں اور دو متنافین میں سے ہر ایک کا فاعل ہیں دوسرے کے عدم کے وقت اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتاہے لیکن باتفاق عقلاء اجتماع ضدین تو کوئی شے نہیں بلکہ وہ تو جسم کو حرکت دینے پر قادر ہے اس کی تسکین کے بدلے میں اور اس کی تسکین یعنی اس کی حرکت کو ختم کرنے پر قادر ہیں اس کی تحریک کے بدلے میں (یعنی ہر ایک پر علی سبیل البدل قادر ہیں )اور اسی طرح اس کو کالا رنگ دینے پر قادر ہیں اس کے تبییض (سفید رنگ دینا )کے بدلے میں اور اس کے تبییض یعنی سفید رنگ دینے پراس کے تسوید کے بدلے میں اور وہ احد الضدین کو وجود دے سکتے ہیں دوسرے کے بغیر جب کہ اس کا وہ ارادہ تام وجود میں آجائے جو قدرتِ کاملہ کے ساتھ ہوتی ہے ۔
اس کی ذات ہی تو ان تمام امور کے لیے موجب اور محدث ہے اگرچہ اس کا فعلِ اول کا احداث ثانی کے حصول میں شرط ہے پس اس کے اندر وہ غیر کی طرف محتاج نہیں ہے بلکہ اس ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اس کی طرف محتاج ہے اور وہ خود اپنے تمام ماسوا سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔
ان لوگوں نے ان اشکالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو ان کے سلف اور اگلوں پر وارد ہوئے تھے اور ان کے تمثیل کے فساد سے اور یہ لوگ جب اپنے قول کی مثال اس امر کے ساتھ دیتے ہیں جو معقول ہوتا ہے مثلا حرکت ِ حیوان اور حرکتِ شمس تو ان کے اوپر پھر فرق کا اور نقض کا اور اس کے علاوہ دیگر امور کا اعتراض نہیں ہوتا جو کہ ان اگلوں کے اقوال پر ہوتا ہے لیکن ان سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارے لیے عالم میں سے کسی شے کا قدم کہاں ثابت ہوتا ہے اور عقلیات میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو اس پر دلالت کرتی ہو اور وہ امور جو تم اور تمہارے امثال اور لوگ بھی ذکرکرتے ہیں وہ تو فعل کے دوام پر دلالت کرتے ہیں نہ کہ کسی فعل معین کے دوام پر اور نہ کسی مفعولِ معین کے دوام پر پس کہاں تمہارے لیے فلک کے دوام یا مادہ فلک کا دوام یا عقول یا نفوس کا دوام یا اس کے علاوہ دیگر ثابت ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں کا اختیار کردہ قول ہے جو قدم عالم کے قائل ہیں یعنی کہ وہ قدیمِ ازلی ذات ہے وہ ازل سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے اور وہ رب تعالیٰ کے ساتھ مقارن ہیں اور اس اپنی قدم کے ساتھ قدیم ہیں اور اپنی ابدیت کے ساتھ ابدی ہیں ۔پس اولا تو ان سے بات کی جائے گی دلیل کے مطالبہ کی اور ان کے ہاں اس پر کوئی دلیلِ صحیح قطعا موجودنہیں ۔
بلکہ یہ ان متکلمین اور فلاسفہ کے قول کی طرف مائل ہوئے جن کی رائے یہ ہے کہ جنسِ کلام اور فعل ممکن بنا بعد اس کے کہ ممتنع تھا بغیر کسی نئے ارداے کے پیدا ہونے کے اور فاعل ذات قادر بنابعد اس کے کہ وہ قادر نہیں تھا اور یہ کہ وہ حوادث کو پیدا کرتا ہے بغیر کسی زمان کے اور یہ بھی کہ وہ ازل سے قدیم ہے اور فعل اور کلام سے اس کی ذات معطل ہے وہ نہ کلام کرتا ہے اور نہ ازل میں وہ کسی شے کا فاعل ہے یہاں تک کہ پھر اس نے کلام کیا اور فعل بھی صادر کر دیا ۔
بہت سے تو یہ کہتے ہیں کہ فعل اور کلام سے اللہ کی ذات معطل ہو جائے گی لہٰذا جنت فنا ہو جائے گی ،ان کی حرکت بھی فنا ہو جائے گی جیسے کہ جہم بن صفوان نے جنت اور نار کے بارے میں کہا ہے اور جیسے کہ ابو االھزیل علاف نے حرکات کی فنا میں کہا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فعل اور کلام کی مدت کو اس کے ازلیت اور ابدیت کی بہ نسبت انتہائی درجے کی قلت والی مدت قرار دی ہے پس ان لوگوں نے ان مبتدعینِ جہمیہ اور معتزلہ کے بارے میں امیدرکھی اور ان متکلمین اور مبتدعین کی وجہ سے یعنی ان کی طرف میلان کی وجہ سے دوسرے اہل ملل کے احوال پر رد کیا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ قولِ صحیح تو صرف اور صرف انہی مبتدعین کا ہے اور یا یہ کہ ان فلاسفہ ملحدین کا قول ہی درست قو ل ہے ۔
ان کا قول یہ ہے کہ نقلی دلائل ان مبتدعین کے زیادہ قریب ہے اور ملحدین کے قول سے زیادہ بعید ہے پس انہوں نے کہا کہ انبیائے کرام نے مثالیں پیش کی ہیں اور ان کے لیے حقائق اشیاء کے ساتھ خبر دینا ممکن نہیں تھا اور وہ الحاد کے دروازے میں داخل ہو گئے اور اللہ کے کلام اور اس کے کلمات کو اپنے صحیح محامل اور معانی سے ہٹا کرتحریف میں مبتلا ہوگئے بسبب ان مفسدہ کے جو ان میں پایا جاتا ہے یعنی سمعیات اور نقلی دلائل کا انکار۔ اگرچہ وہ فلاسفہ جنہوں نے رب تعالیٰ کی صفات اور اس کے ان افعال کی نفی کی جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور وہ فلاسفہ جوان سے پہلے گزرے ہیں وہ الحاد اور تحریف کے اعتبار سے ان لوگوں سے زیادہ فساد میں مبتلا ہیں جنہوں نے صفات اور امور اختیاریہ کو ثابت کر دیا لیکن ا س کے باوجود قدمِ عالم کا قول اختیار کیا اور دونوں جماعتیں صریح معقول سے نکل گئی ہیں جس طرح کہ صریح منقول سے بھی یہ رو گردانی کر چکے ہیں بسبب ان غلطیوں کے جو اس باب میں انہوں نے کی ہیں اور ہر وہ شخص جو حق میں سے کسی بھی شے کا اقرار کرے تو یہ اس کے لیے دوسرے کے قبول کی طرف داعی بنتا ہے اور اس پر اُس کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے جو کہ اس شخص پر نہیں لازم ہوتا جس نے حق کو پہنچانا نہیں تھا اوررب تعالیٰ کی ذات کیساتھ قائم صفات اور افعالِ کی نفی کا قول منافی ہے اس کے اس ذات کے فاعل اور اس کے محدث ہونے کے ۔
اسی وجہ سے جب ابن سینا نے اپنے اشارات میں ان لوگوں کے اقوال کو ذکر کر دیا جو قدم اور حدوث کے قائل ہیں تو اس نے صرف اور صرف ان لوگوں کے قول کو ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دوسرے قدیم ذوات کو بھی ثابت کیا ہے جو کہ معلول نہیں ہیں اس کے لیے کہ جیسے وہ قول جو کہ ذی مقراطیس سے منقول ہے قدمائے خمسہ کا اور ابن ذکریا نے اس کو اختیار کیا ہے اور ان مجوس کا قول جو کہ دو قدیم اصلین کے قدم کے قائل ہیں اور معتزلہ میں سے متکلمین کا قول اور اس کے اصحاب کا قول پس اس نے ان اہل ملل کا قول اور آئمہ فلاسفہ کا قول ذکر نہیں کیا جنہوں نے رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہونے والے امور ِ اختیاریہ کو ثابت کیا ہے اور یہ بات کہ وہ ازل سے اپنی مشیت کے ساتھ متکلم ہیں جب بھی وہ چاہے افعال کواپنی مشیت کے ساتھ اور ان دونوں فریقین کی حجتیں اور دلائل اس نے ذکر کر دئیے ہیں اور پھر اس نے یہ اقوال پڑھنے والے کو اس بات کا حکم دیا ہے جس قول کو وہ ترجیح دیں اسی کو وہ اختیار کر لیں ساتھ اس کے کہ ضروری ہے کہ وہ اُس توحید کو بھی تھامے ہوئے ہوجو اس کے نزدیک نفس کی صفات سے عبارت ہیں اس لیے کہ اس کو اس نے بنیاد قرار دیا ہے ایسا بنیاد جو اور اس کے اور اس کے خصوم کے درمیان متفق علیہ ہے۔
امام رازی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ صفات کا مسئلہ حدوثِ عالم کے مسئلے سے متعلق نہیں اور صورتِ حال وہ نہیں ہے جو کہ امام رازی نے فرمایا ہے بلکہ صفات کی نفی تو ایک ایسی بات ہے جو قدمِ عالم کے قائلین کے شبہات کی تقویت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہونے والے افعال کے اثبات کے ساتھ ان کے ادلہ کے انتہائی درجے کا فساد ظاہر ہو جاتاہے بلکہ ان کے قول کا فساد باوجود یکہ صفات کی نفی اس کے قول کے فساد پر بھی دلالت کرتی ہے یہ اس امر سے زیادہ قبیح ہے جو ان کے مخالفین کے قول کے فساد پر دلالت کرتا ہے لیکن ابن سینا تو ان متکلمین کے درمیان پروان چڑھے جو صفاتِ رب تعالیٰ کی نفی کرنے والے ہیں اور ابن رشد کلاّبیہ کے درمیان پروان چڑھے اور ابو البرکات تو بغداد میں اہل سنت علماء اور علماء اہل حدیث کے درمیان پروان چڑھے پس ان میں سے ہر ایک کی حق سے جو دوری ہے وہ پیغمبر کے آثار کی معرفت سے دوری کے اعتبار سے ہے (یعنی جو پیغمبرکے آثار کی معرفت سے جتنا دور ہے اتنا وہ حق سے دور ہے )اور حق سے اس کے قرب پیغمبر کے آثار کے معرفت سے اس کے قرب کے اعتبار سے ہے ۔
یہ فلاسفہ حدوثِ عالم کے مسئلہ میں ان لوگوں کے قول کو باطل سمجھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جب ان کے اس قول کو باطل کر دیا تو پھر ان کا یہ قول حق رہ گیا اور فاعلیت کے دوام کے قول کو انہوں نے مجمل قرار دیا جس طرح کے ان لوگوں نے اُن کے اس قول کو یعنی کہ ہر وہ شے جو حوادث سے سابق نہ ہو تو وہ حادث ہی ہوتا ہے اس کے اِس قول کو مجمل قرار دیا ہے ۔پس ان لوگوں کے قول کا نتیجہ یہ نکال کہ جن لوگوں نے ان کے قول کو سنا تو ان میں سے اکثروں نے اللہ تعالیٰ کے ازل میں متکلم ہونے کا انکار کر لیا۔
کیوں کہ انہوں نے نوعِ فعل اور عینِ فعل کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا اور ان لوگوں کاقول تو اس بات کا سبب بنا کہ بہت سوں نے فلک کے دوام یا عالم میں سے کسی شے معین کے دوام کا گمان کر لیا کیوں کہ ان لوگوں نے نوعِ فعل اور عینِ فعل کے درمیان فرق نہیں کیا اور ’’فاعلیت کا دوام ‘‘تو ایک مجمل بات ہے کیا اس کے ذریعے فاعلیت معینہ کا دوام مراد ہے یا فاعلیتِ مطلقہ کا دوام مراد ہے ،یا فاعلیتِ عامہ کا دوام مراد ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ اگر فاعلیتِ عامہ تمام مفعولات کا دوام کہلاتا ہے تو اس کا تو کوئی بھی عاقل قائل نہیں اور کسی مفعولِ معین کے لیے فاعلیتِ معینہ کا دوام ایک ایسی بات ہے جس پر ان کے ہاں بالکل کوئی دلیل نہیں بلکہ ادلہ عقلیہ تو اس کی نفی کرتے ہیں جس طرح کہ ادلہ نقلیہ نے اس کی نفی کی ہے رہا ۔
فاعلیتِ مطلقہ کا دوام تو ان کے قول کو ثابت نہیں کرتا بلکہ وہ تو ان لوگوں کے خطا کو ثابت کرتا ہے کہ نفی کرنے والے ہیں یعنی جو ان کے مدِ مقابل ہیں اہل کلام اور فلسفہ میں سے اور اس قول کے بطلان سے دوسرے کے قول کی صحت لازم نہیں آتی ہاں سوائے اس صورت کے کہ صرف یہی دوقول ہوں ( کوئی تیسرا قول نہ ہو )۔
رہا یہ کہ اگر وہاں کوئی قولِ ثالث بھی ہے تو پھر دو قولین میں سے کسی ایک کی صحت ضروری نہیں ٹھہرے گی پس اگر قولِ ثالث ادلہ عقلیہ اور نقلیہ سے مؤید ہو ( پھر تو بطریق اولی کسی ایک قول کی صحت ضروری نہیں ) اور یہاں تومقصود یہ ہے کہ دونوں طائفتین جنہوں نے افلاک کے قدم کا قول اختیار کیا ہے وہ ملحد ہیِ خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کااس کی ذات کے ساتھ قیام کا قول اختیار کریں یا وہ یہ نہ کہیں یعنی اس کی نفی کریں پس یہ فلاسفہ باوجود اس کے کہ غلطی اور درستگی میں ،خطاء اور ثواب میں علوم الٰہیہ کے بارے میں خطاء اور ثواب میں مختلف مراتب پر ہیں بتحقیق وہ رد جو ان کی طرف متوجہ ہے وہ ان بدعات کی وجہ سے ہے جس کو ان اہل کلام نے اختیار کیا ہے اور اس کو ملتِ حق کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔
وہ فلاسفہ جو اہل کلام کی بہ نسبت مللِ حقہ کی معرفت سے انتہائی زیادہ دورہیں ان میں سے بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بھی کوئی ملت سماویہ ہیں ۔ اور بعض تودوسروں کی بہ نسبت نقلی دلائل کا زیادہ علم رکھتے ہیں پس وہ متکلمین کے کلام پر ایک ایسا رد کرنے لگے جس پر ان کے ہاں کوئی نقلی دلیل نہیں تھی۔ اور جن امور میں ان کے پاس کوئی نقلی دلیل تھی؛ اس میں انہوں نے دو قولین میں سے کوئی ایک اختیار کر لیا یا یہ کہ وہ ظاہراً اور باطناً دونوں حالتوں میں اس بات کا اقرار کریں بشرطیکہ وہ ان کے معقول کے موافق ہوں یا پھر وہ ان کو اپنے امثال کے ساتھ ملحق کریں اور وہ یہ کہیں کہ پیغمبروں نے تمثیل اور تخییل کے طریقے پر ان امور پر کلام کیا ہے بوجہ حاجت کے۔
ابن رشد اور ان کے امثال اس طریقے پر چلے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ ابن سینا اور ان کے امثال کی بہ نسبت اسلام کے زیادہ قریب ہیں اور وہ عملی احکام میں ان لوگوں کی بہ نسبت حدودِ شرح کی زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں یعنی ان لوگوں کی بہ نسبت جنہوں نے واجباتِ اسلام کو چھوڑ دیا اور اس کے محرمات کو حلال سمجھا اگرچہ ان میں سے ہر فریق کے قول میں الحاد اور تحریف پایا جاتا ہے قرآن و سنت کی مخالفت کے سبب اور ان کے قول میں درستگی اور حکمت اسی نسبت سے پائی جاتی ہے جس نسبت سے وہ کتاب و سنت کے موافق ہیں اسی وجہ سے ابن رشد حدوثِ عالم کے مسئلہ میں اور اجسام کی دوبارہ بعثت کے مسئلہ میں توقف ظاہر کرنے والا ہے اور دونوں قولین کو جائز قرار دینے والا ہے اگرچہ اس کا باطن اپنے سلف کے قول کی طرف نسبتاًزیادہ مائل ہے اور اس نے ابو حامدِ غزالی پر تھافت التھافت میں ایسا رد کیا ہے کہ اس کے بہت سے مقامات میں اس نے خطا کی ہے اور اس معاملے میں حق ابو حامد غزالی کے ساتھ ہے یعنی حق اس کی تائید کرتا ہے ۔
بعضوں نے اس کو ابن سینا کے کلام میں سے قرار دیا ہے نہ کہ اس کے سلف کے کلام میں سے اور اس میں خطاء کی نسبت ابن سینا کی طرف کر دی اور بعض نے تو اس میں ابو غزالی کی طرف زبان درازی کی اور اس کو قلت انصاف کی طرف منسوب کیا بوجہ اس کے کہ اس نے اصولِ کلامیہ اور فاسدہ پر اس کی بنیاد رکھی ہے جیسے کہ رب تعالیٰ کا کسی سبب اور حکمت سے کوئی فعل نہ کرنا اور اس طرح قادرِ مختار کا اپنے دو مقدورین میں سے کسی ایک کو دوسرے پر بلا کسی مرجح کے ترجیح دینا ۔
بعض تو اس میں بوجہ اشتباہ کے حیرت میں پڑ گئے اور اس نے اس میں کلام کیا اور میں نے ابو حامد غزالی کے قول کی تحقیق کی ہے کہ اس میں درست کتنا ہے ،اصولِ اسلام کے موافق کتنا ہے اور اس کلام کے خطاء کو بھی بیان کیا کہ جو اس کے مخالف ہے یعنی ابن رشد اور دیگر فلاسفہ کا کلام اور یہ بات بھی میں نے ثابت کی ہے کہ ان لوگوں نے کتاب و سنت کے موافق جو بات حق کی ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا بلکہ قبول کیا جائے گا اور جس میں ابو حامد غزالی نے کوتاہی کی ہے یعنی ان کے اقوالِ فاسدہ کے ابطال میں تو ایک دوسرے طریقے سے اس کا رد کرنا بھی ممکن ہے جس کے ذریعے ابو حامد کی اس کے صحیح قصدپر مدد کی جا سکتی ہے اگرچہ یہ اور اس جیسے دوسرے امثال انہوں نے اس کے اوپر زبان درازی کی ہے بسبب ان اصولِ فاسدہ کے جن میں امام غزالی نے ان کے ساتھ موافقت کی ہے اور بسبب اس کلام کے جو اس امام غزالی کی کتاب میں پایا جاتا ہے اور جو ان کے اصول کے موافق ہیں اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں اس جیسا شعر کہنا مناسب ہے:
یومان یمان اذا ماجئت ذایمن
وان لقیت معدیا فعدنانی
اس نسبت سے تو انہوں نے اس کے کلام میں سے بہت بڑے حصے کو مسلمانوں اور فلاسفہ کے درمیان ایک حدِ فاصل اور برزخ قرار دیا ہے پس مسلمان تو اس میں مشائین کی طریقے پر عقلی نظر کو تلاش کرتا ہے اور فلسفی اس کی وجہ سے اسلام کامنقاد ہوتا ہے ،اسلام قبول کرتا ہے ایک فلسفی کے اسلام کی طرح پس وہ مسلم محض نہیں بنتا نہ وہ فلسفی محض بنتا ہے مشائین [چل چلاؤ والوں ]کے طریقے پر ۔ اور رہا فلسفہ کی مطلقا نفی یا مطلقا اثبات تو یہ ممکن نہیں اس لیے کہ فلاسفہ کا کوئی ایسا مذہبِ معین نہیں جس کی وہ دفاع کرتے ہوں اور نہ کوئی ایسا قول ہے جس پر وہ متفق ہوں الٰہیات میں ،معاد کے مسئلے میں اور پیغمبروں کے نبوت اور شرائع کے بار ے میں بلکہ طبعیات اور ریاضیات میں بھی بلکہ بہت سے منطق میں بھی اور وہ اس شے پر متفق نہیں ہوتے جس پر تمام کے تمام بنو آدم متفق ہیں یعنی ان امور میں سے جو حسیات اور مشاہدہ کے قبیل سے ہیں اور ان عقلیات کے قبیل سے جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں اور جس شخص نے بھی تمام کے تمام فلاسفہ سے ان اجناسِ علوم میں سے کوئی ایک قول متفق علیہ نقل کیا ہے تو وہ ان کی فرق اور ان کے اقوالوں کے اختلاف پر علم نہیں رکھتا بلکہ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ مشائین کے طریقے میں غور کرے جو کہ ارسطوکے اصحاب ہیں جیسا کہ ثامسطیوس ،اسکندرِ افرودیس،اور برقلسمن جو کہ قدماء ہیں اور جیسے کہ فارابی ،ابن سینا ،سہر وردی (مقتول)، ابن رشد حفید اور ابو البرکات اور اس کے امثال متاخرین میں سے ہیں اگرچہ ان میں سے ہر ایک کے ہاں الٰہیات اور نبوت میں اور معاد کے بار ے میں ایسا قول ملتا ہے جو اُس کے سلف متقدمین سے منقول نہیں اس لیے کہ ان لوگوں کے ہاں اس باب میں کوئی ایسا علم نہیں جس کو ان کے اتباع اور پیروکارقبول کریں اور بے شک ان لوگوں کا اکثر علم طبیعات پر مشتمل ہے پس وہ اسی میں وہ غور خوض کرتے ہیں اور اس میں ان کا نظر دوڑتا ہے اور اسی کے سبب اِن لوگوں نے ارسطوکی تعظیم کی ہے اور اس کا مرتبہ اونچا کیا ہے اور اسی کے سبب ہے اس کی اتباع کی ہے بوجہ اس کے کہ وہ قطیعات میں اکثر کلام کرنے والا ہے اور اس میں اس کی بات دوسروں کی بہ نسبت درستگی کے زیادہ قریب ہے ۔
رہے الٰہیات تو وہ اور اس کے پیروکاراس کی معرفت سے انتہائی دوری میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کلام میں وہ پوری بات پائی جاتی ہے اور ان کے علاوہ دوسروں کے کلا م میں بھی عقلیات صحیحہ میں کوئی ایسی بات نہیں جو پیغمبروں کی تعلیمات کے خلاف پر دلالت کرتی ہو اس کے خلاف ان میں کوئی بھی دلیل ظنی نہیں ہے چہ جائے کہ قدمِ افلاک پر کوئی دلیلِ عقلی پائی جائے بلکہ افلاک میں سے کسی بھی شے کے قدم پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی اور ان کے بڑے ادلہ تو ایسے امورِ مجملہ ہیں جوکہ عام انواع پر دلالت کرتے ہیں وہ عالم میں سے کسی شے معین کے قدم پر دلالت نہیں کرتے پس جس بات کی رسولوں نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے جیسے کہ پیغمبروں نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کے درمیان (مخلوقات )کو چھ ایام میں تو لوگوں میں سے کسی شخص کو بھی یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ اس بات کی نفی پر کوئی صحیح دلیلِ عقلی قائم کر ے ۔
رہا وہ کلام جس سے متکلمین اِن پر اور اِن کے علاوہ دوسروں پررد کرنے کیلئے استدلال کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ درست اور کچھ غلط ہے ،اس میں سے کچھ وہ ہے جو شرع اور عقل کے موافق ہے اور کچھ وہ ہے جو ان کے مخالف ہیں اور ہر حال میں وہ نظر و مناظرہ اور امورِ کلیہ میں فکر اور نظر کے اعتبار سے زیادہ حاذق ہیں اور ان معقولات کا زیادہ علم رکھتے ہیں جو الٰہیات سے متعلق ہیں اور ان کا قول ان فلاسفہ کی بہ نسبت زیادہ درست ہے اور طبعیات اور ریاضیات میں کلام کرنے والے ان لوگوں کی بہ نسبت زیادہ حاذق ہیں جنہوں نے ان (طبیعیات اور رضاضیات )اُن کی طرح کو نہیں پہچانا ساتھ اس خطاء کے جو اس میں پائی جاتی ہیں ۔
یہاں تو مقصود یہ ہے کہ ان کے آئمہ اور ان حازقین سے جن کے عقول اور ان کے معارف ،الٰہیات کے مسئلے میں ارسطواور ان کے اتباع کے کلام سے بھی اونچے ہیں اور ابن سینا اور ان کے امثال کے کلام سے بھی تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ عالم میں سے کسی شے کے قدم کا قول اختیار کرنے کے لیے موجب کیا بنا ؟اور تمہارے ہاں تو اس میں سے کسی شے معین کے قدم کی کوئی دلیل ہی نہیں اور تمہارے ہاں تو فلسفہ کی بنیاد تو انصاف پرمبنی ہے اور علم کے اتباع اور پیروی پر مبنی ہے اور فلسفی تو وہی شخص ہوتا ہے جو حکمت کو پسند کرنے والا ہوتا ہے اور فلسفہ تو حکمت کی محبت کا نام ہے اور تم نے جب اُن لوگوں کے کلام میں غور وخوض کیا جنہوں نے اس باب میں کلام کیا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جو عالم میں کسی شے معین کے قدم پر دلالت کرتی ہو باوجود یہ کہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تمام جماعتوں کے جمہور علماء اس امرپر متفق ہیں کہ اللہ کے ماسوا سب کچھ مخلوق ہیں اور وہ عدم کے بعدموجود ہوئے اور یہی تو پیغمبروں اور مسلمانوں میں سے ان کے پیروکاروں اور یہود و نصاریٰ کا قول ہے۔