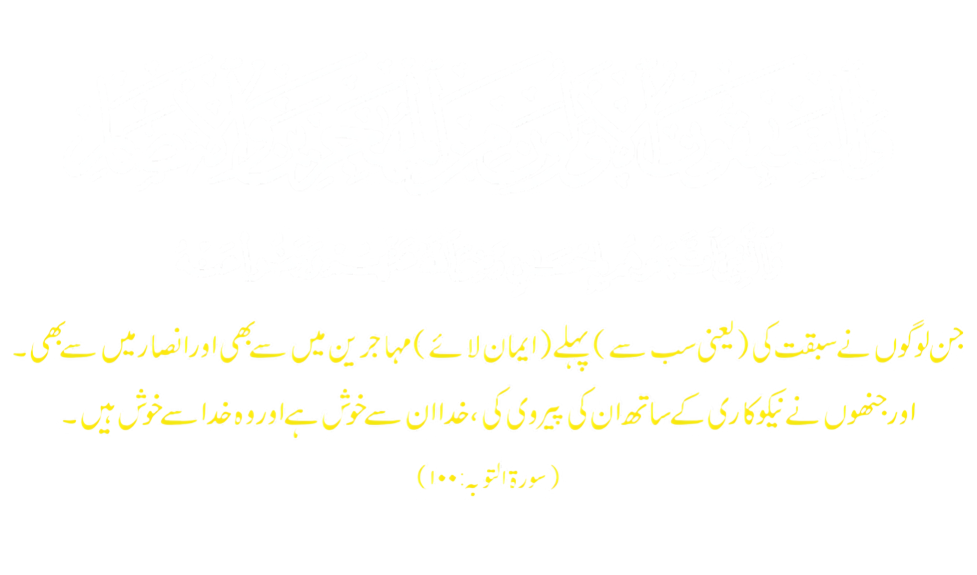ارادے کے ساتھ مراد کی مقارنت کے بارے میں تین تقدیرات
امام ابنِ تیمیہؒارادے کے ساتھ مراد کی مقارنت کے بارے میں تین تقدیرات
یہاں مقصود یہ ہے کہ جب ارادے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ارادے کے ساتھ اس کی مراد مقارنت واجب ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ماسوا تمام چیزوں کے حدوث پر دلیل ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ (یہاں تین صورتیں ممکن ہیں )
اول:.... یہ امرممکن اور جائز ہے کہ ارادے کے ساتھ اس کی مراد مقارن ہو ۔
دوم:.... یہ ارادے کے ساتھ اس کی مراد مقارن نہ ہو ۔
سوم:.... یہ کہا جائے کہ ارادے کے ساتھ اس کی مراد کی مقارنت ممتنع ہے تو ان تینوں تقدیرات پراللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا تمام چیزوں کا حدوث واجب ہے ۔
پہلی تقدیر پر تو اس لئے کہ اگر وہ ارادہ ازلی ہے تو یہ بات لازم آئی کہ تمام کے تمام مرادات ازلی ہوں پس عالم میں کوئی بھی شے حادث نہیں ٹھہرے گی حالانکہ یہ مشاہدہ اور حس کے خلاف ہے اور ہمارے اس قول کی مثال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ازل میں اشیاء کے لیے موجب اور محدث ہیں یا وہ اپنے معلول کی علت ِ تامہ ہے تو یہ بات لازم آئے گی کہ اس کے تمام موجبات اور اس کے تمام معلولات ازل میں اس کے ساتھ مقارن ہوں پس کسی بھی شے کا حدوث ممتنع ٹھہرے گا اگرچہ وہاں کوئی ارادہ حادثہ بھی پایا جائے اس لیے کہ اس میں کلام بالکل اُسی طرح ہے جس طرح کہ دوسرے حوادث میں کلام ہے کہ اگر وہ اس ارادہ ازلیہ سے حادث ہوتے ہیں جس کی اپنی مراد کے ساتھ مقارنت واجب ہے تو وہ ممتنع ٹھہرے گا اور اگر وہ بغیر کسی ارادے اور سببِ حادث کے حادث (پیدا )ہیں تو وہ ممتنع ٹھہرے گا پس واضح طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ارادے کے ساتھ مراد کی مقارنت کے وجوب کے قول پر عالم میں سے کسی بھی شے کا قدم ممتنع ٹھہرے گا خواہ ارادے کے قدم کے قول کو اختیار کیا جائے یا اس کے قدم کے قول کو۔
یا بعض اشیاء کے قدم اور بعض کے حدوث کا اور اگر یہ کہا جائے کہ ارادے کیساتھ مراد کی مقارنت جائز اور ممکن ہے اور اس سے اس کاتاخر بھی ممکن ہے تو اس تقدیر پر پورے عالم کا ایک ایسے ارادہ قدیمہ ازلیہ کے ذریعے حدوث ممکن ٹھہرے گا جس میں بالکل تجدد نہ ہو جس طرح کہ کلابیہ کا یہ قول ہے اور ان لوگوں کا جو ان کے موافق ہیں یعنی اشعریہ کرامیہ میں سے اور ان فقہاء میں سے جو ائمہ اربعہ کی طرف منسوب ہیں اور اس تقدیر پر تو حوادث کا حدوث بغیر کسی سببِ حادث کے ممکن ٹھہرا ؛ایسے ہی دو متماثلین میں سے ایک کا دوسرے پر محض ایک ارادہ قدیمہ کے ذریعے ترجیح لازم آئی اور اس تقدیر پر عالم کے قدم کے قائلین کی حجت باطل ہو گئی اور ان لوگوں نے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ یہ آثار میں تسلسل کے بطلان کا عقیدہ رکھتے ہیں اورایسے حوادث کے امتناع کا عقیدہ رکھتے ہیں جس کے لیے کوئی اول نہ ہو پس اگر ان کا یہ اعتقاد اور الزام حق ہے اور یہ کہ ایسے حوادث کا وجود ممتنع ہے جس کے لیے کوئی اول نہ ہو یعنی وہ ازلی ہوں تو ایسی صورت میں عالم کا حدوث لازم آئے گا اور قدم کا قول ممتنع ٹھہرے گا اس لیے کہ بے شک ان میں سے کوئی شے بھی حوادث کی مقارنت سے خالی نہیں ہوگی یہاں تک کہ عقول اور نفوس بھی ان لوگوں کے نزدیک جو اس کے اثبات کے قائل ہیں اسی لیے کہ یہ عقول اور نفوس کے قائلین کے نزدیک ان کا حوادث کے ساتھ مقارنت ضروری ہے پس ایسے حوادث کا وجود ممتنع ہے جو ازلی ہوں تو جو شے حوادث سے سابق نہیں ہے وہ اس کے بمنزلہ ٹھہرا پس اِس(مسبوق) کا قدم بھی ممتنع ہوا جس طرح کہ ُاس(سابق) کا قدم ممتنع ہے ۔
اگر ان لوگوں کایہ اعتقاد اور الزام باطل ہے تو پھر حوادث کا دوام ممکن ٹھہرا اور اس تقدیر پر مراد کا اپنے ارادے کے ساتھ مقارنت بھی ممکن ہوا اصل میں اور کسی بھی شے کا حدوث ممتنع ہوا الا یہ کہ کوئی سببِ حادث پایا جائے اور اسی صور ت میں عالم میں سے کسی بھی شے کاازلی ہونا ممتنع ٹھہرا ۔
اگر یہ بات ممکن مان لی جائے کہ صرف نوعِ حوادث کے لیے دوام ثابت ہے یعنی وہ ازلی ہیں تو بے شک ازل کسی شے معین سے عبارت نہیں بلکہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں جس کو فرض کر لیا جائے مگر یہ کہ اس سے پہلے ایک اور وقت پایا جاتا ہے پس نوع کے دوام سے کسی شے معین کا قدم لازم نہیں آتا
بے شک یہ کہا جاتاہے کہ کسی شے معین کا قدم ممتنع ہے اس لیے کہ جب ازل میں مراد کے ساتھ اس کی مقارنت ممکن اورجائز ہے تو یہ بات واجب ہے کہ وہ مراد کے ساتھ مقارن ہو اس لیے کہ وہ ارادہ جس کا اپنی مراد کے ساتھ مقارنت ممکن ہو اپنی مراد سے متخلف اور الگ نہیں ہوتا مگر قدرت میں کسی نقص اور کمی کی وجہ سے ورنہ تو اگر قدرتِ تامہ ہو اوروہ ارادہ جس کا اپنی مراد کے ساتھ مقارنت ممکن ہے وہ حاصل اور موجود ہو تو مراد کا حصول لازم ہے بوجہ اُس مقتضی کے پائے جانے کے جو فعل کے وجود کا تقاضا کرتا ہے اور وہ تام بھی ہے کیوں کہ اگر یہ بات لازم نہ ہو باوجود یکہ مراد ممکن ہے تو پھر اس کے بعد اس کے حصول سے یہ لازم آئے گا کہ دونوں متماثلین میں سے ایک کو دوسرے پر بغیر کسی مرجح کے ترجیح دے دی جائے اور اس تقدیر پر یہ امرباطل ہے اس لیے وہ لوگ جو ازل میں حوادث میں سے کسی معین حادث کے امتناع کے قائل ہیں (یعنی کسی ایسے خاص ممکن کا وجود نہیں ہے جو ازل میں پایا جاتا ہو )وہ یہ کہتے ہیں کہ ارادے میں سے کسی شے کا حصول ازل میں ممتنع ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ممکن ہے اور یہ کہ اس ارادے کا اپنے مراد کے ساتھ مقارنت ممکن ہے لیکن لوگوں نے ان پر یہ اشکالات وارد کئے ہیں :
جب تمام اوقات اور حوادث کی ارادہ ازلیہ کی طرف نسبت ایک ہی ہے تو دو وقتوں میں سے ایک کو ترجیح دینا ترجیح بلا مرجح ہے اور دو متماثلین میں سے ایک کو بغیر کسی مخصص کے خاص کر دینا ہے اور یہ کلام اس مقام پر ہمارے مقصود میں کوئی قادح نہیں ہے اس لیے کہ ہم اس قول کا دفاع نہیں کرتے لیکن ہم نے ہر تقدیر پر عالم میں سے کسی شے معین کے قدم کے امتناع کو واضح طور پر بیان کر دیا اور اس بات کو بھی کہ حوادث کا دوام خواہ ممکن مان لیا جائے یا ممتنع پس بے شک دونوں تقدیرین پر عالم میں سے ہر شے کا حدوث یہ واجب ہے اوریہ کہ ارادہ خواہ اس کا اپنی مراد کے ساتھ مقارنت کا قول اختیار کیا جائے یا اس کا اس سے تاخر کے امکان کا قول ہر تقدیر پر عالم میں سے ہر ہر شے کا حدوث لازم آئے گا اس لیے کہ جو لوگ ارادے سے اس کی مراد کے تاخر کے قائل ہیں انہوں نے یہ قول ،حوادث کے دوام اور حوادثِ ازلیہ کے وجود کے قول سے فرار کے لیے اختیار کیا ہے اور اس تقدیر پر حدوث عالم لازم آتا ہے ورنہ اگر حوادث کا دوام ممکن ٹھہرے تو ان کے نزدیک ازل میں مراد کا وجود بھی ممکن ٹھہرے گا اور اگر یہ بات ممکن ہوتی تو ارادہ قدیمہ ازلیہ سے مراد کے تاخر کا قول نہ اختیار کرتے باوجود یکہ اس میں وہ خرابی پائی جاتی ہے جو ہم نے بیان کر دی یعنی دو متماثلین میں سے کسی ایک کو بغیر کسی مرجح کے دوسرے کو ترجیح دینا۔
ایسے ہی اس میں عقلی طور پر جوشناعت اور قباحت بھی پائی جاتی ہے اور یہ بھی کہ یہ اس بات کو متضمن ہے کہ عقلاء میں سے ایک جمِ غفیر کی اس بات کی طرف نسبت کی جائے کہ انہوں نے صریح معقول کی مخالفت کر لی اس لیے انہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے بوجہ اس کے کہ ان کا اس بات پراعتقاد ہے کہ حوادثِ ازلیہ ممکن ہیں پس وہ اس بات کی طرف محتاج ہوئے کہ وہ ایک ارادہ قدیم ازلی کو ثابت کریں ایسا ارادہ جس سے اس کا مراد متاخر ہو اور اس کے بعد بغیر کسی سببِ حادث کے وہ حادث ہو اور وہ اس بات کے محتاج ہوئے کہ وہ یہ کہیں کہ ’’نفسِ ارادہ دو متماثلین میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے ورنہ اگر وہ حوادث کے دوام کو جائز اور ممکن سمجھے اور ان کے تسلسل کا اعتقادرکھے تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہ یہ بھی کہیں کہ ارادات اور مرادات حادث ہوں اور وہ یہ بھی کہیں کہ قدیم ذات کے ساتھ حوادث کا قیام بھی ممکن ہو اور وہ اپنے اس قول سے رجوع اختیار کر لیں کہ نفسِ ارادہ قدیمہ دو مثلین میں سے ایک کو دوسرے پر مستقبل میں ترجیح دیتا ہے اور اپنے اس قول سے (بھی رجوع کرلیں )کہ ایسے حوادث کا حدوث ممکن ہے جن کے لیے کوئی سببِ حادث نہ ہو اور وہ اس تقدیر پر عالم میں سے کسی شے کے قدم کے قائل نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ماسوا سب کے سب حادث اور موجود ہیں بعد اس کے کہ وہ نہیں تھے اور یہ اسی تقدیر پر لازم آتا ہے اس لیے ایسی صورت میں جب حوادث میں سے کوئی بھی شے اس کا حدوث جائز او رممکن نہیں ہے مگر کسی سببِ حادث کے ذریعے اور کسی شے کے حدوث کے ساتھ دو وقتوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح کسی ایسے مرجح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جو اس کا تقاضا کرتا ہے پس مراد کا اپنے ارادے سے تاخر نہیں ہوگا مگر مراد کے مقارنت کے متعذرہونے کی وجہ سے ،اس لیے کہ اگر اگر مراد کا اپنے ارادے کے ساتھ اس کی مقارنت ممکن ہو اور یہ بات بھی ممکن ہو کہ و ہ اس سے متاخر ہے تو پھر دو زمانوں میں سے ایک کا احداث کے ساتھ تخصیص بلا مخصص اور ترجیح بلا مرجح ہوگا پس یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس تقدیر پر دو باتوں میں سے ایک بات لازم آتی ہے یا تو مراد کا اردے کے ساتھ مقارنت کا وجود یا اس کا امتناع اور یہ بھی کہ اس کا ارادے کے ساتھ مقارنت واجب ہے جبکہ وہ ممکن ہو اور یہ بھی کہ وہ اس سے متاخر نہ ہو مگر اس صورت میں کہ اس کی مقارنت متعذر اور دشوار ہو یا بذاتِ خود اس کے ممتنع ہونے کی وجہ سے اور اس کے لوازم کے امتناع کی وجہ سے اور لازم کا امتناع ملزوم کے امتناع کا تقاضا کرتا ہے لیکن اس کی امتناع غیر کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ اس کی ذات کی وجہ سے جس طرح کہ مسلمان یہ کہتے ہیں : ’’ماشاء اللّٰہ کان وما لم یشأ لم یکن۔‘‘
پس جس چیزکو اللہ چاہیں تو اس کی مشیت سے اس کا موجود ہونا واجب ہے نہ کہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے اور جس کو اللہ نہ چاہیں تو اس کا کون اور اس کا وجود ممتنع ہے نہ کہ اس کی اپنی ذا ت کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ تب ہی موجود ہوتا جب اللہ چاہیں پس جو اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں چاہا تو اس کا کون اور وجود ممتنع ہوا اور جب اس تقدیر پر دو باتوں میں سے کوئی ایک بات لازم ہے ۔
(۱)یا تو مراد کا ارادے کے ساتھ مقارنت (۲)یا اس کا اپنی ذات کی وجہ سے امتناع تو اس سے اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ اگر عالم میں سے کوئی شے کسی شے کا قدیم ہونا ممکن ہوتا تو یہ بات واجب ہوتی کہ اس کا کہ وہ قدیم ہوتا اس کے ازل میں اس کے ساتھ مقارنت کے وجود کی وجہ سے کیوں کہ یہ بات مفروض ہے کہ مقارنت کا وجود یا مراد کا امتناع یہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ضروری ہے پس جب مراد ازل میں ممکن ہے تو مقارنت بھی اس کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے لیکن مقارنت کا وجود تو ممتنع ثابت ہوا لاس لیے کہ یہ تو اس بات کو مستلزم ہے کہ حوادث میں سے کوئی بھی حادث نہ ہو جس طرح کہ ماقبل میں گزرا پس اس میں آخری یعنی دوسری صورت ہی لازم آئی اور وہ ازل میں کسی مرادِ معین کا امتناع کا ثبوت ہے اور یہی ہمارا مطلوب ہے رہا یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ ارادے سے اس کی مراد کا تاخر واجب اورضروری ہے جس طرح کہ اہل کلام میں سے بہت سے اس کے قائل ہیں تو اس کی مرید ہونے یعنی ارادہ کرنے والی ذات ہونے کی تقدیر پر عالم میں سے کسی شے کا قدم ثابت ہونا ممتنع ہوا اور یہی ہمارا مطلوب ہے ۔
پس واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تمام اشیاء کا حدوث ہر تقدیر پر ثابت ہوا اور یہی مطلوب ہے جان لو ! جس نے اس طریقے کو سمجھ لیا تو اس نے ان سے کئی امور کا استفادہ کر لیا یعنی کئی مور کو سمجھ لیا :
۱:اللہ کی ذات کے علاوہ تمام اشیاء کے حدوث کا ثبوت چنانچہ کہ اگر یہ بات فرض کر لی جائے کہ اجسام کے علاوہ بھی کوئی اور موجود چیز (اس عالم میں )ہے اس عالم میں جس طرح کہ وہ لوگ اس کے قائل ہیں جوعقول اور نفوس کو ثابت کرتے ہیں یعنی فلاسفہ اور متکلمین اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایسے جواہر ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہیں اور یہ اجسام نہیں ہیں ،اس طریقہ کے ذریعے ان اشیاء کا حدوث بھی معلوم ہو جاتا ہے ۔
متاخرین اہل کلام میں سے ایک جماعت کا خیال بھی یہی ہے جیسے شہرستانی، امام رازی ،آمدی اور ان کے علاوہ دیگر ،چنانچہ انہوں نے کہا کہ اہلِ کلام میں سے قدماء نے اس بات کی نفی پر کوئی دلیل قائم نہیں کی اور اجسام کے حدوث پر ان کی دلیل اس کو شامل نہیں اور اس مقام کے علاوہ ایک اور جگہ میں اس بات کو مفصلاً بیان کیا گیا ہے کہ یہ اہل نظر جیسے کہ ابو الہذیل علاف اور اس طرح نظام اور ہشام اور ابن کلاب ،ابن کلام اشعری ،قاضی ابوبکر ،ابو المعالی اور ابو علی اور ابو ہاشم اور ابو الحسن بصری ،ابو بکر ابن العربی ،ابو التمیمی ،قاضی ابو الاعلی ،ابو الحسن ابن الزاغونی اور ان کے علاوہ دیگر ۔
یہ سب ایک ایسے موجود کے وجود کاامتناع ثابت کرتے ہیں جو ممکن ہو ،قائم بنفسہ ہو ،اس کی طرف اشارہ نہ کیا جا سکے ،پس انہوں نے خارج میں ایسے مجردات کے وجود کے بطلان کو ثابت کیا ہے لیکن ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے ایسے اشیاء کے ثبوت کو باطل قرار دیا ہے جن کی طرف اشارہ نہ کیا جا سکے (یعنی اشارہ حسیہ کیساتھ وہ مشار الیہ نہ بن سکیں ) اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہو ں نے ممکنات میں اسے باطل قرار دیا ہے اور یہ جو طریقہ ہم نے بیان کر دیا اس کے ذریعے اس قول سے خلاصی حاصل ہوتی ہے جو بغیر کسی سببِ حادث کے حوادث کے پیدا ہونے کا (قول )ہے ۔
اس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ جو صفات اور افعال قائم ہیں ان کی نفی سے خلاصی اور نجات بھی ثابت ہوتی ہے ،اسی طرح اس سے یہ امربھی مستفاد ہوتا ہے کہ یہ قدمِ عالم کے قائلین کے قول کے ابطال پر ایک واضح اور غالب دلیل ہے یا عالم میں سے بعض اشیاء کے کسی خاص چیز کے قدم کے بطلان پر بھی اور یہ ان کے بڑے ادلہ (معتبر ادلہ )سے جواب کو بھی متضمن ہے ۔
جو بات اس سے مزیدمستفاد ہوتی ہے وہ مطلوب کا استدلال ہے بغیر اس کے کہ موجب بالذت اور فاعل بالاختیار کے فرق کی طرف حاجت پیش آئے اور یہ اس لیے کہ اہل نظر میں سے بہت سے لوگوں نے ان دونوں کے درمیان فرق کرنے میں غلطی کی ہے جو کہ معتزلہ اور شیعہ میں سے ہیں اور بہت سے لوگ جیسے کہ امام رازی اور اس کے امثال ،وہ اس مقام پر مضطرب اور پریشا ن نظر آتے ہیں کبھی تو وہ فرق کے اثبات پر معتزلہ کی موفقت کرتے ہیں اور کبھی ان کی مخالفت کرتے ہیں اور جب ان کی مخالفت کرتے ہیں تو پھروہ اہل سنت اور فلاسفہ جو کہ ارسطوکے اتباع ہیں ان کے درمیان متردد ہیں ۔
اس بات کی بنیاد اس پر ہے کہ ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ذات جو قادر ِ مختار ہے ،اپنی مشیت اور قدرت کے ساتھ افعال صادر کرتا ہے لیکن کیا اُس کے ارادہ جازمہ یا قدرتِ تامہ کے وجود کے ساتھ مفعول کا وجود واجب ہے یا نہیں ؟پس اہل سنت میں سے جمہور جو کہ قدر کے مثبتین ہیں ان کا مذہب اور ان کے علاوہ جو قدر کے نفی کرنے والے ہیں ان کا مذہب بھی یہ ہے کہ ایسے مقتضی تام کے وجود کے وقت جو کہ ایک ایسے ارادہ جازمہ اور قدرتِ تامہ سے عبارت ہے جس کے (وجود میں آنے کے )وقت مفعول کا وجود واجب ہے اور قدرکے مثبتین میں سے ایک دوسرا گروہ یعنی جہمیہ اور ان کے موافقین اور قدرکی نفی کرنے والوں میں سے یعنی معتزلہ اور ان کے علاوہ دیگر طوائف اس بات کو واجب اور ضروری نہیں سمجھتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قادر تو وہی ذات ہے جو جواز اور امکان کے طریقے پر فعل کرتا ہے نہ کہ وجوب کے طریقے پر اور وہ اسی کو اِس کے اور موجب بالذات کے درمیان فرق قرار دیتے ہیں ۔
یہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قادرِ مختار اپنے دو مقدورین میں سے ایک کو دوسرے پر بغیر کسی مرجح کے ترجیح دے سکتا ہے جس طرح کہ روٹیوں کے ساتھ کسی بھوکے کا حال ہے ،دو راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلنے والے کا حال ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بغیر مرجح کے ترجیح دیتا ہے پس ان لوگوں میں سے قدریہ تو یہ کہتے ہیں کہ بندہ قادر ہے اور اپنے دو مقدورین میں سے ایک کو بغیر کسی مرجح کے ترجیح دیتا ہے جس طرح کہ وہ اس جیسی بات رب تعالیٰ کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان قدریہ کے اقوال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل طاعت پر کوئی ایسے انعامات نہیں کئے جن کیساتھ اُن کو خاص کیا ہے جس کی وجہ سے انہون نے ا سکی اطاعت کی بلکہ اس کا مطیع اور غیر مطیع کو قدرت دینا برابر ہے لیکن اِس ایک نے بغیر کسی مرجح کے اُس کی اطاعت کرنے کو ترجیح دی ہے بلکہ محض اپنی قدرت کی وجہ سے بغیر کسی سبب کے اور دوسرے نے معصیت کو راجح قرار دیا محض قدرت کی وجہ سے بغیر کسی ایسے سبب کے پائے جانے کے جو اس کا موجب ہو ۔
رہے جبریہ جیسے کہ جہم بن صفوان اور اس کے اصحاب ہیں ؛تو ان کے نزدیک تو بندے کے لیے اصلا کوئی قدرت ہی ثابت نہیں اور اشعری معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ان کے موافق ہیں ،پس وہ یہ کہتا ہے کہ بندے کے لیے کوئی قدرت ثابت نہیں اور وہ ایک ایسی شے کو ثابت کرتا ہے جس کو وہ ’’قدرت ‘‘کا نام دیتا ہے اور جس کے وجود کو وہ عدم کے مساوی اور برابر قرار دیتا ہے اسی طرح وہ کسب جس کو وہ ثابت کرتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ بات ممکن نہیں کہ وہ قدریہ کے قول کابطلان اس بات سے ثابت کریں کہ بندے کی فاعلیت (کسی کام کو جوددینا)کا اس کے تارکیت (فعل نہ کرنا )پر جو رجحان ہے اس کے لیے کسی مرجح کا ہونا ضروری ہے جس طرح کہ امام رازی اور جبریہ میں سے ایک گروہ اس طرح کرتے ہیں اور اسی وجہ سے تو اشعری اور اس کے قدمائے اور اصحاب نے اس حجت کو ذکر نہیں کیا اور لوگوں میں سے ایک گروہ جیسے امام رازی اور اس کے اتباع (پیروکار)ہیں جب انہوں نے معتزلہ کے ساتھ قدر کے مسائل میں مناظرہ اور بحث و تمحیص کی تو انہوں نے اس اصل اور بنیاد کو باطل کر دیا اور انہوں نے واضح طور پر یہ بنیاد بیان کر دیا کہ فعل کا وجود کسی مرجح تام کے وجود کے وقت واجب ہے اور یہ کہ اس کا فعل بغیر کسی مرجح تام کے (صادر ہونا )ممتنع ہے اور انہوں نے اس بات پر دلائل قائم کئے اور اِس کا دفاع کیا کہ قادرِ مختار ذات اپنے دو مقدورین میں سے ایک کو دوسرے پر بغیر کسی مرجح تام کے ترجیح نہیں دیتا اور جب حدوثِ عالم اور فاعلِ مختار کے اس مسئلے میں انہوں نے فلاسفہ کے ساتھ مناظرہ اور بحث کی اور اس طرح موجب بالذات کے قول کے ابطال کے بارے میں تو وہ اس قول کو اختیار کرنے میں معتزلہ اور جہمیہ کے طریقے پر چلے کہ قادرِ مختارذات اپنے دو مقدورین میں سے کسی ایک کو بغیر مرجح کے ترجیح دیتا ہے اور وہ اکثر لوگ جو ابو عبد اللہ ابن الخطیب اور ان کے امثال کے طریقے پر چلے ہیں توتو ان کو پائے گا کہ وہ اس تناقض میں پڑ جاتے ہیں اور واضح اور فیصلہ کن بات تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ موجب بالذات کے لفظ سے کیا مراد ہے ؟
اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ وہ ایک ایسی ذات کے ذریعے موجب ہے جو کہ مشیت اور قدرت سے مجرد اور خالی ہے تو ایسی ذات کے لیے کوئی حقیقت اور خارج میں کوئی ثبوت نہیں چہ جائے کہ وہ موجب بنے اورفلاسفہ کا قول تو تناقض پر مشتمل ہے اس لیے کہ وہ اول کے لیے ایک غایت اور انتہا ثابت کرتے ہیں اور عللِ غائیہ کو بھی ثابت کرتے ہیں اور یہ ارادے کو مستلزم ہے اور جب وہ غایت کی تفصیل محض علم سے کرتے ہیں اور علم کو محض ذات قرار دیتے ہیں تو یہ انتہائی درجے کا فساد اور تناقض ہوا اس لیے کہ ہم یقین سے اس بات کو جانتے ہیں اور بداہت کے ساتھ کہ ارادہ محض علم کا نام نہیں اور یہ بات بھی کہ علم محض عالم نہیں لیکن یہ اس باب میں فلاسفہ کے تناقض میں سے ہے اس لیے کہ وہ معانی متعددہ اور مختلفہ کو ایک ہی قرار دیتے ہیں پس وہ علم کو قدرت ہی کا مصداق بنا دیتے ہیں حالانکہ وہ ارادہ ہے اور وہ صفت کو نفسِ موصوف قرار دیتے ہیں جس طرح کہ وہ علم کا مصداق نفسِ عالم ٹھہراتے ہیں اور قادر بعینہ قدرت کو اور ارادہ بعینہ مرید کو یعنی ارادہ کرنے والے کو اور عشق ذاتِ عاشق کو قرار دیتے ہیں اور اس بات کی ان کے فضلاء نے تشریح کی ہے اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو ان کی دفاع کرنے والے ہیں جیسے ابن رشد جس نے ابن حامدِ غزالی پر تھاف التھافت میں رد کیا ہے اور اس کے امثال اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر مشیت اور اختیار سے خالی کسی ذات کے وجود کو فرض کر لیا جائے تو اس تفسیر پریہ ممتنع ہو گاکہ عالم کسی موجب بالذات سے صادر ہو ا س لیے کہ اس اعتبار پرموجب بالذات اپنے موجب اور مقتضی کے ساتھ مستلزم ہوا پس اگر عالم کا مبدأ موجب بالذات ہو تواس تفسیر پر لازم آیا کہ عالم میں سے کوئی بھی شے حادث اور پیدا نہ ہو حالانکہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے پس ان کا موجب بالذات کا یہ قول اللہ کی صفات اور اس کے افعال کی نفی کو اور عالم میں سے کسی شے کے حدوث کی نفی کو مستلزم ہے اور یہ تمام امور معلوم البطلان ہیں ۔
اس سے بھی زیادہ باطل امریہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک واحدِ بسیط قراردیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی ذات سے صرف ایک ہی امر صادر ہو سکتا ہے اور پھر امو ر کثیر ہ کے صدور کے لیے انہوں نے کئی حیلے اختیار کئے جو کہ ان کے تحیر اور حیرانگی پر دلالت کرتے ہیں اور ان کی جہل کی علامت ہیں مثلاً اُن کا یہ کہنا کہ صادرِ اول وہ عقلِ اول ہے اور وہی موجود ہے اور واجب بغیرہ ہے ممکن بنفسہ ہے پس اس ایک عقلِ اول میں تین جہتیں ثابت ہوئے :
پس اس کی ذات سے اس کے وجوب کے اعتبار سے عقلِ آخر ثابت ہوا اور اسکی وجود کے اعتبار سے ایک نفس اور اس کے امکان کے اعتبار سے فلک۔
بسا اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے وجود کے اعتبار سے صورتِ فلک اور اس کے امکان کے اعتبار سے اس کا مادہ اور نفسِ فلکیہ تو نفسِ فلکیہ یعنی فلک کے ذات کے بارے میں بھی ان کا نزاع ہے کہ کیا وہ ایک ایسا جوہر ہے جو اس سے مفارق اور جدا ہے؟ یا ایک ایسا عرض ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے ؟اسی وجہ سے ان کے کلام کے فساد کو بیان کرنے میں لوگوں نے بہت تفصیلات ذکر کی ہیں اور یہ اس لیے کہ یہ واحد ذات جس کو انہوں نے فرض کر لیا ہے اس کا وجود متصور نہیں مگر صرف اذہان میں اور پھر ان کا یہ کہنا کہ واحد سے صرف اور صرف واحد ہی صادر ہو سکتا ہے یہ قضیہ کلیہ ہے اور اگر وہ بعض صورتوں میں اس کے ثبوت کو جانتے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ بھی کلیہ ہو مگر کسی قیاسِ تمثیل کے ساتھ پس کیا حال ہو گا اس کے بطلان کا حالانکہ وہ کسی ایسے فرد کو یقین کے ساتھ نہیں جانتے یعنی ان کو نہیں معلوم کہ جس سے کوئی شے صادر ہو ۔
وہ مثال جو وہ بیان کرتے ہیں یعنی آگ سے گرم ہونے کا صدور اور پانی سے ٹھنڈ ا کرنے کا صدور ،یہ مثال باطل ہے اس لیے کہ یہ آثار دو الگ الگ چیزوں سے صادر ہوتے ہیں ایک فاعل ہے یعنی اثر کرنے والا اورایک قابل یعنی اثر قبول کرنے والا اور اولِ حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کی ذات کے علاوہ جتنے ماسوا ہیں وہ سب اس سے صادر ہیں وہاں وہ قادر اور موجود ہی نہیں اور اگر وہ یہ کہیں کہ خارج میں وہ ماہیاتِ ثابتہ جوفاعل سے غنی بے نیاز ہیں وہ بھی قبول کرنے والے ہیں تو یہ تین وجوہ سے باطل ہے :
۱) ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بات ان کے اصلِ فاسد پر مبنی ہے اور وہ خارج کے اندر ایسے ماہیاتِ موجودہ کا اثبات ہے جو اعیانِ موجودہ کے مغایر ہوں اور یہ قطعا باطل ہے اور جو بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ مثلث کا وجود معلوم ہونے سے پہلے وہ خارج میں مثلث کے ثبوت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ صرف ذہن میں اس کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو اشیاء اذہان میں حاضر ہوتی ہیں اور جو اعیان ،مشاہدہ اور حس میں ہوتی ہیں ان دونوں کے درمیان فرق ہے تو یہیں سے یہ بہت بڑی غلطی میں پڑ گئے اس لیے کہ انہوں نے ذہنوں میں بہت سے امور کا تصور کر لیا پس انہوں نے اعیا ن کے اندر بھی اس کے ثبوت کا گمان کر لیا جیسے کہ عقول اور ماہیاتِ کلیہ ہیں اور حیلولت اور اس کے امثال ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماہیات کا اعتبار ان کے وجود کے اعتبار سے ہے پس جو بھی شے وجود میں آتی ہے تو اس کے لیے ان کے ہاں ایک ماہیت ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی کہنے والا اس بات کا قائل ہے کہ معدوم بھی کوئی شے ہے یعنی معتزلہ اور روافض میں سے بعض کی رائے یہ ہے پس صرف اس توہم کی بنا پر چند امور پرموجودات کو محدود کرنا جائز نہ ہوا کہ ان کے علاوہ کوئی ایسی ماہیت نہیں پائی جاتی جو وجود کو قبول کرے ۔
ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کہا جائے کہ ماہیاتِ ممکنہ فی نفسہا کے لیے کوئی انتہا نہیں یعنی وہ لامحدود ہیں نیز ان میں سے یہ بھی ہیں کہ یہ کہا جائے کہ وہ فردِ واحد جو مشاہدہ میں نظر آتا ہے اورر جس سے اس کے آثار صادر ہوتے ہیں ا س کے بھی قوابلِ موجود ہیں اور باری تعالیٰ تو اپنی ذات کے ماسوا تمام اشیاء کے وجود کے لیے مبدع (از سر نو پیدا کرنے والے )ہوتے ہیں تو ایسا کوئی امر معلوم نہیں جو کسی ممکن سے (اکیلے )صادر ہو مگر دو سے زیادہ اشیاء سے ،باوجود یکہ بسا اوقات وہاں پر کوئی ایسا معنی پایا جائے جو تاثیر کو روکتا ہے اور موجودات میں اور ایسی کوئی شے نہیں جو اکیلے اس کی ذات سے صادر ہوں سوائے اللہ تعالیٰ کے ۔