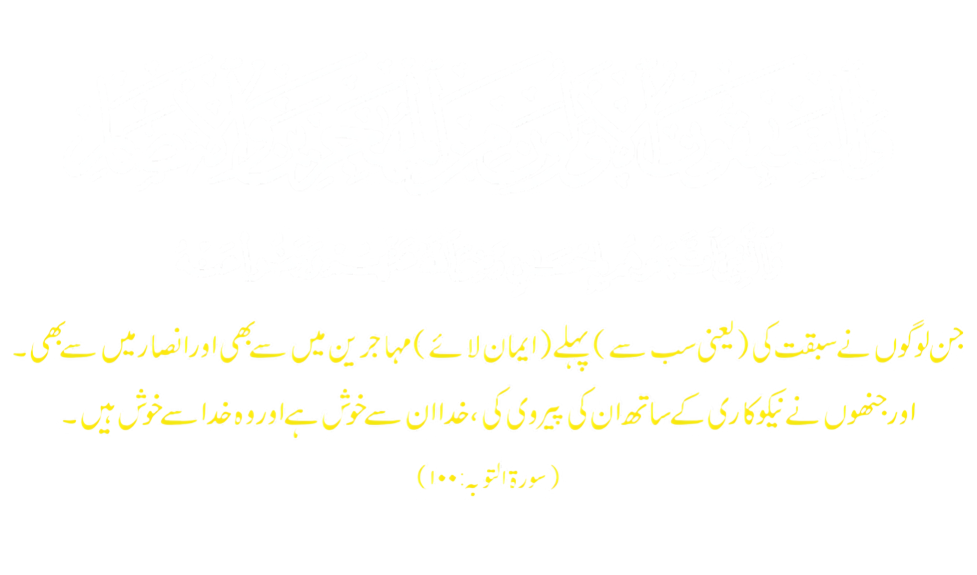فصل: ....میراث حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ
امام ابنِ تیمیہؒفصل: ....میراث حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ
[سلسلہ اعتراضات]: [پہلا اعتراض]: شیعہ مصنف لکھتا ہے: ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاورثہ دینے سے انکار کر دیا۔تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں :
اے ابو قحافہ کے بیٹے ! کیا تم اپنے باپ کے وارث بن سکتے ہو اور میں اپنے باپ کی وارث نہیں بن سکتی؟ اور ایک منفرد روایت سے احتجاج کیا۔۔اور آپ[ابو بکر رضی اللہ عنہ ] پران کا قرض تھا؛ آپ کے لیے صدقہ حلال تھا ۔اور اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’ ہم انبیاء کی جماعت ہیں ۔ہم وراثت نہیں چھوڑتے ؛ جو کچھ ہم اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ۔‘‘حالانکہ اس بارے میں جو کچھ آپ سے روایت کیا گیا ہے قرآن ا س کے خلاف کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿یُوْصِیْکُمُ اللّٰہُ فِیْٓ اَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ﴾ [النساء۱۱]
’’اللہ تمہاری اولاد کی بابت تم کو وصیت فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے ۔‘‘
اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صرف امت کے ساتھ خاص نہیں کیا ۔بلکہ ان کی روایات کو جھٹلایا ہے۔ جیسا کہ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل ۱۶]’’ اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے ۔‘‘
حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿وَ اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّ رَآئِ یْ وَ کَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا فَہَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّاo یَّرِثُنِیْ وَ یَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ﴾ [مریم۵۔۶]
’’ اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ جو میری اولاد اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو۔‘‘[انتہی کلام الرافضی]
[جوابات]: اس کا جواب کئی طرح سے دیا جاسکتا ہے :
پہلا جواب :....شیعہ نے جو قول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: کیا تم اپنے باپ کے وارث بن سکتے ہواور میں اپنے والد کی وارث نہیں بن سکتی؟ اس قول کی صحت کا کوئی علم نہیں ہوسکا۔ اگریہ قول صحیح ثابت بھی ہوجائے تو اس میں رافضی کے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد ِ محترم کو کائنات بھر کے کسی فرد و بشر پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اور ابو بکر مؤمنین کو ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز نہیں ہوسکتے۔ جیسا کہ آپ کے والد محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔اور نہ ہی آپ کاشمار ان لوگوں میں ہوتاہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نفلی یا فرض صدقہ کو حرام کیا ہے جیسے آپ کے والد محترم پر تھا۔ اور نہ ہی آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ اپنی جان و مال اور اہل خانہ کی محبت سے مقدم کرنے کا حکم دیا ہے؛ جیساکہ آپ کے والد محترم کے لیے یہ حکم تھا۔ [اگر رسول اﷲ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترکہ چھوڑا تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کی تنہا وارث نہ تھیں ، بلکہ آپ کی ازواج مطہرات اس میں برابر کی شریک تھیں ۔مزید یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما اس ضمن میں سرفہرست تھیں جن کے گھر میں آپ نے وفات پائی اور وہیں دفن کیے گئے،حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما بھی برابر کی وارث تھیں ۔ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ورثہ نہ پاسکیں تو آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے چچا عباس بھی ورثہ سے محروم رہے ، مگر شیعہ سیدہ فاطمہ کے سوا دیگر اقارب کاذکر تک نہیں کرتے۔ علاوہ ازیں باغ فدک اور خیبر کا خمس اہل بیت کے لیے مباح تھا اور وہ ان سے اپنی ضروریات اسی طرح پوری کرتے تھے جس طرح آپ کی زندگی میں ، جو بچ جاتا وہ ان مصارف میں صرف کیا جاتا، جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔]
انبیائے کرام علیہم السلام اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے وارث بننے سے پاک رکھا ہے۔ تاکہ ان لوگوں کے لیے شبہ کی گنجائش نہ رہے جو کہتے ہیں :
’’انبیاء کرام علیہم السلام نے دنیا اس لیے طلب کی تھی کہ اسے اپنے بعد اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جائیں ۔‘‘
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے امثال کو وہ مقام نبوت حاصل نہیں ہے جس پر قدح کا اندیشہ نہ ہو۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خط و کتابت ؛ شعر گوئی وغیرہ سے محفوظ رکھا تھا تاکہ نبوت پر کوئی شبہ واقع نہ ہو۔اگرچہ کسی دوسرے کے لیے اس حفاظت میں کوئی حجت نہیں ہے۔
دوسرا جواب :....ہم کہتے ہیں : شیعہ مصنف کا اس کو منفرد روایت قرار دینا صاف جھوٹ ہے۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان :’ہم وراثت نہیں چھوڑتے ؛ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ۔‘‘[صحیح بخاری ؛کتاب: وصیتوں کے مسائل کا بیان ؛ باب : وقف کی جائیداد کا اہتمام کرنے والا اپنا خرچ اس میں سے لے سکتا ہے ۔ح نمبر: 2776؛ یہ پوری روایت اس طرح ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:’’ جو آدمی میرے وارث ہیں ؛ وہ اشرفی اگر میں چھوڑ جاؤں تو وہ تقسیم نہ کریں وہ میری بیویوں کا خرچ اور جائیداد کا اہتمام کرنے والے کا خرچ نکالنے کے بعد صدقہ ہے۔‘‘اس کے علاوہ یہ روایت مختلف الفاظ سے ان کتابوں میں موجود ہے: البخاری ؍ ۸۹ ؛ کتاب المغازی ؛ باب غزوۃ خیبر ۔ مسلم ۳؍ ۱۳۷۶ ؛ کتاب الجہاد و السیر ؛ باب حکم الفیء ؛سنن ابی داؤد ۳؍۱۹۲ ؛ کتاب الخراج الإمارۃ و الفیء ؛ باب في صفایا رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ؛ سنن الترمذی ۳؍ ۸۱ ؛ کتاب السیر ؛ باب ما جاء فی ترکۃ النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم ۔]
یہ حدیث خلفاء اربعہ ، حضرت طلحہ، زبیر، سعید، عبدالرحمن بن عوف، عباس، ابوہریرہ(رضی اللہ عنہم ) اور آپ کی ازواج مطہرات (رضی اللہ عنہم )نے روایت کی ہے۔ان لوگوں سے یہ روایت مسانید ‘ صحاح ؛ اور دوسری مشہور کتب احادیث میں موجود ہے؛جسے محدثین کرام اچھی طرح جانتے ہیں ۔ اب رافضی کا اس روایت کو منفرد کہنا اس کی انتہائی جہالت یا جان بوجھ کر جھوٹ بولنے پر دلالت کرتا ہے۔
تیسرا جواب :....شیعہ مصنف کا یہ قول کہ:’’ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مقروض تھے‘‘ صریح کذب ہے۔ کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ کے دعویٰ دار نہ تھے؛ اور نہ ہی اس مال کو اپنے اہل خانہ کے لیے روکنا چاہتے تھے۔ بلکہ آپ کا ترک کردہ مال صدقہ تھا اور وہ ان کو ملنا چاہیے تھاجو اس کے مستحق ہیں ۔ جیسا کہ مسجد مسلمانوں کا حق ہے۔اور عدل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے پرگواہی دے کہ اس نے اپنے گھر کو مسجد کے لیے وقف کرنے کی وصیت کی تھی یااپنے پانی کے کنوئیں کو عام گھاٹ بنانے یا پھر اپنی زمین کو قبرستان بنانے کی وصیت کی تھی۔ تو ایسی گواہی باتفاق مسلمین جائز ہے۔ اس کنوئیں سے پانی پیاجائے گا؛ اور اس زمین میں مردوں کو دفن کیا جائے گا۔اس لیے کہ یہ گواہی عوام کی طرف سے غیر محصور ہے ۔ اور گواہ بھی اس عموم کے حکم میں داخل ہے ۔ اس کے متعین ہونے کے لیے کسی خاص حکم کی کوئی ضرورت نہیں ۔ایسے معاملات میں کوئی فریق مخالف[خصوم] نہیں ہوتا۔
ایسے ہی کسی مسلمان کی بیت المال کے لیے گواہی کا مسئلہ ہے۔مثال کے طور پر کوئی گواہی دے کہ فلاں انسان کے پاس بیت المال کا کوئی حق ہے ؛ اور یہ گواہی دینا کہ فلاں انسان کا بیت المال کے علاوہ کوئی وارث نہیں ؛ اور ذمی پر گواہی دینا کہ اس نے عہد ذمہ توڑ دیا تھا ؛ اور اب اس کا مال مالِ فئے کے طور پر بیت المال میں داخل ہوگا؛وغیرہ ۔
اگر کوئی انسان گواہی دے کہ فلاں انسان نے اپنا مال فقراء اورمساکین پر وقف کردیا تھا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اگرچہ گواہی دینے والا کوئی فقیر انسان ہی کیوں نہ ہو۔
چوتھا جواب :....حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس صدقہ کے مستحق نہ تھے۔ بلکہ وہ ایسی چیزوں سے بے نیاز انسان تھے۔ اور نہ ہی آپ نے خود اور نہ ہی آپ کے اہل خانہ نے اس صدقہ سے کسی قسم کا فائدہ اٹھایا۔ آپ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مالدار لوگوں کی ایک جماعت کسی انسان کے متعلق گواہی دے کہ اس نے اپنا مال فقراء کے لیے صدقہ کرنے کی وصیت کردی تھی تو ان لوگوں کی گواہی بالاتفاق مقبول ہوگی۔
پانچواں جواب :....یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کا فائدہ یہ حدیث روایت کرنے والے صحابہ کو بھی حاصل ہوتا ہو تو تب بھی ان کی روایت قبول کی جاتی ۔ اس لیے کہ اس کا شمار روایت کے باب میں ہوتا ہے گواہی کے باب میں نہیں ۔اسی لیے جب محدث کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس میں اس کے اورفریق مخالف کے درمیان فیصلہ کن حکم موجود ہو تو اس کی روایت حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے کہ روایت کا حکم عام ہے اس میں راوی اور دوسرے لوگ برابر کے شریک ہوتے ہیں ۔ اس کا تعلق خبر کے باب سے ہے۔ جیسے کہ چاند دیکھنے کی گواہی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوحکم بیان کیا ہے وہ راوی اور دوسرے لوگوں کے لیے عام ہے ۔ ایسے ہی جس چیز سے آپ نے منع کیا ہو‘ یا جس چیز کو مباح قرار دیا ہو۔ یہ حدیث بھی ایک شرعی حکم کی روایت کو متضمن ہے۔ اسی وجہ سے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی میراث کی حرمت کو شامل ہے ۔اور یہ میراث کی اشیاء کو آپ کے ورثہ سے خریدنے کی حرمت کو بھی متضمن ہے۔اور اس حدیث میں اس مال کو صدقات کے مصاریف میں خرچ کرنے کے وجوب کا حکم بھی ہے ۔
آیات میراث پر بحث:
چھٹا جواب :....شیعہ مصنف نے کہا ہے کہ : حالانکہ اس بارے میں جو کچھ آپ سے روایت کیا گیا ہے قرآن ا س کے خلاف کہہ رہا ہے۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿یُوْصِیْکُمُ اللّٰہُ فِیْٓ اَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ﴾ [النساء۱۱]
’’اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے ۔‘‘
اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صرف امت کے ساتھ خاص نہیں کیا ۔
[ جواب]: اس کا جواب یہ ہے کہ : آیت کے الفاظ کے عموم سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارث بنیں گے۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿یُوْصِیْکُمُ اللّٰہُ فِیْٓ اَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ فَاِنْ کُنَّ نِسَآئً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَہُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَ اِنْ کَانَتْ وَاحِدَۃً فَلَہَا النِّصْفُ وَ لِاَبَوَیْہِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْہُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ اِنْ کَانَ لَہٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ یَکُنْ لَّہٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَہٗٓ اَبَوٰہُ فَلِاُمِّہِ الثُّلُثُ فَاِنْ کَانَ لَہٗٓ اِخْوَۃٌ فَلِاُمِّہِ السُّدُسُ﴾ [النساء۱۱]
’’ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں (یعنی دو یا) دو سے زیادہ؛ تو کل ترکے میں انکا دو تہائی اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف۔ اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ ہوگا؛ بشرطیکہ میت کی اولاد ہو اور اگراس کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ ہے؛ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ۔‘‘
دوسری آیت میں ہے:
﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ اَزْوَاجُکُمْ اِنْ لَّمْ یَکُنْ لَّہُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ کَانَ لَہُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ ........إلی قولہ تعالی........مِنْ بَعْدِ وَصِیَّۃٍ یُّوْصٰی بِہَآ اَوْدَیْنٍ غَیْرَ مُضَآرٍّ ﴾ [النساء۱۱]
’’اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں ، اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہاراہے اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی ہے....آگے یہاں تک کہ فرمایا....ادائے وصیت و قرض کے بعد ؛ بشرطیکہ میت نے ان میں سے کسی کا نقصان نہ کیا ہو ۔‘‘
یہ ان لوگوں کے لیے ایک شامل خطاب ہے جو کہ یہاں پر مقصود ہیں ۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے موجب ظاہر ہوتا ہوکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت میں مخاطب ہیں ۔
مخاطب کا’’کاف ‘‘ ان کو شامل ہوتا ہے جو خطاب سے مقصود ہوں ۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کوئی خاص اس خطاب سے مقصود ہے تو وہ اس خطاب میں شامل نہیں ہوگا۔ پھر بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ ضمائر مطلق طور پر تخصیص کو قبول نہیں کرتے ۔تو پھر ضمیر مخاطب کا کیاحال ہوگا؟ اس لیے کہ ضمیر خطاب تو صرف اس کے لیے ہوتی ہے جو مخاطب کا مقصود ہو؛ یہ ضمیر ان لوگوں کو شامل نہیں ہوتی جن کا قصد نہ کیا جائے۔اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ ضمیر عام ہے ‘ اور تخصیص قبول کرتی ہے ؛ توبلاشبہ یہ ان لوگوں کے لیے عام ہے جو اس خطاب سے مقصود ہیں ۔ اس آیت میں کوئی ایک اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کاتقاضا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مخاطبین سے مقصود ہیں ۔
اگر یہ کہا جائے کہ : تصور کیجیے ! تمام ضمائر خطاب ؛ متکلم اور غائب بذات خود کسی متعین چیز پر دلالت نہیں کرتیں ؛ مگر اپنے قرائن کی روشنی میں ان کی دلالت واضح ہوتی ہے۔پس ضمائر خطاب ان لوگوں کے لیے وضع کی گئی ہیں جو مخاطب کے خطاب سے مقصود ہو۔ اور ضمائر متکلم کلام کرنے والے کے لیے ہیں خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ بات معروف ہے کہ قرآن میں خطاب سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورتمام مؤمنین ہوتے ہیں ۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿یٰٓاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ ﴾ [البقرۃ ۱۸۳]
’’ اے مومنو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے ۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿یٰٓأَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلٰوۃِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْہَکُمْ وَ اَیْدِیَکُمْ اِلَی الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدہ ۶]
’’اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لو ۔‘‘
اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿یُوْصِیْکُمُ اللّٰہُ فِیْٓ اَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ﴾ [النساء۱۱]
’’اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے ۔‘‘
بلکہ کبھی کبھار قرآن مجید میں جمع کا ’’کاف ‘‘ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کے لیے آتا ہے ۔ اور کبھی کبھار صرف مؤمنین کے لیے آتا ہے ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِیکُمْ رَسُوْلَ اللّٰہِ لَوْ یُطِیعُکُمْ فِیْ کَثِیْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَکِنَّ اللّٰہَ حَبَّبَ اِِلَیْکُمُ الْاِِیْمَانَ وَزَیَّنَہٗ فِیْ قُلُوْبِکُمْ وَکَرَّہَ اِِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ اُوْلٰٓئِکَ ہُمْ الرَّاشِدُوْنَ ﴾ [الحجرات ۷]
’’ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ؛ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں ۔‘‘
یہاں پر کاف صرف امت کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿لَقَدْ جَآئَ کُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِیْمٌ ﴾ [التوبۃ ۱۲۸]
’’ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں ۔ تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں ۔ اورمومنوں پر نہایت شفقت کرنیوالے اورمہربان ہیں ۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿یٰٓاََیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَطِیعُوا اللّٰہَ وَاَطِیعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَکُمْ﴾ [محمد۳۳]
’’ مومنو! اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دو۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمُ اللّٰہُ وَ یَغْفِرْلَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ﴾ [آل عمران ۳۱]
’’ فرما دیجئے!اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔‘‘
اس طرح کی دیگر مثالیں بھی ہیں ۔ ان مواضع پر ’’کاف ‘‘ خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہیں ۔ بلکہ یہ ان تمام لوگوں کو شامل ہے جن کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجاگیا ہے ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں : ﴿ یُوْصِیْکُمُ اللّٰہُ فِیْٓ اَوْلَادِکُمْ ﴾ بھی’’کاف‘‘ اسی طرح ہے جیسے مذکورہ بالا آیات میں ۔پس سنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ظاہر قرآن کے مخالف ہو۔اسی آیت کی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے :
﴿ وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِی الْیَتٰمٰی فَانْکِحُوْا مَا طَابَ لَکُمْ مِّنَ النِّسَآئِ مَثْنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَۃً اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ ذٰلِکَ اَدْنٰٓی اَلَّا تَعُوْلُوْاo وَ اٰتُوا النِّسَآئَ صَدُقٰتِہِنّ نَحْلَۃً فَاِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْئٍ مِّنْہُ نَفْسًا فَکُلُوْہُ ہَنِیْٓئًا مَّرِیْٓئًا﴾ [النساء ۳۔۳]
’’اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے(کہ ایسا کرنے سے نا انصافی اور) ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ۔اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔‘‘
ان آیات میں ضمائر جیسے : ﴿ وَ اِنْ خِفْتُمْ﴾اور﴿ تُقْسِطُوْا﴾اور﴿فَانْکِحُوْا﴾اور﴿ مَا طَابَ لَکُمْ﴾ ﴿مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ﴾ امت کے لیے ہیں ؛ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ۔اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ آپ چار سے بیویوں سے شادیاں کریں ۔اور آپ کو یہ بھی اختیار حاصل تھا کہ بلا مہر شادی کریں ۔جیسا کہ نص اور اجماع کی روشنی میں ثابت ہے۔
اگر کوئی یہ بات کہے کہ : جو دلائل تم نے ذکر کیے ہیں ان مثالوں میں ایسے قرآئن موجود ہیں جو ان کے امت کے لیے خاص ہونے کا تقاضا کررہے ہیں ۔پس بیشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے وجوب کا ذکر کیا جائے ؛ یا آپ کی اطاعت و محبت کے لیے خطاب کیا جائے تو اس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب میں شامل نہیں ہیں ۔
تواس اعتراض کرنے والے کو کہا جائے گا: ایسے ہی میراث والی آیت کا حال ہے ؛ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿یُوْصِیْکُمُ اللّٰہُ فِیْٓ اَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ﴾ [النساء۱۱]
’’اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے ۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّۃٍ یُّوْصٰی بِہَآ اَوْدَیْنٍ غَیْرَ مُضَآرٍّ ﴾ [النساء۱۲]
’’ادائے وصیت و قرض کے بعد؛ بشرطیکہ ان سے میت نے کسی کو کوئی تکلیف نہ دی ہو ۔‘‘
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿تِلْکَ حُدُوْدُ اللّٰہِ وَ مَنْ یُّطِعِ اللّٰہَ وَ رَسُوْلَہٗ یُدْخِلْہُ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْھٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا وَ ذٰلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُo وَ مَنْ یَّعْصِ اللّٰہَ وَ رَسُوْلَہٗ وَ یَتَعَدَّ حُدُوْدَہٗ یُدْخِلْہُ نَارًا خَالِدًا فِیْہَا وَلَہٗ عَذَابٌ مُّہِیْنٌ﴾ [النساء ۱۳۔۱۳]
’’یہ اللہ کی مقرر کردہ حدودہیں اور جوکوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریگااسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہونگی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول(صلی اللہ علیہ وسلم )کی نافرمانی کریگا اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے گا اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اوراس کے لئے رسوا کن عذاب ہے ۔‘‘
جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عدم درایت کاخطاب کیا؛ جوکہ رسولوں کے احوال کے متناسب نہیں ہوسکتی ؛ تو پھر اس کے بعد وہ امور ذکر کیے جن میں ان رسولوں کی اطاعت واجب ہوتی ہے ؛ ان ہی امور میں سے میراث کے حصوں کی مقدار بھی تھی اوریہ کہ اگر وہ ان حدود کو قائم رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہ مخالفت اس طرح ہوگی کہ کسی وارث کو اس کے مقرر شدہ حصہ سے زیادہ دیا جائے۔ یا وارث جتنے حصہ کا مستحق ہے ؛ اس میں سے کچھ حصہ روک لیا جائے۔ آیات مبارکہ دلالت کرتی ہیں کہ ان کے مخاطبین سے درایت کا علم سلب ہے۔تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر وعدوں کا ذکر کیا گیا ۔ اوراللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے پر برے انجام سے ڈرایا گیاہے ۔حدود میراث میں تجاوز کے خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہیں ۔جیسا کہ اس جیسے دوسرے خطاب کے مواقع پر امت کو خطاب شامل ہے ‘آپ کو نہیں ۔
جب مال وراثت میں مقرر شدہ حصے ذکر کرنے کے بعد حدود سے تجاوز کرنے کی حرمت کا ذکر کیا گیا تو اس سے دلالت واضح ہوتی ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے مقررہ شدہ حصہ میں زیادہ کرے ؛ اور آیت دلالت کرتی ہے کہ ان ورثاء کے لیے وصیت کرنا بھی جائز نہیں ۔ یہ حکم پہلے حکم کا ناسخ ہے جس میں والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا :
’’ اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دیدیا ہے ۔ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے ۔‘‘[رواہ اہل السنن‘ ابو داؤد ۳؍۱۵۵؛کتاب الوصایا؛ باب ما جاء : في الوصیۃ للوارث ؛ والترمذي ۳؍۲۹۳۔کتاب الوصایا؛ باب ما جاء : لا وصیۃ للوارث ؛سنن النسائی ۶؍۲۰۷ ؛ کتاب الوصایا ؛ باب إبطال الوصیۃ ؛ ورواہ اہل سیر؛ واتفقت الأمۃ علیہ۔]
یہاں تک کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس حدیث سے آیت وصیت منسوخ ہوئی ہے۔اس لیے کہ استحقاق میراث اور استحقاق وصیت میں کوئی منافات نہیں پائی جاتی ۔ اور نسخ اسی وقت ہوتا ہے جب ناسخ اور منسوخ کے مابین منافات پائی جائے۔
سلف اور جمہور مسلمین کہتے ہیں : یہاں پر ناسخ آیت میراث ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے مقرر کر دیے ہیں ۔اور پھر ان حصوں سے تجاوز کرنے سے منع کردیا ہے ۔ پس جب مرنے والا اگر وارث کو اس کے مقرر حصہ سے زیادہ دے گا تو وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ اس نے مقرر کردہ حصہ میں زیادہ کیا ہے حقیقت میں وہ دوسرے وارثوں کا اور عصبہ کا حق تھا۔ جب عصبہ کا حق لیا جائے اور اس کو دیا جائے تو ایسا کرنے والا اللہ کے ہاں ظالم ٹھہرے گا۔
اس لیے علمائے کرام کے مابین اس انسان کے مسئلہ میں اختلاف واقع ہوا ہے جس کا کوئی عصبہ نہ ہو۔ تو کیا یہ مال باقی ورثہ پر رد کیا جائے گا یا نہیں ؟جس نے اس رد سے منع کیا ہے ؛ انہوں نے کہا ہے : میراث بیت المال کا حق ہے۔ کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں ۔اور جنہوں نے جائز کہا ہے ؛ وہ اس پر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں : اس مال کو بیت المال میں اس وقت رکھا جائے گا جب اس کا کوئی خاص مستحق نہیں ہوگا۔ جب کہ ان لوگوں کے عام اور دیگر خونی[رحمی] رشتہ دار موجود ہیں ۔جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے :
’’حصہ والے اس کے زیادہ حقدار ہیں جن کا کوئی حصہ نہ ہو۔‘‘
یہاں پر بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ رافضیوں کے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ وہ اس آیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرسکیں ۔
اگریہ کہا جائے کہ : اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کوئی ایک مرجائے ؛ جیسے آپ کی تین بیٹیوں کو انتقال ہوا؛ اور آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا ؛ تو کیاآپ ان کے وارث بنیں گے؟
جواب: اس آیت میں خطاب موروثین کے لیے ہے ‘ وارثین کے لیے نہیں ۔تو اس سے لازم نہیں آتا کہ جب آپ کی اولاد موروثین ہونے کی وجہ سے کاف خطاب میں داخل ہیں ؛تو وارثین میں بھی شامل ہوں ۔اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے:
﴿ وَ لِاَبَوَیْہِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْہُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ اِنْ کَانَ لَہٗ وَلَدٌ﴾ [النساء۱۱]
’’ اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ ہوگا؛ بشرطیکہ میت کی اولاد ہو۔‘‘
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غائب کی ضمیر کے ساتھ ذکر کیا ہے ‘ ضمیر خطاب کے ساتھ نہیں ۔پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی اولادیا باقی لوگوں سے میں جتنے بھی موروث ہیں سب کو شامل ہے ۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مخاطبین کے وارث تھے ۔ اور آپ کو اس طرح خطاب نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی آپ کا وارث بنے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ان میں سے ہیں جن کو کاف خطاب شامل ہے۔تو ان کو وصیت کی گئی ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ پس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کہ بیٹوں کے لیے دولڑکیوں کے برابرحصہ ہے ۔اور ان کے والدین کے لیے اگر [اولاد] والدین کی موجود گی میں فوت ہوجائیں ؛ توان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے ۔
٭ اگر یہ کہا جائے کہ: آیت زوجین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ’’ تم [شوہروں کے لیے ] اور ان [بیویوں کے لیے ]۔‘‘
جواب: پہلی بات یہ ہے کہ : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی وارث نہیں بنیں اور نہ ہی آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے وارث بنے ؛ بس صرف آپ کی اکیلی بیٹی ہی آپ کی وارث بنی تھی۔
دوسری بات:....اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایسی بیوی کے مرنے کا علم نہیں ہوسکا جس کے پاس مال ہو اور آپ اس کے وارث بنیں ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال مکہ میں ہوگیا تھا۔اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا الہلالیہ کا انتقال مدینہ میں ہوا؛ لیکن ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی مال بھی چھوڑا تھا؟ اور اس سے پہلے آیت فرائض نازل ہوچکی تھی۔کیونکہ اللہ تعالیٰ کایہ فرمان ان سب کو شامل ہے :
﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ اَزْوَاجُکُمْ﴾ [النساء۱۱]
’’اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں تو اس میں نصف حصہ تمہاراہے ۔‘‘
یہ خطاب عام ہے تم میں سے جس کی بھی بیوی مرے ‘اور ا سکا کوئی ترکہ ہو۔ پس اگر کسی کی بیوی مری ہی نہیں ‘یا اگر مری ہے تو اس نے اپنے پیچھے کو ئی مال نہیں چھوڑا تو ایسا انسان اس کاف خطاب میں شامل نہیں ہے ۔
اگر اس کو تسلیم بھی کرلیا جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ ایک کاف کے شامل ہونے کی وجہ سے دوسرے کاف کا شمول بھی لازم آئے گا۔ بلکہ یہ امر دلیل پر موقوف ہے ۔
اگر یہ کہا جائے : تم کہتے ہو: ’’ جو احکام آپ کے حق میں ثابت ہیں ؛ وہ آپ کی امت کے حق میں بھی ثابت ہیں ۔ اور ایسے ہی اس کے برعکس۔پس بیشک جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تووہ تمام امت کو شامل ہوتا ہے ۔یہ بات شارع کی عادت سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿فَلَمَّا قَضٰی زَیْدٌ مِّنْہَا وَطَرًا زَوَّجْنٰکَہَا لِکَیْ لَا یَکُوْنَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ حَرَجٌ فِیْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِیَآئِہِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْہُنَّ وَطَرًا ﴾ [الأحزاب ۳۷]
’’ پس جب زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کرلی توہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیاتاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالک کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح تنگی نہ رہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کرلیں ۔‘‘
اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لیے حلال کردیا ہے تاکہ آپ کی امت کے لیے بھی حلال ہوجائے ۔ آپ کو اس حلت میں خاص نہیں کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے حکم میں ارشاد فرمایا :
﴿ وَامْرَاَۃً مُّؤْمِنَۃً اِنْ وَّہَبَتْ نَفْسَہَا لِلنَّبِیِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِیُّ اَنْ یَّسْتَنْکِحَہَا خَالِصَۃً لَّکَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴾ [الأحزاب ۵۰]
’’ اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے یہ خاص طور پر صرف آپ کے لئے ہی ہے اور مومنوں کے لئے نہیں ۔‘‘
تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ کاف آپ کو شامل نہیں ہے؟
جواب :شارع کی عادت سے معلوم ہے کہ جب اس کی طرف سے خطاب آتا ہے تو وہ عام اور شامل ہوتا ہے ۔ جیسا کہ بادشاہوں کی عادت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کسی امیر کو کوئی حکم دیتے ہیں ‘ تو اس امیر یا عامل کے امثال و نظائر بھی اس میں مخاطب ہوتے ہیں ۔تویہ عادت اوراستقراء سے مخاطب کے لیے کئے گئے خطاب سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ الفاظ کے معانی اہل لغت کے ہاں استقراء و تتبع سے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں فلاں کلمے کا یہ معنی لیا جاتاہے ۔
پس قرآن کریم کی عادت مبارک ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے مختلف رنگ و اسلوب اختیار کرتا ہے ۔ کبھی یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو شامل ہوتاہے اورکبھی شامل نہیں ہوتا۔تو اس سے واجب نہیں آتا کہ اس موقع پر بھی یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل ہو۔مدعی کے دعوی کی آخری حدیہ ہوسکتی ہے کہ : اصل میں ’’کاف ‘‘ خطاب آپ کو بھی شامل ہے۔جیساکہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے ساتھ احکام میں برابر ہیں ۔ اوراحکام شریعت میں آپ اس امت کے ساتھ مساوی ہیں ۔یہاں تک کہ کسی مسئلہ کے آپ کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل مل جائے۔یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خصائص ہیں جو باقی امت کے برعکس صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں ۔اہل سنت والجماعت کہتے ہیں : یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ وراثت نہیں چھوڑتے ۔ پس کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس حکم میں آپ کی خصوصیت کا انکار کرے ؛ یہ انکار وہی کرسکتا ہے جو باقی تمام خصوصیات کا انکار کرتا ہو۔لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کسی بھی انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی خصوصیت کے لیے دلیل طلب کرے۔بطور دلیل اس بارے میں صحیح اور مشہور بلکہ متواتر احادیث موجود ہیں کہ آپ نے وراثت نہیں چھوڑی ۔ آپ کے اختصاص میں مروی اہم ترین احادیث میں سے مال فئے کے آپ کے ساتھ خاص ہونے کی احادیث ہیں ۔
سلف و خلف میں بہت سارے احکام کے متعلق اختلاف موجود ہے کہ کیا یہ احکام آپ کے ساتھ خاص تھے ؟ جیسا کہ فئے اور خمس کے متعلق اختلاف ہے کہ کیایہ مال آپ کی ملکیت ہوا کرتا تھا یا نہیں ؟ اور کیا جو عورتیں آپ پر حرام تھیں وہ آپ کے لیے مباح کردی گئی تھیں یا نہیں ؟ لیکن سلف و خلف کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی ؛ کیونکہ یہ مسئلہ آپ سے صاف ظاہر منقول اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم میں مشہور تھا۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں :
﴿ یَسْئَلُوْنَکَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰہِ وَ الرَّسُوْلِ﴾ (الانفال ۱)
’’ وہ تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں ، کہہ دے غنیمتیں اللہ اور رسول کے لیے ہیں ۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:
﴿ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْئٍ فَاَنَّ لِلّٰہِ خُمُسَہٗ وَ لِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی وَ الْیَتٰمٰی وَ الْمَسٰکِیْنِ وَ ابْنِ السَّبِیْلِ ﴾ (الانفال۳۱)
’’اور جان لو کہ بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔‘‘
اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں :
﴿مَا اَفَائَ اللّٰہُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ مِنْ اَہْلِ الْقُرَی فَلِلَّہِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِیْ الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْل﴾ (الحشر۷)
’’جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں سے اپنے رسول پر لوٹایا تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔‘‘
آیت کریمہ میں لفظ فئے بالکل ویسے ہی ہے جیسے لفظ خمس ۔سورۃ انفال کے نزول کا سبب بدر کا واقعہ تھا۔ تو اس میں اموا ل غنیمت بلا شک و شبہ داخل ہیں ۔ اور اس میں وہ تمام اموال فئے بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کفار کے مال میں سے مسلمانوں پر انعام کرتے ہیں ۔ اورجیسے لفظ ’’فئے ‘‘ سے وہ تمام اموال مراد لئے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بغیر جنگ کے عطا کرتے ہیں ؛ تو غنیمت کا مال بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ صرف اس مال ِفئے کی حد تک خاص ہوتا ہے جو بغیر لڑائی اور قتال کے ہاتھ آجائے۔ جس پر سواریا پیادے نہ دوڑے ہوں ۔ پہلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ہے:
’’جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال فئے دیا ہے ‘ اس میں سے میرا صرف پانچواں حصہ ہے ۔اور یہ پانچواں حصہ بھی آپ لوگوں کی ہی واپس دیا جاتاہے۔ ‘‘[سننِ النسائِیِ:۷؍۱۱۹؛ ِکتاب قسمِ الفیئِ ؛ وفِی سننِ بِی داود:۳؍۱۰۹ کتاب الجِہادِ، باب فِی الإِمامِ یستأثِر بِشیء مِن الفیئِ لِنفسِہِ؛ صحِیحِ الجامِعِ الصغِیرِ:۶؍۲۷۲؛ سِلسِلۃِ الأحادِیثِ الصحِیحۃ:۲؍۵۸۷؛ جاء الحدِیث مرسلا عن عبدِ اللہِ بنِ عمرو فِی: الموطِأ:۲؍۴۵۷؛ کتاب الجِہادِ، باب ما جاء فِی الغلول۔]
یہ خمس اور فئے کے بارے میں ہے ۔پس یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت اس حیثیت سے ہے ؛ اسی لیے علماء کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس اضافت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے ایسے ہی مالک ہیں جیسے تمام لوگوں کی املاک ہوتی ہیں ۔ اور پھر اس میں سے اموال غنیمت کو لڑنے والے مجاہدین کے لیے خاص کردیا گیا۔ اور اس میں سے پانچواں حصہ ان لوگوں کا ہے جن کا نام لے کر قرآن میں ذکر آیاہے۔ باقی رہ گیا مال ِ فئے یا بقیہ چار حصے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہیں ؛ جیسا کہ امام شافعی اور امام أحمد رحمہما اللہ کے اصحاب میں سے ایک گروہ کا خیال ہے؛ کہ اسے فئے میں لوٹایا جائے گا۔ جب اکثر علماء کہتے ہیں : مال فئے میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا۔ اس کے خمس کا صرف امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہے؛ جیسے امام خرقی۔ جبکہ امام مالک ؛ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ ؛ اوران کے جمہور اصحاب ؛ اور دیگر تمام ائمہ مسلمین کے نزدیک مال فئے میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا۔ فئے اس مال کو کہتے ہیں : جو مشرکین سے لڑے بغیر حاصل ہو؛ جیسے جزیہ اورخراج ۔
علماء کے ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ اس اضافت کاتقاضا نہیں کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے مالک ہوں ؛ بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا نظام اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہے۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس مال کو تقسیم کرتے ہیں ۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :
’’ اللہ کی قسم! میں تم میں سے کسی کو نہ کچھ دیتا ہوں اور نہ ہی کسی سے کچھ روکتا ہوں ؛ بلکہ میں تقسیم کرنے والا ہوں ؛ میں وہیں پر رکھتا ہوں جہاں کا مجھے حکم دیا جاتا ہے۔‘‘[البخارِیِ:۴؍۸۵؛ فِی المسندِ ط۔الحلبِی:۲؍۴۸۲: ونصہ فِیہِ:’’ واللّٰہِ ما أعطِیکم ولا أمنعکم، وِإنما أنا قاسِم أضعہ حیث أمِرت۔وقال ابن حجر فِی تعلِیقِہِ علی حدِیثِ البخارِیِ فتحِ البارِی: ۶؍۲۱۸۔ ]
اور ایک دوسری صحیح حدیث شریف میں ہے؛ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
’’ میرے نام پر نام رکھو؛ اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو؛ بیشک میں تقسیم کرنے والا ہوں ؛ جو تمہارے مابین تقسیم کرتا ہوں ۔ ‘‘[البخارِیِ:۴؍۸۴؛ کتاب فرضِ الخمسِ، باب قولِ اللّٰہِ تعالی: فإن لِلّٰہِ خمسہ؛ مسلِم:۳؍۱۶۸۲؛ ِکتاب الآدابِ، باب النہیِ عنِ التکنِیۃ بأِبِی القاسِمِ ؛ سننِ أبِی داود:۴؍۳۹۹کتاب الأدبِ، باب فِی الرجلِ یتکنی بِأبِی القاسِمِ، باب من رأی أن لا یجمع بینہما، باب فِی الرخصۃِ فِی الجمعِ بینہما؛ سننِ التِرمِذِیِ:۴؍۲۱۴کتاب الأدبِ، باب ما جاء فِی کراہِیۃِ الجمعِ بین اسمِ النبِیِ صلی اللّٰہ علیہ وسلم وکنیتِہِ ؛ المسندِ ط۔ المعارِفِ الرقم:۷۳۰۔]
پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوامر و نواہی پہنچانے والے ہیں ۔پس جس مال کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی گئی ہو؛ وہ ایسا مال ہے جو ان جگہوں پر خرچ ہوگا جہاں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؛ خواہ وہ واجب ہو یا مستحب ۔ بخلاف ان اموال کے جن کا مالک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بنا دیتے ہیں ۔ ان کے لیے اس مال کا مباح امورمیں خرچ کرنا جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معاہدہ کرنے والے غلاموں کے بارے میں ارشاد فرمایا:
﴿ وَّآتُوہُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰہِ الَّذِیْ آتَاکُمْ ﴾ (النور۳۳)
’’ اور انھیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمھیں دیا ہے۔‘‘
اکثر علماء جیسے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ اوردیگر حضرات کا کہنا ہے کہ: ’’تمہیں دیا ہے ‘‘ سے مراد وہ اموال ہیں جن کا مالک اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بنایا ہے۔ کیونکہ اس مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا گیا جیسے دوسری جگہ پر دوسرے مال کو منسوب کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ مال صرف وہاں پر خرچ کیا جائے گا جہاں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔
نفلی اموال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں ؛ کیونکہ ان کی تقسیم اللہ اوررسول کے مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔وہ ان اموال وراثت کی طرح نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مستحقین میں تقسیم کردیے ہیں ۔یہی حکم مال خمس اور مالِ فئے کا بھی ہے۔
مال خمس اور مالِ فئے کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے۔امام مالک رحمہ اللہ اوردیگر علماء کہتے ہیں : ان دونوں قسم کے اموال کا مصرف ایک ہی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے۔ اور کچھ اصناف اس کے لیے متعین کردی گئی ہیں ؛ جیسے ایتام ؛ مساکین ؛ مسافر ؛انہیں بالخصوص ذکر کیا گیاہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی اس کی موافقت روایت کی گئی ہے۔
آپ خمس کے مال کو معدنیات اور ذخائر کی طرح سمجھتے ہیں ۔اوریہ مال فئے مال غنیمت کے خمس کے تابع ہے۔جب کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں : اس کے تین حصے کئے جائیں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں کے حصہ کو ساقط قرار دیتے ہیں ۔ اورداؤد بن علی رحمہ اللہ کا کہنا ہے: بلکہ مال فئے کو بھی پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جبکہ پہلا قول صحیح ترین قول ہے۔ جیسا کہ یہ تفصیل اپنی جگہ پر گزر چکی ہے۔ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورسنت خلفائے راشدین اسی پر دلالت کرتی ہے۔
فرمان ربانی : ﴿فَلِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ﴾ ’’ تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ‘‘ یہ خمس اور فئے سے متعلق ہے ۔جیسا کہ انفال کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: ﴿لِلَّہِ وَلِلرَّسُوْلِ﴾ اس مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان اموال کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقسیم کرتے ہیں ۔ یہ اموال کسی کی ملکیت نہیں ہیں ۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :
’’ اللہ کی قسم! میں تم میں سے کسی کو نہ کچھ دیتا ہوں اور نہ ہی کسی سے کچھ روکتا ہوں ؛ بلکہ میں تقسیم کرنے والا ہوں ؛ میں وہیں پر رکھتا ہوں جہاں کا مجھے حکم دیا جاتا ہے۔‘‘[سبق تخریجہ]
یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ ان اموال کے مالک نہیں ؛ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے والے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ بادشاہ نبی بن جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے متواضع بندے اور رسول بن جائیں توآپ نے متواضع بندہ اور رسول بن جانے کو اختیار فرمایا ۔ یہ ان دونوں منزلتوں میں سے اعلی ترین منزلت ہے ۔ بادشاہ مال کو اپنی پسند میں خرچ کرتا ؛ اس کا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب کہ متواضع بندہ رسول مال کو صرف اس جگہ پر خرچ کرتا ہے جہاں کا اسے حکم دیا جائے۔ پس اس لحاظ سے آپ جو بھی کام کرتے؛ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت ہوتی۔ آپ کی تقسیم میں کو ئی ایسا مباح امر نہیں ہوتاتھا جس پر آپ کو ثواب نہ ملے۔ بلکہ آپ کو ہر ایک کام پر ثواب ملتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے :
’’جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال فئے دیا ہے ‘ اس میں سے میرا صرف پانچواں حصہ ہے ۔اور یہ پانچواں حصہ بھی آپ لوگوں کی ہی واپس دیا جاتاہے۔ ‘‘[سنن أبي داؤد ۳؍۱۰۹۔کتاب الجہاد ؛ باب في الإمام یستأسر بشئي من الفئی لنفسہ ۔ و الحدیث صحیح ؛ صححہ الألباني في صحیح الجامع الصغیر ۶؍ ۲۷۲۔ والنسائی ۷؍۱۱۹۔ کتاب قسم الفئی۔ الموطأ ۲؍۴۵۷۔]
یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔اس لیے کہ حدیث میں لفظ: ’’اس میں سے میرا ‘‘ کا مطلب ہے کہ اس کا معاملہ میرے ذمہ ہے۔ اسی لیے فرمایا: ’’اور یہ پانچواں حصہ بھی آپ لوگوں کی ہی واپس دیا جاتاہے۔ ‘‘
اس اصل کی بنیاد پر آپ کے ہاتھ میں جو بھی اموال تھے ؛ اموال بنی نضیر؛ فدک؛ خیبر کاخمس وغیرہ ؛ یہ تمام اموال مالِ فئے تھے ؛ جوکہ آپ کی ملکیت نہیں تھے؛ اس وجہ سے وہ آپ کی طرف سے کسی کو وراثت میں نہیں ملیں گے ۔ وراثت میں تووہ مال ملتاجو آپ کی ملکیت ہوتا ۔بلکہ ان اموال کے متعلق واجب تھا کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے پسندیدہ اور محبوب کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔یہی بات تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔
رہی وہ روایات جن کی بناپر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ آپ اس مال کے مالک تھے۔جیسے کہ وہ مال جس کا ایک حصہ حضرت مخیریق کو دینے کی وصیت کی تھی؛تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ : اس مال کا حکم پہلے مال کاہے ۔اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مال آپ کی ملکیت تھا۔لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے لیا کریں اور جو ضرورت سے بچ جائے وہ صدقہ ہوگا ‘ اسے وراثت میں نہیں دیا جائے گا۔
صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
’’ میرے ورثہ درہم ودینار تقسیم نہیں کریں گے۔جو کچھ میں اپنے بعد چھوڑوں گا وہ میری بیویوں کا خرچہ ہوگا اورمیرے عمال کی محنت مزدوری ہوگی [جو اس سے بچ جائے ] وہ صدقہ ہوگا۔ ‘‘[البخاري ۴؍۱۲۔کتاب الوصایا ؛ باب نفقۃ القیم للوقف ؛ مسلم ۳؍۱۳۸۲۔ کتاب الجہاد والسیر ؛ باب قول النبي صلی اللّٰہ علیہ وسلم لا نورث ؛ سنن أبي داؤد ۳؍ ۱۹۸ ؛ کتاب الخراج الإمارۃ و الفئي ؛ باب صفایا الرسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم ۔ ]
اورصحیحین میں ہی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
’’ہم وراثت نہیں چھوڑتے ؛ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ۔‘‘[البخاري ۸؍۱۲۵؛ ومسلم ۳؍۱۳۷۹۔وسبق تخریجہ۔]
اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے جن میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور امام مسلم نے بھی آپ سے اوردوسرے صحابہ کرام سے یہ حدیث نقل کی ہے۔
یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے سیاق میں واقع ہے:[اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ]:
﴿ وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِی الْیَتٰمٰی فَانْکِحُوْا مَا طَابَ لَکُمْ مِّنَ النِّسَآئِ مَثْنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَۃً اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ ذٰلِکَ اَدْنٰٓی اَلَّا تَعُوْلُوْاo وَ اٰتُوا النِّسَآئَ صَدُقٰتِہِنّ نَحْلَۃً فَاِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْئٍ مِّنْہُ نَفْسًا فَکُلُوْہُ ہَنِیْٓئًا مَّرِیْٓئًا ﴾ [النساء ۳۔۳]
’’اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو دیگر عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی ؛یہ زیادہ قریب ہے(کہ ایسا کرنے سے نا انصافی اور) ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ۔اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔‘‘ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا :
﴿یُوْصِیْکُمُ اللّٰہُ فِیْٓ اَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ﴾ [النساء۱۱]
’’اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے ۔‘‘
یہ بات معلوم شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں مخاطب نہیں ہیں ۔اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو تین یا چار بیویاں نہیں تھیں ۔بلکہ آپ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اس سے زیادہ جتنی بھی چاہیں شادیاں کرلیں ۔اورنہ ہی آپ کو یہ حکم تھا کہ بیویوں کو ان کامہر پورا پورا اداکریں ۔بلکہ آپ کو اختیار حاصل تھا کہ اگر کوئی عورت اپنا نفس آپ کو ہبہ کردے تو آپ اسے بغیر مہر کے قبول کرسکتے تھے ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿یٰٓاَیُّہَا النَّبِیُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَکَ اَزْوَاجَکَ الّٰتِیْٓ اٰتَیْتَ اُجُوْرَہُنَّ وَ مَا مَلَکَتْ یَمِیْنُکَ مِمَّآ اَفَآئَ اللّٰہُ عَلَیْکَ وَ بَنٰتِ عَمِّکَ وَ بَنٰتِ عَمّٰتِکَ وَ بَنٰتِ خَالِکَ وَ بَنٰتِ خٰلٰتِکَ الّٰتِیْ ہَاجَرْنَ مَعَکَ وَامْرَاَۃً مُّؤْمِنَۃً اِنْ وَّہَبَتْ نَفْسَہَا لِلنَّبِیِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِیُّ اَنْ یَّسْتَنْکِحَہَا خَالِصَۃً لَّکَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْہِمْ فِیْٓ اَزْوَاجِہِمْ وَ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُہُمْ لِکَیْلَا یَکُوْنَ عَلَیْکَ حَرَجٌ وَّ کَانَ اللّٰہُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا﴾ [الأحزاب۵۰]
’’ اے نبی!ہم نے آپ کے لئے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں آپ ان کے مہر دے چکے ہیں ؛ اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دی ہیں اورآپ کے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے یہ خاص طور پر صرف آپ کے لئے ہی ہے اور مومنوں کے لئے نہیں ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کی بابت احکام مقرر کر رکھے ہیں یہ اس لئے کہ آپ پر حرج واقع نہ ہو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑے رحم والا ہے ۔‘‘
جب یہ سیاق کلام ہے ‘ تو اس سے واضح ہوگیا کہ یہ[سابقہ آیت میں ] خطاب امت کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ؛ آپ اس آیت کے عموم میں داخل نہیں ہیں۔
٭ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ : اس آیت[سابقہ] میں خطاب عام ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواور امت کو شامل ہے ؛ مگر اسے آیت نکاح اور آیت مہر سے خاص کیا گیا ہے ۔
جواب: تو اس سے کہا جائے گا: ایسے ہی آیت میراث سے بھی اس حکم کو خاص کیا گیا ہے ۔جو کچھ بھی تم اس کے جواب میں کہوگے وہی تمہارے اعتراض کا جواب ہوگا۔ بھلے آپ یہ کہو کہ آیت کے الفاظ آپ کو شامل ہیں اور پھر آپ کو اس سے خاص کیا گیا ہے ۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ : یہ آیت آپ کو شامل نہیں ہے؛ اس لیے کہ آپ اس کے مخاطبین میں سے نہیں تھے ۔یہی بات اس موقع پر بھی کہی جائے گی۔
ساتویں وجہ :....اس آیت کا مقصود یہ بیان کرنا نہیں کہ کون وارث بنے گا اورکون وارث نہیں بنے گااور نہ ہی اس میں وارث اور موروث کے احوال و اوصاف کا بیان ہے ۔بلکہ یہاں پر مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ مالِ موروث اس تفصیل کیساتھ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ پس یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ان حصہ داروں کو جب وہ وارث بنیں تو اس تفصیل کے ساتھ حصے دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مرنے والا مسلمان ہو‘اور اس کے ورثاء کافر ہوں تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ کفار اس مسلمان کے وارث نہیں بنیں گے۔اور ایسے ہی اگر مرنے والا کافر ہو اور اس کے اقرباء مسلمان ہوں تو بھی وہ اس کے مال کے وارث نہیں بنیں گے ؛ جمہور مسلمین کا یہی مسلک ہے۔ایسے ہی اگر مرنے والا غلام ہو اور اس کے ورثہ آزاد ہوں ‘ یا مرنے والا آزاد ہواور اس کے ورثہ غلام ہوں ؛ اور ایسے ہی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے والا بھی جمہور مسلمین کے نزدیک وارث نہیں بنیں گے۔ایسے ہی غلطی سے قتل کرنے والا دیت میں وارث نہیں بنے گا ۔ اس طرح کے باقی مسائل میں بھی اختلاف ہے۔جب یہ علم حاصل ہوگیاکہ مرنے والوں میں بعض ایسے بھی ہونگے جنکی اولاد ان کی وارث بنے گی اور بعض کی اولاد ان کی وارث نہیں بنے گی۔آیت نے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی کہ کون اس کا وارث بنے گا اور کون اس کا وارث نہیں بنے گا۔اور نہ ہی وارث اور موروث کے کوئی اوصاف و احوال بیان ہوئے ہیں ۔تو اس سے معلوم ہوا یہاں پر مقصود اس کی تفصیل کا بیان کرنا نہیں ‘ بلکہ ان وارثوں کے حقوق بیان کرنا ہے ۔پس اس آیت میں یہ بیان نہیں ہوا کہ کون وارث بنے گا اور کس کا وارث بنے گا۔ اس میں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے کہ غیر نبی وارث بنے گا یا اسے وراثت نہیں دی جائے گی۔توپھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موروث نہ ہونے پر دلالت بدرجہ اولی موجود ہے ۔
ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے:
’’ اس زمین میں عشر ہے، جسے آسمان یا چشمہ کا پانی سیراب کرے یا خود بخود سیراب ہو اور جس زمین کو کنوئیں سے سیراب کیا جائے، اس میں بیسواں حصہ واجب ہے۔‘‘[البخارِیِ:۲؍۱۲۶؛ کتاب الزکاۃِ، باب العشرِ فِیما یسقی مِن مائِ السمائِ ؛ مسلِم:۲؍۶۷۵؛ ِکتاب الزکاۃِ، باب ما فِیہِ العشر و نِصف العشرِ ؛ سننِ أبِی داود:۲؍۱۴۵؛ ِکتاب الزکاۃِ، باب صدقِۃ الزرعِ ؛ سننِ التِرمِذِیِ ؛ ِکتاب الزکاۃِ، باب ما جاء فِی الصدقۃِ فِیما یسق بِالنہارِ وغیرِہا۔]
اگر اس سے مقصود یہ فرق کرنا ہو کہ کس چیز میں دسواں حصہ واجب ہے؛ اور کس چیز میں بیسواں حصہ واجب ہے؛ اور یہ بیان مقصود نہیں کہ ان میں سے کسی ایک میں کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے؛ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کے عموم سے سبزیوں میں زکاۃ کے واجب ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔
فرمان الٰہی ہے:
﴿وَ اَحَلَّ اللّٰہُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ﴾ (البقرۃ ۲۷۵]
’’اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے؛ اور سود کو حرام ۔‘‘
یہاں پر تجارت اور سود میں فرق بتانا مقصود ہے۔ یہ کہ ان میں سے ایک میں حرام ہے اور دوسرا حلال۔ یہاں پر یہ بیان مقصود نہیں کہ کس چیز کی تجارت جائز ہے اور کس کی ناجائز ۔ پس اس آیت کے عموم سے ہر ایک چیز کے بیچنے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اورجس کسی کا خیال یہ ہو کہ ’’اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے‘‘ یہ حکم مردار ؛ خنزیر اور شراب اور کتے ؛ اور لونڈی اور وقف اور دوسرے کی ملکیت ؛ اور پھلوں کی پکنے سے پہلے کی خرید و فروخت کو شامل ہے؛ تو یقیناً وہ غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے۔
آٹھویں وجہ :....اس سے کہا جائے گا : تصور کیجیے ! اس آیت کے الفاظ عام ہیں ۔ اوراس میں سے کسی کافر بیٹے ؛ یا غلام یا قاتل کوایسے دلائل سے خاص کیا گیا ہے جو ان دلائل سے کمزور تر ہیں جن کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے عموم سے خارج کیا گیا ہے ۔اس لیے کہ جن صحابہ کرام نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ : آپ وراثت نہیں چھوڑتے۔‘‘ وہ ان صحابہ سے زیادہ جلیل القدر اہل علم اور کثرت کے ساتھ ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔یا قاتل کو میراث نہیں ملے گی ۔ اوریہ کہ جوکوئی اپنے غلام کو فروخت کرے ؛ اور اس غلام کا کچھ مال بھی ہو‘ تووہ مال بیچنے والے کا ہوگا سوائے اس صورت کے کہ خریدنے والا اس مال کی شرط بھی لگائے ۔
خلاصہ کلام ! جب یہ آیت کسی نص سے یا اجماع سے مخصوص ہے تو پھر کسی دوسری نص سے اس کی تخصیص کرنا باتفاق مسلمین جائز ہے۔بلکہ علمائے کرام رحمہم اللہ کے ایک گروہ کا نکتہء نظر یہ ہے کہ عام مخصوص مجمل ہی باقی رہے گا۔ عموم قرآن جب کہ خبر واحد سے مخصص نہ ہو تواس کی تخصیص کی بابت علماء کا اختلاف ہے۔ جب کہ عامِ مخصوص کی تخصیص عام خبر واحد سے کی جاسکتی ہے؛ خصوصاً ایسی خبر جسے قبول عام حاصل ہو۔ بلاشک وہ شبہ وہ اس سے عموم قرآن کی تخصیص پر متفق ہیں ۔
٭ اس خبر کو صحابہ کرام میں قبول عام حاصل رہا ہے؛ اور اس پر عمل کرنے پر ان کا اجماع ہے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ ۔
٭ مستفیض نصوص اور اجماع سے تخصیص متفق علیہ مسئلہ ہے۔ جو لوگ اس مسلک پر چلتے ہیں وہ کہتے ہیں : ظاہر آیت عموم کا فائدہ دیتی ہے؛ لیکن یہ عموم مخصوص ہے۔ اور جو حضرات پہلے مسلک پر عمل پیرا ہیں ؛ وہ اس عموم کے ظہور کو صرف ان لوگوں تک تسلیم کرتے ہیں جن کے بارے میں علم ہو کہ وہ وارث بنیں گے۔ اور یہ نہیں کیا جائے گا کہ: اس کا ظاہر متروک ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں : یہاں پر مقصود صرف وارث کے حصے کا بیان ہے۔ اس حال کا بیان نہیں جس میں وراثت ثابت ہوگی۔ پس آیت مرنے والوں کے ورثاء اولاد میں عام ہے ؛اور موروثین میں مطلق۔ جب کہ اس آیت میں وراثت کی شروط سے تعرض نہیں کیا گیا۔ بلکہ یہ آیت میں مطلق ہیں ؛ نہ ہی اس میں نفی کی دلیل ہے اور نہ ہی اثبات کی ۔جیسا کہ حکم ربانی ہے:
﴿ُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِیْنَ حَیْثُ وَ جَدْتُّمُوْہُمْ﴾ (التوبۃ ۵]
’’مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ ؛ انہیں قتل کر ڈالو ۔‘‘
یہ حکم ربانی اشخاص میں عام ہے: اور جگہ اور احوال میں مطلق ہے۔ پس جو خطاب اس مطلق کو مقید کرنے والا ہوگا؛ وہ اس شرعی حکم کے بیان سے شروع ہوگا جس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہ گزری ہو جو اس کے منافی ہو۔ اور نہ ہی اس ظاہری خطاب شرعی کو ختم کرنے والا اور اس اصل کا مخالف ہو۔
نویں وجہ :....نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وراثت نہ چھوڑنا قطعی دوٹوک سنت اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ سنت اور اجماع میں سے ہر ایک دلیل قطعی ہے ۔اس کا مقابلہ کسی ایسی روایت سے نہیں کیا جاسکتا جس کے عام ہونے کے بارے میں گمان کیا جاتا ہو ۔ اگرایسا کوئی عموم ہو بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ مخصوص ہے۔ اور اگر اسے دلیل تسلیم بھی کرلیا جائے تو یہ دلیل ظنی ہوگی۔ دلیل قطعی کو دلیل ظنی سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کوکئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مختلف اوقات اور مختلف مجالس میں بیان کیا ہے۔ ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس کا انکار کیا ہو۔ بلکہ ہر ایک نے اسے مانااور اس کی تصدیق کی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے بھی میراث حاصل کرنے کے لیے اصرار نہیں کیا ۔ اور نہ ہی آپ کے چچا محترم [حضرت عباس رضی اللہ عنہ ] نے میراث کے لیے اصرار کیا ۔ بلکہ ان میں سے اگر کسی نے ایسا کو ئی مطالبہ کیا بھی تواسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی خبر دی گئی تو انہوں نے اپنے مطالبہ سے رجوع کرلیا ۔ یہ معاملہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے مبارک عہد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور تک ایسے ہی رہا ۔اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی گئی اور نہ ہی آپ کا ترکہ تقسیم کیا گیا ۔
[[صحابہ اس بات پر یقین رکھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس ضمن میں پیش پیش تھے....کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کوئی نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے، تو انہوں نے آپ کے ترکہ کو تقسیم کیا نہ اس کے مصرف میں کوئی تبدیلی پیدا کی۔ آیت میراث کے عموم سے آپ کی وراثت پر استدلال کرنا اس لیے صحیح نہیں کہ انبیاء کی وراثت اس سے مستثنیٰ ہے، جس طرح یہ مسائل استثنائی حیثیت رکھتے ہیں ، کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور قتل عمد کا مرتکب ورثہ سے محروم رہتا ہے، نیز یہ کہ غلام وارث نہیں ہوتا]]
دسویں وجہ :....یہ امر قابل غور ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے متعلقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ سے کئی گنا زائد مال دے دیا تھا۔ اس کے پہلو بہ پہلو یہ بات بھی فراموش کرنے کے قابل نہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے خود اس مال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا؛ بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متروکہ مال حضرت علی رضی اللہ عنہ و عباس رضی اللہ عنہ کو اس مقصد کے پیش نظر دے دیا تھا کہ وہ اسے انہی مصارف میں خرچ کریں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے [صحیح بخاری ۳۰۹۸۴، صحیح مسلم:۴۹؍۱۷۵۷۔]اس سے اس تہمت کا ازالہ ہوجاتا ہے جو ان دونوں اکابر پر عائد کی جاتی ہے۔
گیارھویں وجہ :....شیعہ کے جواب میں کہا جائے گا کہ : ظالم بادشاہوں کی عادت رہی ہے کہ وہ جب ان دوسرے لوگوں کے بعد اقتدار میں آجاتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہو‘اور ان کی اچھی تربیت کی ہو‘ اور انہوں نے اس گھرانے سے بادشاہی چھین لی ہو؛ تووہ اس متاثرہ گھرانے کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا سلوک کرتے ہیں ‘ اور انہیں عطیات سے نوازتے ہیں تاکہ انہیں اس منازعت[تنازعہ ] سے روک سکیں ۔[اور انہیں کچھ دیکر خاموش کرادیں ]۔
اگر شیعہ کا یہ مفروضہ تسلیم کر لیا جائے کہ۔العیاذ باللہ ۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ظالم و غاصب تھے، اور انہوں نے جبراً خلافت پر قبضہ جما لیا تھا تو اس کا تقاضا تھا کہ وہ ان ورثاء سے مزاحم نہ ہوتے جو خلافت و امامت کا استحقاق رکھتے تھے، بلکہ خلافت کے دعوی سے دور رکھنے کے لیے انہیں من مانی دولت عطا کر دیتے تاکہ وہ حکومت و خلافت کا مطالبہ نہ کریں ۔جب کہ حکومت بھی چھین لینا اورمیراث بھی کلی طور پرروک لینا بادشاہوں کی سیرت میں ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوسکی؛ اگرچہ وہ سب سے ظالم اور فاسق و فاجر حکمران ہی کیوں نہ ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ جوکچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گیا ہے وہ بادشاہوں اور حکمرانوں کی عادت و طبیعت سے خارج امر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مؤمنین کی عادات شرعیہ سے بھی خارج ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس معاملہ میں خاص کیا ہوا تھا یہ خصوصیت دوسرے حکمرانوں کے نصیب میں نہیں آئی۔ آپ کی خصوصیت نبوت تھی ؛ او رانبیاء کرام علیہم السلام وراثت نہیں چھوڑا کرتے ۔
انبیاء کی میراث:
بارھویں وجہ :....شیعہ قرآن کریم کی آیت: ﴿ وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاؤٗدَ ﴾’’ اور سلیمان داؤد کے وارث بنے ‘‘ نیز :﴿فَہَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّاo یَّرِثُنِیْ وَ یَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْب﴾ [مریم۵۔۶]
’’پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا۔‘‘
[ان مذکورہ بالاآیات ]سے انبیاء علیہم السلام کی وراثت پر استدلال کرتے ہیں ۔حالانکہ ان کا دعوی اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ’’ ورثہ ‘‘ اسم جنس ہے اور اس کے تحت متعدد انواع ہیں ۔ اور ایک عام چیز کا ذکر کرنے سے کسی خاص چیز کا ذکر لازم نہیں آتا۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ یہاں حیوان موجود ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں انسان یا گھوڑا یا اونٹ موجود ہے ۔ بعینہ اسی طرح ورثہ کا لفظ میراث علم و نبوت اورملوکیت اور مادی وراثت پر بولا جاتا ہے، مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ ہوں :
﴿ ثُمَّ اَوْرَثنَا الْکِتٰبَ الَّذِیْنَ اصْطَفَیْنَامِنْ عِبَادِنَا ﴾ (فاطر:۳۲)
’’پھر ہم نے ان لوگوں کو (اس)کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں پسند فرمایا۔‘‘
نیز فرمانِ الٰہی ہے:
﴿اُوْلٰٓئِکَ ہُمُ الْوَارِثُوْنَ ٭الَّذِیْنَ یَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ﴾ [المؤمنون]
’’وہ ہی ہیں میراث لینے والے۔جو فردوس کے وارث ہونگے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔‘‘
نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ وَتِلْکَ الجنۃُ الَّتِیْ اُوْرِثْتُمُوْہَا بما کنتم تعملون﴾ (الزخرف:۷۲)
’’یہ وہ جنت ہے جس کے وارث تمہیں بنایا گیا ہے؛ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :
﴿ وَاَوْرَثَکُمْ اَرْضَہُمْ ودیارہم و أرضاً لم تطؤوہا﴾ (الاحزاب: ۲۷)
’’ اور تمہیں ان کی زمینوں اور دیار کا وارث بنایا ؛ اور اس زمین کا بھی جیسے ابھی تم نے نہیں روندا۔‘‘
(یہاں پر وراثت سے مراد بادشاہی وخلافت ارضی ہے)۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :
﴿ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰہِ یُوْرِثُہَا مَنْ یَّشَائُ من عبادہ والعاقبۃ للمتقین ﴾ (الاعراف:۱۲۸)
’’بے شک زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنائے؛ اور اچھا انجام کار اہل تقوی کے لیے ہے۔‘‘
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :
﴿ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ کَانُوْا یُسْتَضْعَفُوْنَ في مشارق الأرض و مغاربہا التي بارکنا فیہا ﴾ (الاعراف: ۱۳۷)
’’ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا؛جس میں ہم نے برکت دی تھی؛ کا وارث اس قوم کو بنایا جس کو ضعیف سمجھا جاتا تھا۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے:
﴿ وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ اَنَّ الْاَرْضَ یَرِثُہَا عِبَادِیَ الصّٰلِحُوْنَ﴾
’’ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک یہ زمین، اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔‘‘(الانبیاء۱۰۵)
محدث ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
’’بیشک انبیاء علیہم السلام کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ علمی ورثہ عطا کرتے ہیں ۔جس نے یہ علمی ورثہ لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ پالیا ۔‘‘[سنن ابی داود۔ کتاب العلم۔ باب الحث علی طلب العلم،(ح:۳۶۴۱) سنن ترمذی۔ کتاب العلم۔ باب ما جاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ (حدیث :۲۶۸۲)،ابن ماجۃ، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم( ح:۲۲۳)]
ایسے ہی خلافت کا لفظ بھی ہے۔ اسی لیے میت کے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خلیفہ کہتے ہیں ۔ یعنی اس نے اپنے ترکہ میں فلاں پیچھے[اپنا خلیفہ ] چھوڑا۔ [اس لحاظ سے ] خلافت کبھی مال میں ہوتی ہے ‘ اور کبھی علم میں ہوتی ہے ‘ اور کبھی ان کے علاوہ دیگر امور میں ۔
جب یہ بات سمجھ میں آگئی تواب سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: ﴿ وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاؤٗدَ ﴾’نیز : ﴿ یَّرِثُنِیْ وَ یَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْب﴾ ان میں لفظ ارث جنس وراثت پر دلالت کرتا ہے ۔مالی وراثت پر دلالت نہیں کرتا۔ پس ان آیات سے خاص طور پر مالی وراثت پر استدلال کرنا مصنف کی وجوہ دلالت سے جہالت کی نشانی ہے ۔
جیسا کہ اگر کہا جائے : یہ شخص اس کا خلیفہ ہوگا۔ اور اس نے اسے اپنے بعد چھوڑا ہو۔ تو اس سے مطلق خلافت پر دلالت ہوتی ہے؛ اس میں کہیں بھی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کے مال کا یا اس کی عورت و اہل خانہ کا یا اس کی املاک کا وراث بنے گا۔
تیرھویں وجہ: ....ہم ان نصوص صریحہ کی روشنی میں کہتے ہیں کہ: زیر تبصرہ آیت میں مالی ورثہ مراد نہیں ، بلکہ علم و نبوت کی میراث مقصود ہے۔ اسی لیے فرمایا: ﴿ وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاؤٗدَ ﴾ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت سلیمان کے سوا حضرت داؤد کے متعدد بیٹے اور بھی تھے، اگر مالی ورثہ مراد ہوتا تو وہ تنہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ ملتا ۔ علاوہ ازیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مالی ورثہ پانے میں کسی کی مدح و ستائش نہیں کی جارہی نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور نہ حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ اس لیے کہ نیک و بد سبھی اپنے والد کا مالی ورثہ پاتے ہیں ؛ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ حالانکہ آیت کا سیاق حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدح اور ان کی خصوصیات کا متقاضی ہے۔ ظاہر ہے کہ مالی میراث ایک عام چیز ہے جو سب لوگوں کے یہاں مشترک ہے؛ جیسے کھانا پینا؛ میت کودفن کرنا ۔ لہٰذا اس طرح کے امور کا انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق ذکر و بیان عبث اور کسی فائدہ سے خالی ہے۔بلکہ وہ چیز بیان کی جاتی ہے جس میں عبرت اور فائدہ ہو۔ وگرنہ کوئی کہنے والا کہے : فلاں انسان مرگیا اور اس کا بیٹا اسکے مال کا وارث بنا ۔‘‘
٭ یہ تو اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے : اسے دفن کیا؛ او رکوئی کہے : انہوں نے کھایا پیا اور سو گئے ؛ یعنی اس طرح کی باتیں جن کا ذکر کرنا [بے موقع اور بے فائدہ ہے] قرآن کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔
اسی طرح زکریا علیہ السلام کے متعلق آیت قرآنی : ﴿ یَرِثُنِیْ وَیَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ﴾ (مریم: ۶)
اس آیت میں بھی مالی ورثہ مراد نہیں ، اس لیے کہ حضرت یحییٰ نے آل یعقوب سے مالی میراث حاصل نہیں کی تھی، بلکہ یہ میراث ان کی اولاد اور دیگر ورثہ نے پائی ہوگی؛ اگر ایسا ہوگا۔[ورنہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مالی وراثت نہیں ہوتی]۔اور نبی اللہ زکریا علیہ السلام نے بیٹا اس لیے طلب نہیں کیا تھا کہ ان کے مال کا وارث بنے۔اس لیے کہ اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو لازمی طور پر یہ مال آپ سے دوسرے لوگوں کو منتقل ہونا ہی تھا خواہ وہ آپ کا بیٹا ہو یا کوئی اور ہو۔نیز یہ کہ اگر اس سے مقصود یہ ہوتا کہ صرف بیٹاہی مالی وارث بنے ؛ تو اس سے لازم آتا کہ بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہ بنے ۔
ایسا کوئی بخیل سے بخیل انسان بھی نہیں کرسکتا ۔اس لیے کہ اگر بیٹا موجود ہو تو اسے دیا جاتاہے۔اس لیے کہ اس کا مقصود ہی بیٹے کو نوازنا ہے۔اور اگربیٹا نہ ہو تو؛ پھربیٹے سے صرف یہ مراد نہیں ہوسکتی کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرایہ مال نہ لے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام مال دار نہ تھے جن کاورثہ حاصل کیا جاتا ۔آپ بڑھئی کا کام کرتے تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیوی مال و متاع سے بے نیاز تھے، لہٰذا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مالی میراث حاصل کرنا خارج از بحث ہے۔مزید برآں آپ کا یہ فرمان بھی ہے:
﴿ وَ اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّ رَآئِ ی﴾ (مریم ]’’اور بیشک میں اپنے پیچھے قرابتداروں سے ڈرتا ہوں ۔‘‘یہ معلوم ہے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد مال کے لینے سے نہیں ڈرتے تھے؛ کیونکہ یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں ۔