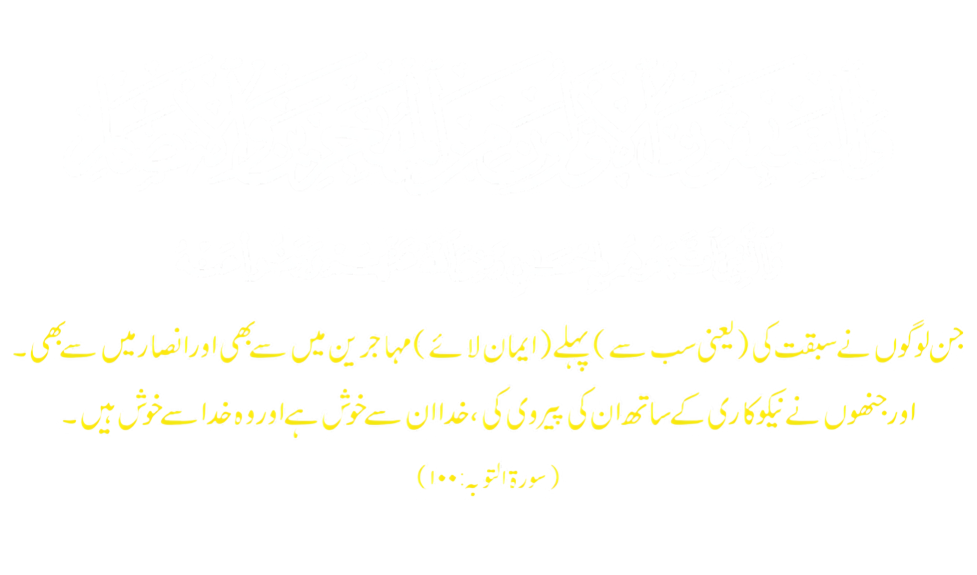فصل:....حضرت علی رضی اللہ عنہ اور علم کلام
امام ابنِ تیمیہؒفصل:....حضرت علی رضی اللہ عنہ اور علم کلام
[اشکال] :شیعہ مصنف لکھتا ہے:’’ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم الکلام کی اصل و اساس ہیں ۔ آپ کے خطبات سے لوگوں نے علم الکلام حاصل کیا۔ لہٰذا لوگ اس فن میں آپ کے شاگرد ہیں ۔‘‘[انتہی کلام الرافضی]
[جواب]:ہم کہتے ہیں : یہ جھوٹ ہے؛ علاوہ ازیں اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس علم الکلام سے پاک رکھا تھا جوکہ کتاب و سنت کی تصریحات کے منافی ہے۔ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو حدوثِ اجسام سے حدوث عالم پر استدلال کرتا ہو۔ نیز حدوثِ اجسام کو اعراض اور حرکت و سکون کی دلیل سے ثابت کرتا اور کہتا ہو کہ اجسام اس کو مستلزم ہیں ۔اس سے علیحدہ نہیں ہوسکتے۔اورجس سے پہلے کوئی حوادث نہ گزر ہوں وہ خود حادث ہے۔اور اس پر ان حوادث کی بنیاد رکھتے ہیں جن کی کوئی انتہاء ہی نہیں ۔ بخلاف ازیں پہلی مرتبہ اس کا اظہار پہلی صدی کے بعد جعد بن درہم اور جہم بن صفوان کی طرف سے ہوا۔ پھر عمرو بن عبید اور[ واصل بن عطاء]ابوہذیل العلاف اور ان کے امثال نے اس میں حصہ لیا۔عمرو بن عبید اور واصل بن عطاء ان دونوں نے جب انفاذ و عیدمیں علم کلام کا اظہار کیا کرتے تھے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جو انسان جہنم میں داخل ہوگیا تو پھر وہ وہاں سے کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ اور تقدیر کا انکار کرنے لگے۔ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پاک رکھا تھا۔
جو خطبات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں ، ان میں معتزلہ کے اصول خمسہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو بھی باتیں منقول ہیں ‘ وہ سب آپ پر جھوٹ ہیں ۔ متقدمین معتزلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعظیم نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت و ثقاہت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے۔ جنگ جمل کے لڑنے والوں کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے:
’’فریقین میں سے ایک فاسق ہے، مگر متعین طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔‘‘یا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں یا پھر حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما ۔اور جب ان میں سے کوئی ایک گواہی دے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ۔ جب کہ اکیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گواہی کے بارے میں ان کے دو قول ہیں ۔ یہ قول عمرو بن عبید اور ان جیسے دوسرے معتزلہ کے ہاں معروف ہے۔‘‘[ابن طاہر بغدادی اپنی کتاب ’’ اصول الدین ‘‘ص ۲۹۰ میں فرماتے ہیں :واصل بن عطاء ‘ عمرو بن عبید اور نظام اور اکثر قدریہ کہتے ہیں کہ : ہم انفرادی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور انکے اصحاب سے محبت کرتے ہیں ؛ اور طلحہ و زبیر اوران کے متبعین سے بھی انفرادی طور پر ولاء کااظہار کرتے ہیں ۔اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیساتھ انکی جماعت کا ایک آدمی گواہی دے تو اس کی گواہی مان لیں گے ‘اورایسے ہی طلحہ و زبیر کے ساتھ بھی اگر ان کی جماعت کا کوئی آدمی گواہی دیدے تو ہم مان لیں گے۔ لیکن اگر طلحہ اور علی رضی اللہ عنہما اکیلے باگلے کی ایک بالی پر بھی گواہی دیں تو تب بھی اسے نہیں مانیں گے۔ اس لیے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک فاسق ہے۔ فاسق دائمی جہنمی ہوتا ہے ‘وہ نہ ہی مومن ہے او رنہ ہی کافر۔دیکھیں : ابو الحسن أشعری کی کتاب : مقالات اسلامیین ۲؍۱۴۵۔]
متأخرین شیعہ کے برعکس تمام متقدمین شیعہ ہاشمی اور دوسرے لوگ ؛صفات الٰہی اور مسئلہ تقدیر کے قائل تھے۔ متاخرین شیعہ نے صراحت کے ساتھ تجسیم کے عقیدہ کا اظہار کیا تھا؛ اور اس بارے میں ان سے انتہائی برے اقوال نقل کیے گئے ہیں ۔جب کہ ان کا دعوی ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ اہل بیت سے اخذ کیا ہے۔ [علامہ اشعری نے اپنی کتاب ’’ مقالات الاسلامیین ‘‘ ۱؍۱۰۶میں مسئلہ تجسیم میں روافض کے عقائد ذکر کیے ہیں اورانہیں چھ اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پھر ان کے بارے میں کہاہے : ’’ توحید میں یہ لوگ معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ رکھتے ہیں ۔یہ ان کے متأخرین شیعہ کا عقیدہ ہے۔ جب کہ ان کے اولین تشبیہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ جب کہ اعمال العباد کے بارے میں ایک گروہ ہشام بن حکم کا عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان کی افعال ایک طرح سے اختیاری ہیں اور ایک طرح سے اضطراری ۔ اور دوسرا گروہ جہمیہ کا عقیدہ رکھتا ہے کہ : اعمال میں کوئی جبر نہیں ؛ اور نہ ہی تفویض ہے جیسے کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے ۔جب کہ تیسرے گروہ کا عقیدہ ہے کہ اعمال اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہیں ۔یہ لوگ معتزلی بھی ہیں اور امامت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں ۔]
امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ: قرآن خالق ہے یا مخلوق ؟ تو انھوں نے فرمایا:
’’وہ نہ ہی خالق ہے اور نہ ہی مخلوق؛ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔‘‘
[واصل بن عطاء اور محمد بن حنفیہ کی شاگردی]
رہا رافضی کا یہ قول کہ : ’’ واصل بن عطاء نے ابو ہاشم بن محمد بن الحنفیہ سے علم حاصل کیا تھا۔‘‘
[اس کا جواب یہ ہے کہ]: اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن بن محمد بن حنفیہ [حسن بن محمد بن حنفیہ نے سب سے پہلے مسئلہ ارجاء پر کتاب لکھ کر قدریہ وغیرہ کا رد کیا ہے۔ [سزکین م۱؍ج۴؍ص ۱۵]۔ ]نے معتزلہ کے قول کے برعکس ’’ارجاء ‘‘ کے مسئلہ پر ایک کتاب تالیف کی تھی۔کئی اہل علم نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس معتزلی مذہب سے متناقض ہے ؛ جس کا اظہار واصل بن عطاء کیا کرتا تھا۔اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ :اس نے ابو ہاشم سے علم حاصل کیا تھا۔[ابو ہاشم عبداللہ بن محمدبن علی بن ابی طالب۔ ابن حجر رحمہ اللہ تہذیب التہذیب ۶؍۱۶ پر آپ کے حالات زندگی تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں : امام زہری فرماتے ہیں :’’ عبد اللہ اور حسن دونوں محمد بن علی [المعروف ابن حنفیہ ] کے بیٹے ہیں ۔ان دونوں میں سے حسن زیادہ ثقہ راوی تھا۔ ابو اسامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :’’ ان میں سے ایک مرجئی تھا او ردوسرا شیعہ ۔‘‘ اور ابن حجر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ : حضرت زبیر فرماتے ہیں :’’ ابو ہاشم شیعوں کا ساتھی تھا۔‘‘ اور یہ بھی کہاہے کہ : ’’ عبداللہ سبائیت کی روایات جمع کیا کرتا تھا۔‘‘]
اس ابو ہاشم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے ایک کتاب تصنیف کی تھی جس پر انکار کیا گیا ؛نہ ہی اس کے بھائیوں نے اس پر موافقت کی اور نہ ہی اہل بیت نے۔اورنہ ہی اس نے اپنے والد سے علم حاصل کیا تھا۔
خواہ کچھ بھی ہو‘ وہ کتاب جو حسن کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ اس کتاب کے متناقض ہے جو ابو ہاشم کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ یہ بھی کہاگیا ہے کہ :اس نے اس کتاب سے رجوع کرلیا تھا۔ اور یہ بات ممتنع ہے کہ ان دونوں نے یہ متناقض علوم اپنے والد محمدبن الحنفیہ سے حاصل کیے ہوں ۔ محمد کی طرف ان دومیں سے ایک کتاب کی نسب زیادہ مناسب ہے۔ پس اس سے قطعی طور پر یہ باطل ثابت ہوگیا محمد بن حنفیہ ایک ہی وقت میں دو مختلف عقائد کے قائل نہیں ہوسکتے۔ بلکہ یہ بات دو ٹوک اور قطعی یقینی ہے کہ محمد مرجئہ کے عقیدہ سے برأت کے ساتھ ساتھ معتزلہ کے عقیدہ سے بھی اس سے بڑھ کر بری ہیں ۔اور ان کے والدحضرت علی رضی اللہ عنہ مرجئہ اورمعتزلہ سے اس سے بڑھ کر بری ہیں ۔
جب کہ ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ علی جبائی کے شاگرد تھے؛ مگر انھوں نے جبائی کو چھوڑ دیا تھا ؛ اور اس کے مذہب سے جملہ طور پر رجوع کرلیا تھا۔ اگرچہ آپ کے ہاں ان کے مذہب کے اصولوں کی کچھ بقایا رہ گئی تھیں ۔لیکن آپ نے نفی صفات کے مسئلہ میں ان کی مخالفت کی ؛ اور ابن کلاب کے مذہب پر گامزن ہوگئے۔ اور قدر‘ ایمان اوراسماء و احکام کے مسائل میں ان کی مخالفت کی؛اورحسین بن نجار اورضرار بن عمرو کے رد سے بڑھ کر ان کارد کیا؛ حالانکہ یہ دونوں حضرات اس باب میں جمہور فقہاء اور جمہور محدثین کی طرح متوسط شمار کیے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اس مسئلہ میں جہم کے عقیدہ کی طرف مائل ہوگئے ‘ مگر وعید کے مسئلہ پر ان کی مخالفت کی۔ پھر اہل سنت و الجماعت کا مذہب اختیار کیا اور اپنے آپ کو اہل سنت و محدثین کے مذہب کی طرف منسوب کرنے لگے جیسے احمد بن حنبل اور ان کے امثال رحمہم اللہ ؛ اور اسی عقیدہ کی مناسبت سے لوگوں میں مشہور بھی ہوئے۔آپ کے مذہب میں سے جس قدر عقیدہ کی تعریف کی گئی ہے ‘ وہ وہی ہے جو اہل سنت محدثین کے موافق ہے ؛ جیساکہ جامع جملے ۔اورجس قدر عقیدہ کی مذمت کی گئی ہے ؛ وہ جو مخالفین محدثین اہل سنت معتزلہ ‘ مرجئہ اور جہمیہ و قدریہ کے مذہب کے موافق ہے۔
آپ نے بصرہ میں زکریا بن یحییٰ ساجی[ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ بن عبدالرحمن بن محمد بن الضبي البصری الساجي اپنے زمانہ میں بصرہ کے سب سے بڑے محدث تھے۔حافظ اور ثقہ تھے۔ ۲۲۰ہجری میں پیدا ہوئے ۳۰۷ہجری میں وفات پائی ۔ الاعلام ۳؍۸۱۔ ] سے حدیث و سنت کا علم حاصل کرنا شروع کیا تھا۔پھر بغداد میں امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے اصحاب اور دوسرے لوگوں سے علم حاصل کیا۔ امام اشعری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب’’ مقالات الاسلامیین‘‘ میں لکھا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت محدثین کے مشرب و مسلک پر ہیں اور کہا ہے : ’’ہم نے جتنے بھی اعتقادات ذکر کیے ہیں ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور اس مذہب پر عمل پیرا ہیں ۔‘‘
یہ مذہب جہمیہ اور قدریہ کے مذہب سے بہت دور ہے۔
[ معجون مرکب شیعہ مذہب]:
جب کہ رافضہ شیعہ-جیسا کہ ابن مطہر اوراس کے امثال متاخرین امامیہ -کا مذہب ایک اچھا خاصہ معجون مرکب ہے۔ انکار صفات باری میں انھوں نے جہمیہ کا مذہب اختیار کیاہے۔ افعال العباد کے مسئلہ میں وہ قدریہ کے پیرو ہیں ۔ امامت و تفضیل کے مسائل میں وہ روافض کے زاویہ نگاہ کے متبع ہیں ۔ اس سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کردہ علم کلام آپ پر صاف جھوٹ ہے؛مزید براں اس میں مدح کاکوئی عنصرشامل نہیں ۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ پر عظیم ترین افتراء تویہ ہے کہ قرامطہ و اسماعیلیہ اپنے عقائد و افکار کوآپ کی جانب منسوب کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ کو باطنی علم دیا گیا تھا؛ جو کہ علم ظاہر کے خلاف تھا۔صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:’’اس ذات کی قسم جس نے نباتات کو اگایا اور سب مخلوقات کو پیدا کیا! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا جو باقی لوگوں سے نہ لیا ہو۔سوائے اس کے جو کچھ آپ نے فرمایا تھا وہ میرے اس صحیفہ میں درج ہے۔اس کتاب میں :دیت‘قیدیوں کی رہائی کامسئلہ تھا اوریہ کہ کافر کے بدلہ میں مسلمان کوقتل نہیں کیا جائے گا؛ البتہ اللہتعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو کتاب اللہ کا فہم عطا کردے تو وہ ایک الگ بات ہے۔‘‘[البخاری ۔ کتاب الجہاد۔ باب فکاک الاسیر(ح:۳۰۴۷)،مسلم، کتاب الحج، باب فضل المدینۃ (ح:۱۳۷۰)۔الترمذي کتاب الدیات ‘باب: ماجاء لا یقتل مسلم بکافر۔]
اب لوگوں میں سے بعض ’’الحوادث ‘‘کو آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں ‘اور بعض دوسرے’’ جفر ‘‘کو۔کچھ دوسرے ’’بطاقہ ‘‘ اور دیگر علوم کو آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ جن کے بارے میں یہ بات یقینی علم کیساتھ معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بری ہیں ۔ ایسے ہی حضرت جعفر صادق پر اتنے جھوٹ باندھے گئے ہیں جن کی حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی طرف علم نجوم کے احکام ‘رعود ‘ بروق اور قرعہ منسوب کیے گئے ہیں جو حقیقت میں پانسہ بازی کی ہی ایک قسم ہے۔ آپ کی طرف ’’منافع سورالقرآ ن ‘‘ نامی کتاب بھی منسوب کی گئی ہے۔ اوران کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں علماء جانتے ہیں کہ حضرت جعفر رحمہ اللہ اس سے بری ہیں ۔ یہاں تک کہ آپ کی طرف مختلف انواع کی تفسیر بھی منسوب کی گئی ہے جو کہ باطنیہ کے طریقہ پر ہے۔ جیسا کہ ابو عبد الرحمن سلمی نے اپنی کتاب ’’حقائق التفسیر‘‘ میں ذکر کیا ہے۔ اور اس نے وہاں پر اس تفسیر کے کچھ قطعات بھی بطور نمونہ ذکر کیے ہیں ۔یہ حقیقت میں کلمات قرآن میں تحریف؛اور اللہ تعالیٰ کی مراد کو تبدیل کرناہے۔ آپ کے علوم کی معرفت رکھنے والا ہر انسان جانتا ہے کہ آپ ان اقوال و عقائداورکتاب اللہ کی تفسیر میں جھوٹ سے بری تھے۔ او رایسے ہی بعض لوگوں نے آپ کی طرف ایک اور کتاب بھی منسوب کی ہے جسے ’’رسائل إخوان الکدر‘‘ کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے دو سو سال بعد سے زیادہ عرصہ بعد لکھی گئی ہے۔ جعفر صادق کا انتقال سن ایک سو اڑتالیس ہجری میں ہوا ہے۔ او ریہ کتاب ’’عبیدی باطنی اسماعیلی ‘‘دور حکومت میں اس وقت لکھی گئی جب یہ لوگ مصر پر غالب آگئے اور قاہرہ شہر آباد کیا۔ یہ ایسے لوگوں کی تصنیف ہے کہ فلسفہ و شریعت اور شیعیت کو ایک ہی جگہ جمع کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ ان عبیدیوں کا مسلک تھا۔ جن کا دعوی تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں ۔ نسب کے ماہرین اہل علم جانتے ہیں کہ یہ نسب باطل[اور جھوٹ] ہے۔
جب کہ ان کا دادا ظاہری اور باطنی طور پر یہودی تھا؛ان کا سوتیلادادا مجوس میں سے تھا۔ اس نے ایک یہودیہ عورت سے شادی کرلی تھی۔یہ ان کا یہودی دادا اس مجوسی کے پاس لے پالک تھا۔ ان کی نسبت باہلہ کی طرف تھی۔ حالانکہ یہ لوگ باہلہ کے موالین میں سے تھے۔ پھر انہوں نے یہ دعوی کیا کہ وہ محمد بن اسماعیل بن جعفر کی اولاد میں سے ہے۔ اسماعیلیہ کو اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کا دعوی ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے اثنا عشریہ کے ساتھ نہیں ۔اس لیے کہ اثنا عشریہ موسیٰ بن جعفر کی امامت کے دعویدار ہیں ۔ جب کہ یہ لوگ اسماعیل بن جعفر کا کہتے ہیں ۔
ان کے ائمہ باطن میں زندیق اورملحدین ہیں جو کہ غالیہ فرقہ میں سے سب سے برے لوگ ہیں ۔اثنا عشریہ کی جنس میں سے نہیں ہیں ۔لیکن انہیں اس فاسد مذہب اور نسبت پر لگانے والے اثنا عشریہ اور ان کے امثال کے کرتوت ہیں ۔ان لوگوں نے اس فرقہ پر جھوٹ بولے تو جواب میں انہوں نے وہی جھوٹ بلکہ اس سے زیادہ ان پر بہتان گھڑے ۔ اثنا عشریہ نے ان کو ملحد کہا تو انہوں نے جواب میں انہیں جہمیہ اورقدریہ وغیرہ کہا۔
جب یہ اسماعیلیہ و نصیریہ ملاحدہ او ران کے امثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں ‘حالانکہ وہ طرقیہ عشریہ اور دوسرے لوگوں کی طرح ہیں ؛ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایسی باتیں بھی منسوب کرنے لگے جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منزہ و مبرا رکھا ہے۔[اہل بیت پر جو جھوٹ باندھا گیا ہے وہ بیان سے باہر ہے]۔یہاں تک کہ شیعہ چور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خط میں ان کولوگوں کے اموال چوری کی اجازت دی ہے۔ جس طرح یہودخیابرہ اس بات کے مدعی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک خط کے ذریعہ ان کا جزیہ معاف کردیا تھا۔اور ان کے اموال کا عشر ان کے لیے مباح کردیا تھا۔ان کے علاوہ بھی دیگر ایسے امور ہیں جو دین اسلام کے خلاف ہیں ۔[ کیا اس سے زیادہ گمراہی کا بھی امکان ہے؟]
تمام علماء کرام رحمہم اللہ کا اجماع ہے کہ یہ تمام باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھی گئی ہیں ۔آپ ایسی باتوں سے لوگوں میں سب سے زیادہ بری ہیں ۔ پھر اس پر بھی حد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر گھڑے گئے بہتانوں کو اپنے تئیں ان کی مدح شمار کرتے ہیں ۔اوران کی وجہ سے انہیں سابقہ خلفاء راشدین پر فضیلت دیتے ہیں ۔اور ان خلفاء کے ان خرافات سے پاک ہونے کو ان کی ذات میں عیب شمار کرتے ہیں ۔ اور اس وجہ سے ان سے بغض رکھتے ہیں ۔یہاں تک کہ باطنیہ کے سرغنے جو اپنے عقائد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب کرتے ہیں ، ان کا عقیدہ ہے کہ اسلام کا مقصد و غایت صرف اس بات کا اقرار ہے کہ افلاک ربوبیت کے مرتبہ پر فائز اور مدبر عالم ہیں ۔ ان کے سوا اور کوئی ان کا بنانے اور پیداکرنے والا نہیں ۔ ان کے خیال میں یہ دین اسلام کا باطنی پہلو ہے جس کو دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا یہ باطنی پہلو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خواص کو اس کی تعلیم دی۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ محمد بن اسماعیل بن جعفر تک پہنچا جن کو وہ ’’ القائم‘‘ کہتے ہیں ۔انکے ہاں اسکی حکومت اب بھی قائم ہے۔اور یہ کہ محمد بن عبداللہ [رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ]کی شریعت منسوخ ہوچکی ہے۔ اب امام پر ان خفیہ تاویلات کو ظاہرکرنا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لیکر امام تک رازہی چلی آرہی ہیں ۔
یہ لوگ اپنے خاص اصحاب سے نماز‘ زکواۃ ‘ روزہ اور حج کو ساقط قرار دیتے ہیں ۔ اور محرمات‘ فواحش اور منکرات کو مباح سمجھتے ہیں ۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے علماء مسلمین نے مختلف معروف کتابیں تألیف فرمائی ہیں جن سے ان کی حقیقت بیان ہوتی ہے او رتمام رازوں سے پردے اٹھتے ہیں ۔اس لیے کہ ان علماء پر ان لوگوں کے دین و دنیا کا فساد ظاہر ہوگیا تھا۔ جن علماء کرام نے ان کے بارے میں کتابیں لکھیں اور ان کے اسرار ظاہر کیے ان میں قاضی ابوبکر رضی اللہ عنہ بن الطیب و قاضی عبد الجبار بن احمد و قاضی ابویعلی و غزالی و ابن عقیل و ابو عبد اللہ شہرستانی رحمہم اللہ کے نام شامل ہیں ۔ ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی اس کام میں حصہ لیا ہے۔
یہ وہی ملحدین کا گروہ ہے جو مشرق و مغرب؛ شام اور یمن کے علاوہ دیگر متعدد مواقع پر ظاہر ہوئے۔ قلعہ الموت [اصحاب الموت چند ملحد شخص تھے۔ ان میں آخری شخص رکن الدین تھا۔ انھوں نے ۴۷۳ھ سے ۶۵۴ھ تک قلعہ الموت میں اسماعیلی فرقہ کی بنیاد رکھی اور اس کی نشرو اشاعت میں لگے رہے،یہ قلعہ طہران و نیشا پور کے درمیان واقع تھا۔ اسماعیلی ملاحدہ کے ہاں دو اور قلعے بھی تھے۔ ان کا نام کرد کوہ۔ میمون ذر تھا۔ حاکم الموت کو شیخ الجبل کہا کرتے تھے، ہلاکو خاں نے ۶۵۴ھ میں اسماعیلیہ کا خاتمہ کردیا تھا۔ ملحد اسماعیلیہ کا آخری شیخ الجبل اٹلی کے مشہور سیاح مارکوپولو کے زمانہ تک بقید حیات تھا۔ مار کوپولو نے شیخ الجبل کی جنت اور اس کے جرائم کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔’’مواقف حاسمۃ‘‘ص : ۲۲۱۔ ۲۲۳۔نیز ملاحدہ کی تفصیلات کے لیے دیکھیے ’’الحوادث الجامع لابن الفوطی‘‘ص: ۳۱۲ ۔ ۳۱۳، نیز ’’مختصر الدول لابن العبری‘‘ (ص:۴۶۲)، و عمدۃ الطالب (ص:۲۱۱)، تاریخ العراق بین احتلالین (۱؍۱۵۰۔۱۵۴)۔]
والے باطنیہ ہی میں سے تھے۔ [سنان ان کا داعی تھا]۔
[یہ بظاہر شیعہ مگرباطن میں ملحد و زندیق ہوتے ہیں ]۔ یہ شیعہ کی راہ سے مسلمانوں میں داخل ہوئے اور دین اسلام میں سب سے بڑا بگاڑ پیدا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باطنیہ حد درجہ جاہل خواہش پرست اور دین اسلام سے بیگانہ ہوتے ہیں ۔یہی وجہ تھی کہ انھوں نے اپنے داعیوں کو نصیحت کی تھی کہ تشیع کے دروازے سے مسلمانوں کے یہاں داخل ہوں ۔ یہ شیعہ کے اکاذیب و اہواء سے فائدہ اٹھاتے اوروقت یاجگہ کی مناسب سے ان پر خاطر خواہ اضافہ کیا کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا وہ بت پرست اورعیسائی بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔حقیقت میں ان کا دین فرعون کا دین ہے جو کہ یہود و نصاری اور بت پرستوں کے دین سے بھی برا ہے۔
ان کی دعوت کی ابتداء شیعیت سے ہوتی ہے اورانتہاء اسلام کے مسخ کرنے پر۔بلکہ انسان کو تمام ملتوں سے نکال دیتے ہیں ۔جو انسان اسلام کے احوال اور اس میں لوگوں کے مذاہب ومسالک کے بارے میں سے کچھ جانتا ہو وہ لازمی طور پر ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ کچھ نہ ضرورجانتا ہی ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق ہے جوکہ صحیح بخاری ومسلم میں مذکورہے۔ [حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ]: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
’’تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی(ایسی زبردست پیروی کرو گے)حتی کہ( ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز پر)یعنی ذرا سا بھی فرق نہ ہوگا۔حتی کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہو گے ہم نے عرض کیا :یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم !کیا یہود و نصاری مراد ہیں ؟آپ نے فرمایا:’’نہیں تو پھر اور کون مراد ہو سکتا ہے۔‘‘ [صحیح بخاری:ح 684]
ایک دوسری متفق علیہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
’’ میری امت ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز پرسابقہ امتوں کی راہوں پر چلے گی ۔‘‘ صحابہ نے عرض کیا :
یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! کیا اہل فارس اوراہل روم کی راہوں پر ؟ توآپ نے فرمایا: ’’ کیا ان کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ بھی ہیں ۔‘‘ [سبق تخریجہ]
یہ بات بعینہ ان لوگوں میں ہے جو اپنے آپ کو شیعیت کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ بلاریب اسماعیلیہ نے اپنا مذہب اہل فارس سے لیا ہے ۔جن کے عقیدہ کے دواصول ہیں : نور اورظلمت۔انکے علاوہ دیگر واہیات باتیں بھی ہیں ۔ اور کچھ چیزیں اہل روم نصاری کے مذاہب سے لی ہیں ۔ اورکچھ نصرانیت سے پہلے اہل یونان کے مذہب کی چیزیں ہیں ؛ جیسا کہ نفس اور عقل کا عقیدہ اوراس طرح کے دوسرے امور۔ انہوں نے ان سب چیزوں کو آپس میں ملاکر اس کے لیے ایک نیا اصطلاحی نام رکھا: ’’السابق والتالی۔‘‘[یعنی گزشتہ اور آنے والا]۔ اور پھر اسے لوح و قلم قرار دیا۔
کہتے ہیں : قلم ہی عقل ہے۔ اور یہی سب سے پہلی تخلیق ہے۔ اس پر وہ اس حدیث نبی سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ : سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا پھر اس سے کہا حاضر ہوجاتووہ حاضر ہوگیا۔پھر کہا: پلٹ جا تو وہ پلٹ گیا۔ پھر فرمایا:
’’مجھے اپنی عزت کی قسم!میں نے کبھی اپنے نزدیک تجھ سے مکرم کوئی مخلوق پیدا نہیں کی ۔ پس میں تجھ سے ہی (حساب) لوں گا۔ اورتیرے سبب سے ہی دوں گا۔ اورثواب و عقاب بھی تجھ پر ہی منحصر ہوگا۔‘‘
یہ حدیث بعض ان لوگوں نے روایت کی ہے جنہوں نے عقل کے متعلق کتابیں لکھی ہیں جیسے داد بن محبراور دوسرے لوگ۔یہ موضوع روایت ہے جو کہ نبی کریم پر جھوٹ گھڑ لیا گیا ہے۔ محدثین اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جیسا ابوحاتم بن حبان البستی دار قطنی ابن جوزی [ابن جوزی نے اپنی کتاب ’’الموضوعات‘‘۱؍۱۷۴ پر اس روایت کو مختلف اسانید سے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:’’ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کیساتھ ثابت نہیں ہوتی۔یحیٰ بن معین فرماتے ہیں : ’’فضل انتہائی برا انسان تھا۔‘‘ اورابن حبان فرماتے ہیں : ’’ حفص بن عمرو جھوٹی احادیث روایت کیا کرتا تھا۔ اس کی روایات سے استدلال کرنا حلال نہیں ہے۔ جب کہ سیف نامی راوی کے جھوٹا ہونے پر سب کا اجماع ہے۔ پھر انہوں نے ۱؍۱۷۵ پر ایک دوسری سند سے یہ روایت نقل کرتے ہوئے کہا ہے: یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور پھر امام دار قطنی کا قول نقل کیا ہے ؛ آپ فرماتے ہیں : عقل پر چار لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ۔ان میں سے پہلا انسان مسیرہ بن عبدربہ ہے۔ پھراسی سے مواد چرا کر اور اس کے ساتھ اسناد ملاکر داؤد بن محبر نے تالیف کی۔ پھر اس سے عبد العزیز بن ابی رجاء نے مواد چرایا اور اس کے ساتھ ایک دوسری قسم کی اسناد ملا کر روایت کیا ۔ پھر یہی کام سلیمان بن عیسی سجزی نے کیا۔ دیکھیں : المقاصد الحسنۃ للسخاوی ص۱۱۸۔ الموضوعات للقاری ۳۷۔]اور دوسرے علما کرام رحمہم اللہ نے وضاحت کیساتھ بیان کیاہے۔ لیکن یہ روایت ان لوگوں کی خواہشات کے موافق تھی تو اپنی عادت کے مطابق اس سے استدلال کرنے لگے۔حالانکہ احادیث کے الفاظ ان کے مذہب کے خلاف ہیں ۔ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ میں ول حرف لام پر زبر کیساتھ وارد ہوا ہے۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ:’’ لما خلق اللّٰہ العقل۔‘‘ یعنی:’’ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا‘‘ تو اس سے یہ بات اس کی پیدائش کی بعدشروع کے اوقات میں ہی کہی۔اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو جب پیدا کیا تو اس وقت اسے مخاطب بھی کیا ۔اس سے یہ مراد نہیں کہ عقل سب سے پہلے پیدا کی گئی ۔ ہی وجہ ہے کہ اس سے خطاب میں یہ بھی کہا گیا کہ:’’ ما خلقت خلقاً أکرم عليَّ مِنک۔‘‘
’’ میں نے اپنے لیے تجھ سے بڑھ مکرم مخلوق نہیں پیدا کی۔‘‘
اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دوسری مخلوقات بھی پیدا کی تھیں ۔ اورپھر اس کا وصف بیان فرمایا کہ: عقل آگے بڑھتی ہے اور پیچھے ہٹتی ہے۔زنادقہ کے ہاں عقل اول پر یہ بات ممتنع ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا ہے:
’’بکِ آخذ، وبکِ أعطِی، وبِک الثواب بک العقاب۔‘‘
’’ پس میں تجھ سے ہی(حساب) لوں گا۔ اورتیرے سبب سے ہی دوں گا۔ اورثواب و عقاب بھی تجھ پر ہی منحصر ہوگا۔‘‘
ان کے نزدیک تو عقل تمام جہان کی پروردگار اور رب عالم ہے۔اور وہی تمام چیزوں کو بغیر کسی مثال سابق کے پیدا کرنے والی ہے۔یہی پہلی علت ہے ۔اعراض اربعہ اس کے ساتھ خاص نہیں ۔ بلکہ عقل ان کے نزدیک تمام جواہر:علویہ و سفلیہ حسیہ اور عقلیہ کی مبدع ہے۔
جبکہ مسلمانوں کی زبان میں :عقل وہ عرض ہے جو دوسری چیز کیساتھ قائم ہے۔ یا پھر عقل قوت نفس کانام ہے۔
عقل کا مصدر: عقل یعقِل عقلاًہے؛ جبکہ عاقل کو ان کی زبان میں عقل نہیں کہا جاسکتا۔ ان(زنادقہ)کی اصطلاح میں عقل ایسا جوہر ہے جو بذات خود قائم ہے۔ ہم نے اس نکتہ پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ اورمعقول ومنقول میں ان کی واضح کی ہے۔ یہ لوگ عند التحقیق مفارقات میں سب سے پہلے جس چیزکوثابت کرتے ہیں وہ اعیان و اذہان میں نفس ناطقہ کا وجود ہے۔اور اس کی بعض صفات بیان کرنے میں بھی خطا کے مرتکب ہوئے ہیں ۔
ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ: عالم علت ازلیہ قدیمہ واجب الوجود سے معلول ہے۔ اوربلاریب اس عالم کے لوازم بھی ہیں ۔لیکن ان کے عقیدہ کی حقیقت یہ ہے کہ :یہ ایک علت غایت ہے۔ اورافلاک کی حرکت اس سے مشابہت کے لیے ارادی وشوقی حرکت ہے۔اوریہی شوق اس کا محرک ہے۔ جیساکہ محبوب اپنے محب کی مشا بہت میں حرکت میں آتا ہے تاکہ اسے محب سے تشبیہ حاصل ہوجائے۔ ایسی چیز کا اس کے تصور و ارادہ اور حرکت کے مطابق محدث ہونا واجب نہیں ہوتا۔حرکت فلک میں ان کا عقیدہ قدریہ کے افعال حیوانات میں عقیدہ کی جنس سے ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں : فلک کی حرکت ہی حوادث کا سبب ہوتی ہے۔ ان کے اس قول کی حقیقت یہ ہے کہ:اصل میں یہ تمام حوادث بغیر کسی محدث کے وجود میں آتے ہیں ۔اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتے اور ہر مقام کے لیے اس کے مناسب مقال بھی ہوتا ہے۔
ان لوگوں نے وجود اور اس کے لواحق میں علم باطن کوعلم اعلی اور فلسفہ اولی قرار دیا ہے۔ اوروجود کو جوہر و عرض میں تقسیم کیا ہے۔ پھر اعراض کو نو اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو انہیں صرف پانچ اقسام قراردیتے ہیں ۔اور بعض نے صرف تین اقسام تسلیم کی ہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے صحیح اعداد و شمار پر کوئی دلیل موجود نہیں ۔ نیز انہوں نے جواہر کو بھی ان پانچ انواع میں تقسیم کیا ہے:
1۔عقل 2۔ نفس 3۔ مادہ 4۔ صورت 5۔جسم
واجب الوجود کوکبھی کبھی جوہر کا نام دیتے ہیں ۔یہ ان کی قدما کا عقیدہ ہے۔ جیسے ارسطو وغیرہ۔ اور کبھی یہ نام نہیں بھی دیتے جیسا کہ ابن سینا کا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ ابن سینا کا عقیدہ ہے۔ ان کے قدما اپنے دل میں عقلی امور میں تصور کرتے تو پھر خارج انہیں ثابت بھی خیال کرنے لگتے۔ جیسا کہ فیثاغورس اور افلاطون کی جماعت سینقل کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے خارج میں کچھ مجرد اعداد کو ثابت مانا ہے۔ اور اول الذکر لوگوں نے افلاطونی امثال کو ثابت کیا ہے۔ یہ اعیان سے خالی کلیات ہیں اورایسے ہی انہوں نے مجرد مادہ کو ثابت مانا ہے۔ اسے ہیولی اولی کہتے ہیں ۔ اورپھرمجرد مدت کو ثابت مانا ہے۔یہ عقلی زمانہ ہے جو کہ جسم اوراعراض سے خالی ہے۔ ایسے ہی جسم واعراض سے خالی فضا کو بھی یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں ۔
اس مسئلہ میں ارسطو اور اس کے متبعین نے اپنے اسلاف کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی مجرد نہیں ۔لیکن اس کے برعکس صورت کے لیے مادہ مقارنہ کو تسلیم کیا اور ثابت مانا ہے۔ اور اعیان کے مقارن کلیات کوبھی ثابت مانتے ہیں ۔ نیز انہوں نے دس عقول کو ثابت مانا ہے۔ جب کہ خود اکثر فلکیہ اسے جسمانی قوت مانتے ہیں ۔ان میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جوہر ہے جو بذات خود ایسے ہی قائم ہے جیسے انسانی نفس۔
لفظ صورت سے کبھی تو ان کی مراد عرض(اصل جسم)ہوتی ہے اور کبھی وہی مصنوعی صورت ۔جیسے کا چارپائی انگوٹھی اور تلوار کی شکل ۔ یہ عرض اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور مادہ سے بھی یہاں پر مراد جوہر ہے جو کہ بذات خود قائم ہے ۔اور کبھی صورت سے مراد قدرتی صورت اور مادہ سے قدرتی مادہ مراد لیتے ہیں ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حیوانات معادن اور نباتات کی بھی ایک صورت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ مادہ سے پیدا کیے گئے ہوتے ہیں ۔لیکن صورت سے ان لوگوں کی مراد بذات خود قائم جوہر ہوتا ہے۔ اورمادہ سے مراد ایک دوسرا جوہر ہوتاہے جو کہ اس پہلے جوہر کے قریب تر ہوتا ہے۔ جب کہ ان کے مقابلہ میں اہل کلام جو کہ منفرد جوہر کا عقیدہ رکھتے ہیں ۔ ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی حادث ایسا نہیں ہے جس کا ظہور پذیر ہونا مشاہدہ سے معلوم ہوا ہو مگروہ عرض ہوتا ہے۔ اوریہ کہ وہ جواہر میں سے کسی بھی جوہر کے حدوث کا مشاہدہ کرتے ہیں ۔ یہ دونوں قول خطا پر مبنی ہیں اور اس بارے میں ہم اپنی جگہ پر تفصیل سے کلام کرچکے ہیں ۔
کبھی مادہ سے مرادہ مادہ کلیہ ہوتا ہے جو کہ اجسام کے مابین مشترک ہوتاہے۔اور صورت سے مراد بھی صورت کلی ہوتی ہے جوکہ اجسام میں مشترک ہوتی ہے۔اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ یہ دونوں عقلی جوہر ہیں ۔حالانکہ ایسا کہنا غلط ہے۔ اس لیے کہ اجسام کے مابین مشترک چیز امر کلی ہے۔ اور کلیات توصرف اذہان میں پائے جاتے ہیں اعیان میں نہیں ہوتے۔ اور ہر وہ چیز جو خارج میں اپنا وجود رکھتی ہو اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے دوسروں سے ممیز اورجدا اوراس میں کوئی دوسرا شریک بھی نہیں مگر وہ جب کلیہ کے اعتبار سے اخذ کی جائے تو ذہن میں بھی موجود ہوتی ہے۔
اجسام میں اتصال اورانفصال پایا جاتا ہے۔ یعنی ان میں اجتماع اورافتراق ہوتا ہے۔ اوروہ دونوں اعراض ہیں ۔ انفصال کوئی ایسی چیز نہیں جو بذات خود قائم ہو۔جیساکہ حرکت بذات خود قائم کوئی چیز نہیں سوائے اس محسوس جسم کے جس پر اتصال و انفصال واقع ہوتا ہے۔ اسے ہیولیٰ اور مادہ کا نام دیتے ہیں ۔ان امور کو دوسرے مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان کردیا گیا ہے۔
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے اور دوسرے لوگوں کے اقوال کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور نہ ہی انہیں رسولوں کے لائے ہوئے پیغام کی کوئی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ اس میں حق اور باطل میں تمیز کرسکیں ۔ اور انہیں علم ہوسکے کہ کیا وہ صریح معقول کے مخالف ہیں یا موافق۔جب ان میں سے کوئی اسلام کا اظہار کرتا ہے تووہ اسے اسلامی عبارات سے تعبیر کرتا ہے۔ پس وہ عالم الملک کو جسم اور عالم النفس کو ملکوت سے تعبیر کرتا ہے۔عالم جبروت کو عقل سے تعبیر کرتا ہے ؛یا پھر اس کے برعکس۔
کہتے ہیں : بیشک نفوس اور عقول ملائکہ ہیں ۔اور بسا اوقات وہ نفسانی قوت جو فعل الخیرات کا تقاضا کرتی ہے اسے ملائکہ قراردیتے ہیں ۔ اوروہ قوت جو شر کا تقاضا کرتی ہے اسے شیاطین قرار دیتے ہیں ۔اور یہ کہ جو ملائکہ رسولوں پر نازل ہوتے ہیں اور وہ کلام جو موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے سنا تھابلاشبہ وہی چیز انبیاء کرام علیہم السلام کے نفوس میں موجود ہوتی ہے خارج میں نہیں ہوتی۔ اس کی وہی حیثیت ہے جیسے کوئی سویا ہواانسان خواب دیکھنا ہے۔ اورجیسا کہ بہت سارے ریاضت و مشقت کرنے والے لوگوں کے لیے حاصل ہوجاتا ہے۔ اس طرح سے کہ اس کے جی نورانی اشکال کا تخیل پیدا ہوتا ہے۔اور وہ اپنے جی میں کچھ آوازیں بھی سنتا ہے۔ زنادقہ کے نزدیک یہ اللہ کے فرشتوں اور کلام اللہ کی حقیقت ہے۔ ان کے نزدیک کلام منفصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کسی نے یہ بھی دعوی کردیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایسے ہی کلام کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ یا اس سے بھی بڑھ کر کلام کیا۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حروف اور اصوات کی صورت میں کلام کیا گیاتھا جو آپ اپنے جی میں محسوس کررہے تھے۔ اور وہ مجرد عقلی معانی سے کلام کرتے ہیں ۔
مشکاۃ الانوار اور’’الکتب المضنون بہا علی غیرأ ہلہا‘‘ کے کلام میں اس طرح کے کلام کا ایک قطعہ واقع ہوا ہے۔ اور اس وجہ سے دوسرے مقامات ان کی تکفیر کی گئی ہے۔ مگراس نے اس عقیدہ سے رجوع کرلیا تھا۔ اور آخر میں وہ بخاری ومسلم اور دوسری کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔
خلع النعلین کے مصنف ابن قسی اور ان کے امثال اور فصوص الحکم اور الفتوحات المکیۃ کے مصنف ابن عربی بھی اسی ڈگر پر چلے؛ اسی لیے انہوں نے یہ دعوی کر ڈالا کہ وہ بھی اسی معدن سے علم پاتے ہیں جس سے فرشتہ لیتا ہے اور جو انبیا کرام علیہم السلام کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک نبی فرشتہ سے وہی وحی حاصل کرتا ہے جو مرسلین کی طرف وحی کی گئی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک نبی ان خیالات سے لیتا ہی جو اس کے نفس میں متمثل ہوتے اورپھر عقلی معانی خیالی صورت میں ڈھل جاتی ہے۔ یہی صورت ان کے ہاں ملائکہ کی ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک نبوت محض عقل سے تصور کے خیال بننے سے پہلے اخذ کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نبوت پر ولائت کو ترجیح دیتا ہے۔ اور کہتا ہے: بزرخ میں نبوت کا مقام رسول سے تھوڑا اوپر اور ولی سے تھوڑا کم ہوتاہے۔
اس کے فاسد اصول کے مطابق نبی بغیر کسی واسطہ کے براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ عقل سے اخذ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہی بلاواسطہ اللہ تعالیٰ سے اخذ کرنا ہے۔ اس کے ان کے نزدیک ملائکہ کوئی منفصل چیز نہیں ہیں جو وحی لیکر نازل ہوں ۔ اور ان کے نزدیک رب مخلوقات سے جدا کسی وجود کا نام نہیں ۔بلکہ وہ ایک وجود مطلق ہے یا اللہ تعالیٰ کے متعلق بعض امور ثبوتیہ کی نفی کا نام ہے۔ یا پھر بعض امور ثبوتیہ اور سلبیہ کی نفی کا نام ہے۔ اور کہتے ہیں : وہ وجود مخلوقات کانام ہے۔ یا پھر ان میں حال کا نام ہے۔ یا پھر نہ یہ ہے اور نہ ہی وہ ۔ ان کے نزدیک ہر نبی و رسول کی انتہا و غایت یہی ہے۔
نبوت ان کے نزدیک اس قوت تخیلہ کا سے اخذ کرنے کا نام ہے جو عقلی معانی کو خیالی تمثیل میں ڈھالتی ہے۔ اسے وہ قوت قدسیہ کا نام دیتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ولایت کو نبوت سے بلند مقام دیا ہے۔
ان ہی کی جنس سے ملحد قرامطہ بھی ہیں ۔ لیکن یہ لوگ تصوف عبادت گزاری تحقیق و الوہیت کے دعوی کے لبادہ میں ظاہر ہوئے۔ اور دوسرا گروہ شیعیت اور موالات کے روپ میں ظاہر ہوا۔ پہلا گروہ اپنے مشائخ کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ انہیں انبیا کرام علیہم السلام سے بلند مقام تک پہنچادیتے ہیں ۔ اور ولایت کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اسے نبوت سے افضل قرار دیتے ہیں ۔ اور یہ دوسرا گروہ امامت کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک ائمہ انبیا کرام علیہم السلام سے بھی افضل ہوتے ہیں اور امام نبی سے افضل ہے۔ جیسا کہ اسماعیلیہ کا عقیدہ ہے ۔ان میں سے ہر ایک گروہ فلاسفہ کا ستوں شمار ہوتا ہے جو نبی کو فلسفی قراردیتے ہیں ۔ اور کہتے ہیں : نبوت قدسی قوت کے ساتھ مختص ہے۔ پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کو فلسفی پر ترجیح دیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو فلسفی کو نبی پر ترجیح دیتے ہیں ۔ ان کا خیال ہے کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے۔ جب کہ ان لوگوں کا کہناہے کہ: نبوت تین صفات سے عبارت ہے۔جس میں یہ تین صفات پائی جائیں وہ نبی ہے۔
۱۔ اس کے پاس انتہائی طاقتور قوت قدسیہ ہو تاکہ وہ بغیر سیکھنے کے علم حاصل کرسکے۔
۲۔ ہیولی عالم میں اس کی نفس کی تاثیر قوی ہو۔
۳۔ اس کی پاس قوت تخیل ہو جس سے وہ عقل حاصل کرے اور اپنے نفس میں دیکھ سکے اور اپنے نفس کے اندر سن سکے۔ نبوت کے متعلق یہ کلام ابن سینا اور اس کے امثال کا ہے۔ اور اس سے یہ عقیدہ امام غزالی نے اپنی کتاب میں کتب مضنون بہا علی غیر اہلہا میں لیا ہے۔
یہ جس قدر چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں تو اہل ایمان اور عوام الناس میں سیبھی کسی ایک ایسی کو حاصل ہوسکتی ہیں جو عموم اہل ایمان سے افضل بھی نہ ہو چہ جائے کہ وہ نبی ہو۔ اس مسئلہ پر ہم نے اپنی جگہ پر تفصیل کے ساتھ کلام کردیا ہے۔
جب ان لوگوں کو مسئلہ نبوت میں کلام کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنے اسلاف دہریہ کے عقیدہ کے مطابق اس امر کا اظہار کیا ۔وہ دہریہ جن کا عقیدہ ہے کہ افلاک قدیم اور ازلی ہیں ۔اورفاعل کے لیے کوئی مفعول اس کی اپنی قدرت اوراختیار سے نہیں ہوتا۔ نیز انہوں نے اللہ تعالیٰ کی متعلق جزئیات کے علم کاانکار کیاہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی ان کے مذہب کے فاسد اصول ہیں ۔ مگر اس گروہ نے ان کی راہ پر چلتے ہوئے ان کے اصولوں کے مطابق نبوت میں کلام کیا۔
جب کہ قدما جیسے ارسطو اوراس کے امثال ان کے نبوت میں کوئی سیر حاصل کلام نہیں ہے۔ان میں سے بعض لوگ نبی بننا چاہتے تھے جیسا کہ سہروردی مقتول بھی کوشش کررہا تھا کہ وہ نبی بن جائے۔ اس نے نظر اور الوہیت کے مابین جمع کیا تھا اورباطنیہ کے طریق کار پر گامزن تھا۔ نیز اہل فرس اوراہل یونان کے فلسفہ کوبھی جمع کیا تھا۔ روشنیوں کی بڑی تعظیم کرتا تھا۔اورپرانے مجوسیوں کے دین کے زیادہ قریب تھا۔ یہ بھی اسماعیلیہ باطنیہ کی کاپی تھا۔ جادوگری اور پانسہ بازی میں ید طولی رکھتا تھا۔ صلاح الدین رحمہ اللہ کے زمانہ میں مسلمانوں نے اسے شہر حلب میں زندیقیت کی وجہ سے قتل کردیا تھا۔
یہی حال ابن سبعین کا ہے جو مغرب سے مکہ آیا تھا۔اس کی بھی چاہت یہ تھی کہ وہ نبی بن جائے ۔اس نے اس غار حراء کی تجدید کی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں وحی نازل ہوئی تھی۔
اس ے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہاکرتا تھا: آمنہ کے بیٹے نے جھوٹ بولا اورکہا:’’لا نبِی بعدِی۔‘‘
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ انسان فلسفہ اور متصوفین کے متفلسفہ اور اس سے متعلقہ علوم کا ماہر تھا۔
یہ اور ابن عربی اوران کے امثال جیسے صدر قونوی ؛ابن فارض تلمسانی وغیرہ کا منتہائے امر وحدۃ الوجود کاعقیدہ تھا۔ اور یہ کہ بلاشبہ خالق قدیم واجب الوجودوہی وجود ممکن محدث مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ۔ پھر جب دیکھا کہ مخلوقات متعدد ہیں تو کبھی یہ کہنے لگے کہ: مظاہر اورمجالی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ:اگر مظاہر امر وجودی تعدد الوجود ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ یا اس طرح کا کلام کیا جاتا جس سے واضح ہوتا ہو کہ وجود کی دو قسمیں ہیں : خالق اور مخلوق۔ تو اس کے جواب میں کہتے : ہم اپنے ہاں کشف میں اس چیزکو ثابت مانتے ہیں جو صریح عقل کے خلاف ہوتی ہے۔اور جو کوئی ہماری طرح محقق بننا چاہتا ہے اس کے لیے جمع بین النقیضین کرنا لازم ہے ۔ اور یہ ایک جسم ایک وقت میں دو جگہ پر ہوسکتا ہے۔
ان اصناف کے بارے دوسرے مقامات پر تفصیل کیساتھ کلام گزر چکا ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں کی کثرت جہالت میں مبتلا علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ شیعیت کی طرف مائل ہوتے ہیں ۔ جیساکہ ابن عربی ابن سبعین اور ان کی مانند دوسرے لوگوں کا حال تھا۔پس لوگوں کوان کے حقائق سامنے لانے اور ان امور کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی جن کی وجہ سے حق اور باطل میں پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں کا اپنے متعلق دعوی ہے کہ وہ روئے زمین کے سب سے افضل لوگ ہیں ۔اور لوگ ان کے اشارات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ چیز آسان کردی تو میں نے ان کے حقائق کو بیان کردیا۔اور ان کے متعلق کتابیں لکھیں جن سے ان کو بھی علم ہوگیا کہ ان کے عقیدہ کی حقیقت یہ ہے۔اور نقل صحیح اورعقل صریح اور کشف مطابق سے اس کا بطلان بھی ثابت ہوگیا۔جس کی وجہ سے ان کے علماء و فضلاء نے حق کی طرف رجوع کیا۔اور پھر یہی حضرات لوگوں کے سامنے ان کا تناقض ثابت کرنے اور انہیں حق کی طرف واپس بلانے لگے۔ ان کی گمراہی کے اصولوں میں سے یہ بھی تھا کہ : وجود مطلق خارج میں بھی پایا جاتا ہے۔یا تووہ مطلق بغیر کسی شرط کے ہوتا ہے یا پھرمطلق مشروط ہوتا ہے۔مطلق غیر مشروط وہ ہے جسے وہ کلی طبیعی کا نام دیتے ہیں ۔ جب کہا جائے کہ یہ تو خارج میں موجود ہے۔ اور جو معین مقید خارج میں موجود ہووہ ذہن میں مطلق ہوتا ہے اور خارج میں مقید۔ رہے وہ لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ جو چیز ذہن میں مطلق ہوتی ہے وہ خارج میں بحالت تحقق مطلق ہوتی ہے تو یقیناً ایسا انسان بہت بڑی ایسی غلطی کا ارتکاب کررہا ہے جس میں بہت سارے اہل منطق و فلسفہ گمراہ ہوگئے۔ رہ گیا مطلق بشرط اطلاق وہ ایسا مقید وجود ہے جس سے تمام ثبوتی اور سلبی امور سلب کر لیے گئے ہیں ۔جیسا کہ انسان ہر قید سے خالی سے ہوتا ہے۔ جب آپ یہ کہیں کہ: وہ موجودہے یا معدوم ۔ ایک ہے یہ اکثر یا پھر ذہن میں ہے یا خارج میں ۔تو یہ شرط اطلاق کی حقیقت مطلقہ سے زائد ایک قید ہوگی۔اور اس طرح اس وجود کو ہر ثبوتی و سلبی قید سے مجرد قبول کرنا ہوتا ہے۔ آپ اس کی ثبوتی یا سلبی کو ئی صفت نہیں بیان کرسکتے۔ائمہ باطنیہ جیسے الاقالید الملکوتیہ کے مصنف ابو یعقوب سجستانی اور اس کی امثال کے ہاں اسے واجب الوجود کہتے ہیں ۔ لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو رفع نقیضین کو نہیں پہچانتے ۔ وہ کہتے ہیں : نہ ہی موجود ہے اور نہ ہی معدوم ۔ اور ان میں سے کوئی کہتا ہے: میں نقیضین میں سے ایک کے اثبات میں توقف کرتا ہوں ۔میں نہیں کہتا موجود ہے معدوم نہیں ۔جیسا کہ ابو یعقوب کا عقیدہ ہے۔ یہ وحد الوجود کے قائلین کی انتہا ہے۔
ابن سینا اور اس کے اتباع کہتے ہیں : وجودواجب وہ وجود ہے امور سلبیہ کو چھوڑ کر امور ثبوتیہ کی نفی کے ساتھ مقید ہو۔ اگرچہ یہ بات وجود اور عدم میں ممتنع بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی خارج میں وجود عدمی وسلبی کے ساتھ مقید وجود کے تصور سے بہت دور کی بات بھی ہے۔ میں نے تحقیق کے ان دعویداروں سے کہا: تم نے اپنے عقیدہ کی بنیاد مناطقہ کے قوانین پر رکھی ہے۔ یہ وجود مطلق جس میں اطلاق کی شرط لگائی گئی ہے یہ سلب نقیضین کے ساتھ مقید ہے ۔ اہل عقل و دانش کا اتفاق ہے کہ خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ۔ بلکہ اسے ذہن میں مقدر مانا جاتا ہے۔ وگرنہ اگر ہم انسان مطلق کو مقدر مانیں اور اس میں یہ شرط لگادیں کہ نہ ہی وہ معدوم ہو اورنہ ہی موجود ہو نہ ہی ایک ہو نہ ہی زیادہ تو خارج میں کوئی ایسا وجود نہیں پایا جاتا ۔ بلکہ ہم اسے ذہن میں فرض کرلیتے ہیں ۔ جیسا کہ ہم ذہن میں جمع بین النقیضین کو فرض کرلیتے ہیں ایسے ہی رفع نقیضین کو فرض کرنا بھی جمع بین النقیضین کو فرض کرنے کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہی کہ لوگ کبھی اسے جمع بین النقیضین کا نام دیتے ہیں تو کبھی ان دونوں سے امساک کا۔ جیسا کہ ابن عربی اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے کیا ہے۔ اور کبھی ان دونوں چیزوں کو جمع کرلیتے ہیں ۔ جیسا کہ کتاب البطاقہ کے مصنف اور دوسرے لوگوں کے ہاں ملتا ہے۔
مگر اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں وہی ذات اس عالم کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ وہ ذات کی کوئی مثتب یا منفی صفت نہیں بیان کی جاسکتی۔یہ ان کے عقیدہ میں تناقض ہے۔ اس لیے کہ اس کا مبدع ہونا ہی ان دونوں صفات سے خالی نہیں ہے۔
ایسے ہی جب کہتے ہیں : موجود واجب ہے تو اس میں نقیضین سے مجرد ہونے کی شرط لگاتے ہیں ۔ یہ بھی ان کے ہاں تناقض ہے۔
ان کے عقیدہ کی حقیقت یہ بنتی ہے کہ موجود موجود نہیں اور واجب واجب نہیں ۔ یہاں پران کی انتہا ہوجاتی ہے۔ یہ یاتوجمع بین النقیضین ہے یا پھر رفع النقیضین۔
یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ حیرانگی میں سرگرداں پھرتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں ۔ان کے ہاں انبیا و اولیا ائمہ وفلاسفہ کی معرفت کی منتہا یہی ہے۔
ان کی گمراہی کی اصل یہ ہے کہ یہ لوگ اس چیزکوتشبیہ سے تنزیہ شمار کرتے ہیں ۔ان کے نزدیک جب بھی کوئی مثبت یا منفی صفت بیان کی جائے تواس میں تشبیہ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اور ان کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ جس تشبیہ کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہے وہ وہ تشبیہ ہے جس میں اسے مخلوق کے خصائص میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے یا اس کی کسی صفت کو مخلوقات میں سے کسی کی صفت کی مانند قراردیا جائے ۔وہ بھی اس طرح سے کہ یہ عقیدہ ہوکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہ چیز جائز ہے جو مخلوقات کے لیے جائز ہے۔یا اس کے لیے بھی وہ چیز واجب ہے جو مخلو قات کے لیے واجب ہے۔ یا اس پر بھی وہ چیز ممتنع ہے جو مخلوقات پرمطلق طور پر ممتنع ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ شرع کیساتھ ساتھ عقلا بھی یہ مثال ممتنع ہے۔ پس یہ ممتنع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نقائص کے اوصاف بیان کیے جائیں ۔اور یہ بھی ممتنع ہے کہ صفات کمال میں کوئی د وسرا اس کے مماثل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کے لیے یہ دو جامع اصول ہیں ۔جیسا کہ ہم نے کئی مواقع پر بیان کیا ہے۔ اس پر دلیل یہ فرمان الٰہی ہے:
﴿قُلْ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ Oاَللّٰہُ الصَّمَدُ Oلَمْ یَلِدْ ۵ وَلَمْ یُوْلَدْ Oوَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ﴾
’’فرما دیجیے: وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ہی بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔‘‘
ہم اس سورت کی تفسیر میں ایک منفرد کتاب میں تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے۔
رہا اسما میں موافقت کا مسئلہ ؛جیسے حیی اورحیی ؛ موجود اور موجود اور علیم اور علیم ؛تو ایسا ہونا ضروری ہے۔ اورجس نے اس کی نفی کی ہے اس پر تعطیل محض لازم آتی ہے۔ اس لیے کہ موجودین میں سے ہر ایک بذات خود قائم ہے۔پس اس وقت ضروری ہوجاتا ہے کہ ایک ایسا اسم عام ان دونوں کوجمع کرے جو عام معانی پر دلالت کرتا ہو۔لیکن معنی عام صرف ذہن میں ہی پائے جاتے ہیں خارج میں ان کا وجود نہیں ہوتا۔
جب یہ کہا جائے کہ :یہ بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے تو یہ دونوں مسمی وجود میں مشترک ہوئے۔ جس چیز میں یہ دونوں شریک ہیں وہ مشترک صرف ذہن میں ہے خارج میں نہیں ۔ اور ہر موجود جو اپنی ذات اور صفات کے ساتھ مختص ہے اس میں کوئی چیز باہر سے اس کے ساتھ شریک نہیں ہوسکتی۔ بلکہ یہ اشتراک ایک قسم کی مشابہت اور اتفاق ہے۔اور اس میں مشترک کلی بھی صرف ذہن میں پایا جاتا ہے۔ سو جب یہ خارج میں پایا جائے تو وہ اپنے نظیر سے متمیز اور جدا نہیں ہوا۔اورنہ ہی وہ وہی ہوتا ہی۔اورنہ ہی وہ دونوں خارج میں کسی خارجی چیز میں مشترک ہوتے ہیں ۔ پس جب خالق کا نام مخلوق کے نام سے مشابہ ہو جیسے موجود اورحیی۔توکہا جائے گا کہ یہ اسم عام کلی ہے۔ یہ متواطی یا متشکک اسماء میں سے ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس مسمی اسم کے اعتبار سے رب کی جو صفات ہیں مخلوق بھی ان میں شریک ہو۔ بلکہ مخلوق میں سے جس کسی دوسرے کا اگر ایسا نہ ہو تووہ بھی اس کے ساتھ مواصفات میں شریک نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اس کا وجود اس کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کا وجود اس کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن جو مخلوق کی صفات ہیں وہ کبھی دوسرے مخلوق کی صفات کے مماثل ہوسکتی ہیں ۔اور ان میں سے کسی ایک مثل کے لیے وہ امور جائز ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے جائز ہیں ۔
جب کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں کوئی چیز اس کے مماثل نہیں ہوسکتی۔ بلکہ اللہ اور مخلوق کی صفات میں دو فرق اور تباین ہے وہ مخلوق کی صفات میں تباین و فرق سے بہت بڑا ہے۔ جب کہ اس میں معنی مشترک کلی عام جیسا کہ ہم نے ذکر کیا-یہ کلی طور پر صرف ذہن میں ہوسکتا ہے۔
جب دو موصوف میں اس لحاظ سے موافقت و مشارکت اور مشابہت کی ایک نوع پائی جاتی ہے اوراس میں کوئی محذور(ممانعت)والی بات نہیں ۔اس لیے کہ اس قدر مشترک کی وجہ سے وجوب یا جواز یا امتناع لازم نہیں آتا۔ پس اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ پس وہ موجود اپنے موجود ہونے کے اعتبار سے ہے ایسے ہی علیم اور حیی کی صفات کا معاملہ بھی ہے۔ سو جتنا بھی کہا جائے کہ اس سے وجوب یا جواز یا امتناع لازم آتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ جن صفات سے موصوف ہے وہ مخلوق کی صفات موجود و حیات اور علم کے خلاف ہیں ۔ اس لیے کہ مخلوق کے لیے جو امتناع جواز اور وجوب اور استحالہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان نہیں کی جاسکتیں ۔ اور نہ ہی جو صفات وجوب و جواز اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ مخلوقات کے لیے بیان کی جاسکتی ہیں ۔جو انسان اس بات کوسمجھ لیتا ہے اس کے بہت سارے اشکالات ختم ہوجاتے ہیں ۔ بہت سارے اذکیا جو علوم الکلیہ اور معارف الٰہیہ میں نظر رکھتے ہیں وہ اسی چیز کے قائل ہیں ۔ واجب الوجود میں ان کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے۔ یہ اطلاق نفی و اثبات کی شرط کیساتھ مطلق ہے۔ اور تعطیل و الحاد سے زیادہ کامل و اکمل ہے۔
دوسرا قول ابن سینا اور اس کے متبعین کا ہے کہ: بیشک وہ وجود قیود سلبیہ کیساتھ مقید ہے ثبوتیہ کے ساتھ نہیں ۔ اور کبھی اسے یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ وجود مقید ہے ۔ کبھی ماہیات میں سے کوئی بھی چیز اس کا معارضہ نہیں کرسکتی۔یہ تعبیر ابن رازی وغیرہ کی ہے۔ان عبارات کی بنیاد ان کا یہ عقیدہ ہے کہ :وجودکا ماہیات ممکنہ سے اعراض ہوسکتا ہے۔ امام احمد کے اصحاب میں سے بعض مناظرین و متکلمین اور کچھ دوسرے لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ:(ایسا نہیں )بلکہ خارجی وجود کی خارج میں ایک ثابت حقیقت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں نہیں ۔اہل اثبات میں سے جمہور کا یہی قول ہے۔اوردوسرا قول مذاہب اربعہ میں سے اور دوسرے مناظرین کا ہے جو اثبات صفات کے قائل ہیں ۔ لیکن شہرستانی؛ رازی اور آمدی وغیرہ رحمہم اللہ کا خیال یہ ہے کہ اس قول کا قائل کہنا چاہتا ہے کہ: لفظ وجود اشتراک لفظی کے لیے بنایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کلام اشعری وغیرہ سے نقل کیا ہے ۔ جب کہ یہ ان کے متعلق غلط بیانی ہے۔ اس لیے کہ اولین و آخرین میں سے جمہور کایہی قول ہے۔سوائے ایک چھوٹے سے طائفہ کے۔ ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ لفظ وجود اشتراک لفظی کے لیے بنایا گیا ہے ۔یہ اشعری اور اس کے اصحاب کا قول نہیں ۔ بلکہ ان کا اتفاق ہے کہ وجود کی دو قسمیں ہیں : قدیم اورمحدث۔
اسم وجود ان دونوں اقسام کو شامل ہے۔ لیکن اشعری ان احوال کی نفی کرتا ہے۔ وہ کہتاہے : عموم و خصوص کئی ایک اقوال کی طرف لوٹتا ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ خارج میں کلی عام کا کوئی معنی نہیں اس کا مقصود یہ نہیں ذہن میں کلی عام کا معنی قائم نہیں ہوسکتا۔
ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا وجود وہ بذات خود اس کی موجودہ حقیقت ہوتی ہے۔ بیشک یہی قول اشتراک لفظی کا ہے۔ اس لیے کہ ان کا کہناہے کہ:جب اگر ہم وجود کو متساوی ومتواطی(ہم پلہ وہم معنی) الفاظ سے عام قراردیدیں یہ ان الفاظِ متافضلہ کے لیے عام کردیں جنہیں متشککہ کہا جاتا ہے اور ہم نے کہاہے کہ : وجود واجب اور ممکن اور قدیم و محدث میں منقسم ہے تو یہ انواع مسمی وجود میں مشترک ہوتے ہیں ۔ یہی کلی مطلق ہے۔ ان میں سے ہر ایک کیلیے اپنی خصوصیت کے ساتھ دوسرے سے ممتاز(و جدا)ہونا ضروری ہے اسے حقیقت کہتے ہیں ۔پس اس سے لازم آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے وجود کے علاوہ حقیقت بھی ہوتی ہے۔
یہ ایس غلط ہے جس میں کئی لوگ گمراہ ہوگئے جیسے امام رازی اور اس کے امثال۔
اس کا بیان تین طرح سے ہے :پہلی وجہ :یہ کہاجائے گا کہ لفظ موجود بھی لفظ حقیقت اور لفظ ماہیت اور لفظ ذات اورنفس کی طرح ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وجود واجب و ممکن یاقدیم اور محدث میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ تمہارے اس قول کی منزلت پرہے کہ:حقیقت بھی واجب اورممکن یا قدیم اور محدث میں تقسیم ہوتی ہے۔ یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ ذات بھی ان ہی اقسام میں تقسیم ہوتی ہے۔اور ماہیت کی بھی تقسیم ایسے ہی ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے دیگر عام اسما کا بھی یہی حال ہے۔ اور جیسا کہ یہ کہہ دیں : چیز واجب اور ممکن اورقدیم اور حادث میں تقسیم ہوتی ہے۔
پس اس صورت میں جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ دونوں وجود یا وجوب میں مشترک ہیں تو ان میں سے ایک اپنی ماہیت یا حقیقت کے اعتبار سے دوسرے سے جداگانہ ہوگا تواسکی منزلت بھی یہی ہوگی؛گویاکہ یوں کہا جائے: یہ دونوں ماہیت اورحقیقت میں مشترک ہیں ۔ اور ان میں سے ایک دوسرے وجوب یا وجود کی وجہ سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دونوں وجود عام کلی میں مشترک ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی خاص حقیقت ہے۔
تو اس کے جواب میں کہا جائے گاکہ : ایسے ہی یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ :بیشک یہ دونوں اپنی عام کلی حقیقت میں مشترک ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے خاص وجود کے ساتھ جدا اور ممتاز ہے۔ پس اس صورت میں جس چیز کو آپ کلی عام قراردیتے ہوں جیساکہ جنس و عرض عام اور جس چیز کو آپ خاص ممیز جزئی قراردیتے ہو۔ جیسا کہ فصل اور خاصیت۔لیکن آپ نے عموم وخصوص میں دو متساوی چیزوں کا ارادہ کیا ہے۔اور ایک کو آپ نے حال عموم میں مقدر مانا ہے اوردوسری کوحال خصوص میں ۔ یہ سب آپ کی بنائی ہوئی تقدیریں اور قیاسات ہیں ۔ وگرنہ ان میں سے ہر ایک میں اسے ہی تقدیر ممکن ہے جیسے کہ دوسری چیز میں آپ نے مقرر کی ہے۔اور نفس امر میں ان میں سے ہر عموم و خصوص میں اور مشترک اور ممیز ہونے میں دوسری چیز کے برابر ہے۔ تو اس صورت میں تمہارے بنائے ہوئے جنس اورعرض عام اور فصل اور خاص میں حقیقت میں کوئی فرق نہیں ۔ سوائے اس کے کہ تم متساوین میں سے ایک کو عام قرار دیتے ہو اور دوسرے کو خاص۔
دوسری وجہ:....ان سے کہا جائے کہ :جب آپ کہتے ہیں : دو موجود مسمی وجود میں مشترک ہیں ۔ تو اس صورت میں ان میں کسی ایک کا دوسرے سے کسی امر کی بنا پر ممتاز ہونا لازمی ہے۔
اس کے جواب میں آپ سے کہا جائے گا کہ: ممیز کے لیے اس کا خاص وجود ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے یوں کیوں کہا: کہ یہ مسمی کے وجود سے خارج میں ایک چیز ہوتی ہے تاکہ تم ایک دوسری حقیقت ثابت کرسکو۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے کہا ہے :دو انسان مسمی انسانیت میں مشترک ہیں ۔ مگر ان میں سے ایک اپنی کسی خصوصیت کی وجہ سے دوسرے سے ممتاز اورجدا ہے۔تو اس ممتاز کی اپنی انسانیت ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے۔تو اس کے لیے یہ حاجت نہیں ہے کہ ممیز کو غیر کو انسانیت قرار دیا جائے جس سے انسانیت کا اعراض ہوتا ہے۔لیکن ان لوگوں کا خیال ہے کہ کلی میں مشترک انواع میں دوسرے مواد کے بغیر جدائی وفصل ممکن نہیں ۔ اس جگہ پر اہل منطق کی ان غلطیوں پر بڑا طویل کلام ہے جو انہوں نے کلیات اور تقسیم کلیات ترکیب حدود ذاتیات اور دوسرے امور میں قیاس کے مواد اور یقینی اور غیر یقینی چیزوں میں کی ہیں ۔ یہ تمام باتیں دوسرے مواقع پر درج ہیں ۔
تیسری وجہ:....ان سے کہا جائے کہ: جب ہم کہتے ہیں : دو موجود مسمی وجود میں مشترک ہیں ۔ اور ان میں سے ایک کا کسی چیز کی وجہ سے دوسرے سے ممتاز و جدا ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ کسی ایسی چیز میں مشترک ہیں جو کہ بعینہ خارج میں بھی موجود ہے۔ بلاشبہ ایسا ہونا ممتنع ہے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ا س جہت سے یہ دونوں آپ میں موافق اور متشابہ ہیں ۔
نفس مشترک فیہ صرف ذہن میں مشترک ہوتا ہے خارج میں نہیں ۔ وگرنہ نفس وجود میں ان کا اشتراک نہ ہوتا۔ پس اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ لفظ وجود عام کلی اور متشکک الفاظ میں سے اور اس کے معانی میں تفاضل پایا جاتا ہے۔ مگر ان کے اصل مسمی میں اتفاق کے باوجود مماثلت نہیں پائی جاتی۔ جیسا کہ لفظ سفید۔ برف کی سفیدی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ برص کی سفیدی اس سے کم ہوتی ہے ۔یہی حال کالے رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ کوے میں کالا رنگ زیادہ ہوتا ہے اور حبشی میں کم ہوتا ہے۔ اور یہی حال لفظ بلند کا بھی ہے۔ چھت بھی بلند ہوتی ہے اور آسمان بھی بلند ہوتا ہے۔ مگر دونوں کی بلندی میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور لفظ واسع کا اطلاق سمندرپر بھی ہوتا ہے اور بڑے گھر کو بھی واسع کہتے ہیں ۔ایسے ہی وجود کا لفظ بذات خود واجب الوجود کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دوسرے کی وجہ سے ممکن الوجود پر بھی بولا جاتا ہے۔ بذات خود قائم پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور دوسرے کی وجہ سے قائم پر بھی۔اور قدیم پہلی کے چاند کو بھی کہتے ہیں اور اسے بھی کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہو۔ اور محدث اس کو بھی کہتے ہیں جو آج ہی کے دن ایجاد کرلیا گیا ہو اور اسے بھی کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن عدم سے وجود بخشا ہو۔ اور لفظ حی انسان حیوان اورنباتات ے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور اس حیی وقیوم کے لیے بھی بولا جاتا ہے جسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی مخلوقات کے ان ہی اسماء سے بہت بلند و بالا ہیں ۔جیسا کہ الملک؛ السمیع البصیر العلیم؛ الخبیر اور اس طرح کے دیگر اسماء کا شمار بھی اسی باب میں ہوتا ہے۔
جب یہ کہا جائے کہ: تمام عام الفاظ اور تمام عام معانی-خواہ وہ متماثل ہوں یا متفاضل- بیشک جن کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے شریک یا موافق ہوتے ہیں ۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ خارج میں عام کا کوئی ایسا معنی ہے جو کہ عام ہے۔ اس لیے کہ لفظ عام اور اس کا معنی خود مشترک ہیں ۔بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض معین موجودات اس عام میں مشترک ہیں ۔ اور یہ عام صرف عالم کے علم میں ہوتا ہے۔جیسا کہ لفظ عام صرف بولنے والے کے الفاظ میں عام ہوتا ہے۔اور عام خط صرف کاتب کے خط میں ہی عام ہوسکتا ہے۔اس کے عام ہونے سے مراد بیرونی افراد کے لیے اس کا شامل ہونا ہے۔ نہ یہ کہ بذات خود موجود چیز خود اس کے ساتھ بھی متعین ہوگی اور خود ہی اس کے ساتھ بھی متعین ہوگی۔ اس لیے کہ بلاریب یہ بات حس اور عقل کے خلاف ہے۔
یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ابن سینا کا مذہب یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے واجب الوجود ہی تمام ثبوتی امور کے سلب کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔سلب النقیضین یا امساک عن النقیضین کے ساتھ مقید کرنے سے نہیں ہوتا۔جیسا کہ قرامطہ میں سے سجستانی اور اس کے امثال نے کیا ہے۔ابن سینا نے ان کے قول :وجود مقید کو یوں تعبیر کیا ہے کہ حقائق یا ماہیات میں سے کوئی بھی چیز سے سامنا نہیں کرسکتا۔ اس لیے کہ ان کا اعتقاد ہے کہ وجود ممکنات سے سامنا کرسکتا ہے۔یہی ان کا قول ہے کہ واجب کا وجود خود اس کی ماہیت ہے۔
جمہور اہل سنت یہی کہتے ہیں ۔لیکن ان دونوں کے مابین فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک وجود مطلق جو کہ سلب ماہیات کے ساتھ مشروط ہوتو اس کی کوئی ماہیت وجود مقید سلبی کے علاوہ نہیں ہوتی۔
جب کہ انبیاء علیہم السلام اوران کے ماننے والے تمام عقلاء جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اسی کے ساتھ خاص ہے اور موجود بھی ہے؛ مگر مخلوقات میں سے کسی بھی حقیقت کے متماثل نہیں ۔معتزلہ اور ان سے موافقت رکھنے والے ایک گروہ کا کہنا ہے :’’یہ حقیقت اپنی اصل حقیقت پر زائد وجود کے ساتھ موجود ہے۔‘‘
جب کہ جمہور کہتے ہیں : خارج میں مخلوق حقائق کی بھی وہی حقیقت ہے جو کہ موجود کی حقیقت ہے۔ان دونوں کے مابین فرق یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کو ذہنی قراردیا جائے اور دوسرے کو خارجی۔جب حقیقت یا ماہیت کو اس چیز کا نام قراردیا جائے جو ذہن میں موجود ہے۔یہ خارج میں موجود چیز سے ہٹ کرہوتی ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ’’الوجود الذہنی‘‘ تواس سے مراد ذہنی ماہیت ہوتی ہے۔ اورجب کہاجائے :خارجی ماہیت تو اس سے مراد خارجی وجود ہوتاہے۔اگر جب مخلوق میں ایسا جائز ہے تو خالق میں بالاولی جائز ہے۔
ابن سینا کے مذہب کا فاسد ہونا مکمل تصورکے بعد عقلی ضرورت کے تحت معلوم شدہ ہے۔ اس لیے کہ جب دو مودجود مسمی وجود میں مشترک ہوں اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے مجرد سلب کے علاوہ کسی وجہ سے ممیز نہ ہو کیونکہ بلاشبہ نفس الامر خالی عدم محض ہونے سے دو مشترکین میں تمیز کا سبب نہیں ہوسکتا ۔ اس لیے کہ عدم محض کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور جو خود کچھ بھی نہ ہو اس کی وجہ سے نفس الامر میں امتیاز ممکن نہیں ہوتا۔ اور دو موجود چیزوں کے مابین فاصل جو کہ ان دومیں سے کسی ایک کے ساتھ خاص ہوصرف امر ثبوتی یا متضمن بالامر ثبوتی ہی ہوسکتا ہے۔یہ بات ان کے ہاں منطق میں طے شدہ ہے۔ سو پھر اللہ سبحانہ وتعالی رب کائنات کا وجود وجود ممکنات کے ساتھ مسمی وجود میں کیسے مماثل ہوسکتا ہے؟ اورعدم محض کے علاوہ کسی امر ثبوتی کی بنا پر مخلوقات سے ممتاز نہیں ہوسکتا۔
بلکہ اس تقدیر کی بنا پر جس بھی موجود کو مقدر مانا جائے وہ اس موجود سے زیادہ کامل ہوگا۔ اس لیے کہ وہ موجود ان کے نزدیک اپنے وجود میں امر ثبوتی کے ساتھ مختص ہے۔ جب کہ ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ واجب الوجود مسمی الوجود میں مماثلت کے باوجود محض امر عدمی کے ساتھ ہی مختص ہوسکتا ہے۔یہ قول ہر ممکن الوجود کی واجب الوجود کے ساتھ مماثلت فی الوجود کو مستلزم ہے۔ اور ان سے اس کا امتیاز صرف امور ثبوتیہ کے سلب کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ جب کہ کمال تووجود میں ہوتا ہے عدم میں نہیں ہوتا۔ پھر عدم محض میں توکوئی کمال ہے ہی نہیں ۔ سو اس بنا پر وہ ممکنات سے صرف تمام کمالات کے سلب کی وجہ سے ہی ممتاز ہوگا جب کہ ممکنات اس سے تمام کمالات کے اثبات کی بنا پر ممتاز ہونگی ۔یہ ممکنات کی کمال اور وجود میں تعظیم کی آخری حد ہوگی جس میں واجب الوجود نقص اور عدم سے موصوف ہوگا۔
نیز یہ وجود جو کہ اپنے غیر سے صرف عدمی امور کی بنا پر ممتاز ہوتا ہے خارج میں اس کا وجود ناممکن ہوگا۔ بلکہ ذہن کے بغیر اس کا امکان بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ جب یہ ساری موجودات کے ساتھ مسمی وجود میں شریک ہے تو یہ کلی ہوا۔ اور وجود کلی صرف ذہن میں ہوسکتا ہے خارج میں نہیں ۔ نیز یہ کہ محض عدمی امور خارج میں ان کے ثبوت کو واجب نہیں کرتے۔ اس لیے کہ جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے وہ خارجی حقائق کے سلب ہونے سے سلب خارج کا زیادہ حق دار تھا اگرچہ خارج میں یہ ممکن بھی ہوتاتو پھر اس وقت کیا عالم ہوگا جب کہ یہ ممتنع ہو۔
پس جب کلی صرف ذہن میں ہی ہوتا ہے۔اور عدمی قیود اس کو کلی ہونے سے خارج نہیں کرسکتی تو ثابت ہوا کہ خارج میں بھی یہ نہ ہو ۔مزید برآں کہ جوکچھ خارج میں ہے وہ صرف معین ہی ہوسکتا ہے۔ اس کا اپنا وجود ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے۔ جو اس طرح نہ ہو وہ صرف ذہن میں ہی ہوسکتاہے۔ پس ان تین وجوہات اور دیگر وجوہ کی بنا پر ثابت ہوا کہ اس نے جو کچھ واجب الوجود کے متعلق ذکر کیا ہے وہ صرف ذہن میں متحقق ہوسکتا ہے خارج میں نہیں ۔ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اسے امور عدمیہ کے ساتھ مقید کرتے ہیں ۔
ان کا ایک تیسرا قول بھی ہے:وجود مطلق شرط اطلاق کے بغیر جسے یہ کلی طبیعی کا نام دیتے ہیں خارج میں اس کا وجود صرف معین طور پر ہی ہوسکتا ہے۔ یہ قول بھی اپنے سے پہلے دو اقوال کی جنس سے ہے۔ ان میں سے بعض خیال کرتے ہیں کہ خارج میں وہ ثابت ہوتاہے۔ اوروہ معینات کا ایک جز ہے۔پس اس صورت میں ہرمبدع واجب الوجود یا تو مخلوقات کے ساتھ قائم عرض ہوگا یا پھر ان میں سے ایک جز ہوگا۔ پھر یہ واجب عرض میں ممکن کا محتاج ہوگا یا اس میں سے ایک جز کا۔ جیسے حیوانات میں حیوانیت کی منزلت ہوتی ہے۔ یہ خود حیوانات کی خالق نہیں ۔ اور نہ ہی انسانیت انسان کو پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز کے جز یا عرض کا اس چیزکا خالق ہونا ممکن نہیں ۔ بلکہ خالق اس سے جدا اور منفصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جز اور عرض اس(اصل چیز) میں داخل ہوتے ہیں ۔ داخل چیزکے لیے اپنے کل کاخلق اور مبدع ہونے ممکن نہیں ہوتا۔
یہ لوگ جو کچھ اللہ رب العالمین کی صفات بیان کرتے ہیں ان کی موجودگی میں اس کے لیے ممتنع ہے کہ وہ موجودات میں سے کسی ایک چیز کا خالق ہو چہ جائے کہ وہ تمام مخلوقات کا خالق ہو؛ ان امور کی مکمل تفصیل دوسری جگہ پر موجود ہے ۔
یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ان ملاحدہ کے عقیدہ کی حقیقت خالق کا انکار کرنا نبوت کی حقیقت معاد اور شرائع کا انکار کرنا ہے۔ اس چیز کو یہ لوگ موالا ت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس عقیدہ پر تھے۔ جیسا کہ قدریہ جہمیہ اور رافضہ دعوی کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے عقیدہ پر تھے۔ اوریہ عقیدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ماخوذ ہونے کا دعوی بھی کرتے ہیں ۔ یہ تمام باتیں باطل اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام ہیں ۔