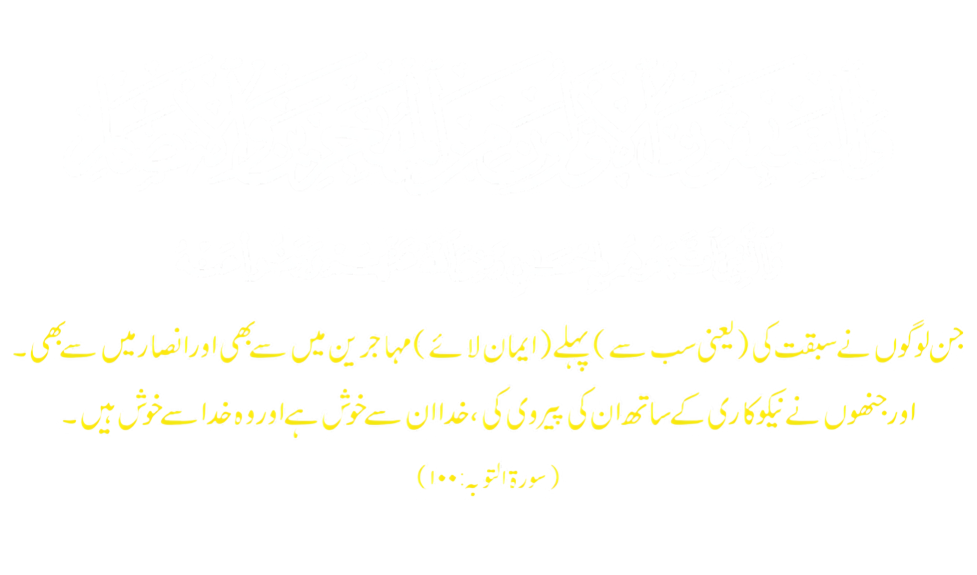دوبارہ لفظ ’’جسم ‘‘کے معانی پر کلام:
امام ابنِ تیمیہؒدوبارہ لفظ ’’جسم ‘‘کے معانی پر کلام:یہاں تو مقصود یہ ہے کہ وہ جہمیہ جو اللہ کی ذات سے صفات کی نفی کرنے والے ہیں جب وہ ظاہر ہوئے تو لوگوں نے لفظ ’’جسم ‘‘میں کلام کیا ہے۔ اور لفظ ’’جسم ‘‘کو اصول دین میں داخل کرنے میں کلام کیا ،ایسے ہی توحیدکے باب میں اور یہ ایسا کلام ہے جو کہ سلف اور آئمہ کے نزدیک مذموم ہے۔ پس لوگ لفظ ’’جسم ‘‘میں تین طوائف میں تقسیم ہو گئے :ایک گروہ نے کہا کہ: وہ جسم ہے۔دوسرے نے کہا کہ وہ جسم نہیں ۔تیسرے نے کہا : اس قول کا اطلاق اُس پر ممتنع ہے؛ اس لیے کہ شریعت میں بدعت ہے۔یا پھر یہ کہ عقلی اعتبار سے (لفظ جسم )حق اور باطل دونوں کو شامل ہے۔پھر ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی زبانوں کو ایسی گفتگو سے روکے رکھتے ہیں ۔ اور بعض متکلم سے تفصیل پوچھتے ہیں ؛ اگر وہ نفی اور اثبات میں صحیح معنی ذکر کر یں تو قبول کر لیتے ہیں ؛ اور اس کوشرعی عبارت کے ساتھ تعبیر کر لیتے ہیں ۔ اور ایسی عبارت سے اس کی تعبیر نہیں کرتے جو شرعا مکروہ ہو۔ اور اگر وہ کوئی باطل معنی ذکر کر دے تو اس کو رد کر دیتے ہیں ۔یہ اس لیے کہ لفظ ’’جسم ‘ ‘ میں لغت کے اعتبار سے کئی معانی میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ اور معنی میں اختلاف ایک عقلی اختلاف ہے۔ پس ہر قوم اپنی اصطلاح اور اپنے اعتقاد کے اعتبار سے اس لفظ کا اطلاق کرتے ہیں ۔ اس لیے کہ جسم اہل لغت کے نزدیک بدن ہے۔ یا بدن کے مثل یعنی ایسی چیز جو غلیظ؍موٹی اور کثیف ہو۔ ایسے ہی اہل لغت میں سے بہت سے حضرات نے نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح کا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے:﴿وَاِِذَا رَاَیْتَہُمْ تُعْجِبُکَ اَجْسَامُہُم﴾( منافقون: ۴ )’’ اور جب آپ انھیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگیں گے۔‘‘اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:﴿وَ زَادَہٗ بَسْطَۃً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ﴾ (بقرہ: ۲۴۷ )’’اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے۔‘‘پھر بسا اوقات اس جسم سے نفس وہ موٹی اور کثیف چیز مراد لی جاتی ہے اور بسا اوقات اس سے اس سے نفس کی جو موٹائی اور کثافت ہے وہ مراد لی جاتی ہے۔ اور ایسی صورتِ حال میں زیادت اس جسم میں متحقق ہوگی جو طول وعرض سے عبارت ہے؛ اور وہی قدر ہے ۔اور اول قول کے مطابق مقدّر اور موصوف ذات میں زیادتی ہوگی۔بسا اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کپڑا اس کے لیے ایک جسم ثابت ہے یعنی یہ موٹا ہے اور پتلا نہیں اور ہوا کو جسم نہیں کہا جاتا ہے اور نہ اس سانس کوجسم کہا جاتا ہے جو انسان کے منہ سے نکلنے والی ہے اور اس کے امثال ان کے نزدیک جسم نہیں ہیں ۔رہے اہل کلام اور فلسفہ ؛ تو ان کے نزدیک جسم اِن تمام تعبیرات سے زیادہ عام ہے۔ جس طرح سے لفظ ’’جوہر‘‘ لغت میں ان کی اصطلاح کی بہ نسبت زیادہ خاص معنی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ جوہر سے ایسی ذات مراد لیتے ہیں جو قائم بنفسہ ہو؛ یا جومتحیز[مکان میں ] ہو؛ یا ایسی ذات جب وہ وجود میں آئے تو اس کا وجود کسی جگہ پر نہ ہو۔ یعنی کسی ایسے محل میں نہ ہو جس سے وہ مستغنی ہو۔ اور ’’جوہر ‘‘لغت میں جوہرِ معروف ہے۔ پھر بسا اوقات جسم کو ایسی ذات سے بھی تعبیر کرتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے ؛یا جو اشارہ حسیہ کو قبول کرے یعنی وہ یہاں ہے اور یہاں ہے۔ اور بسا اوقات اس کو ایسی ذات سے تعبیر کرتے ہیں جو ابعادِ ثلاثہ یعنی طول عرض اور عمق کو قبول کرے۔ اور ایسی چیز کے ساتھ جس میں ابعاد ثلاثہ یعنی طول ،عرض اور عمق ہوں ۔[الشفاء ۱؍ ۶۱]لفظ ’’بُعْد‘‘ان کی اصطلاح میں طول؛ عرض اور عمق سے عبارت ہے ۔اور یہ اس کے لغوی معنی سے زیادہ عام ہے۔ اس لیے کہ اہل لغت اعیان اور اجسام کو طویل اور کثیف کی طرف تقسیم کرتے ہیں اور اور مسافت اور زمان کو قریب اور بعید کی طرف تقسیم کرتے ہیں اور زمین میں سے جو ہموار زمین ہے اس کو عمیق (گہرے )اور غیر عمیق کی طرف تقسیم کرتے ہیں ۔ اور ان لوگوں کے نزدیک ہر وہ چیز جس کو انسان دیکھتا ہے یعنی وہ اعیان میں سے ہے۔ وہ طویل ،عریض اور عمیق ہو سکتی ہے۔حتی کہ ایک دانہ بھی ،ایک ذرہ بھی بلکہ جو ذرہ سے بھی چھوٹاہے اور یہ ان کی اصطلاح میں طویل ،عریض اور عمیق ہو سکتا ہے ۔ بسا اوقات یہ جسم کو مرکب سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کا معنی ان کے نزدیک لغوی معنی سے زیادہ عام ہے اس لیے کہ جو لغت میں مرکب کہلاتا ہے تو وہ وہ ہوتا ہے جس کو کسی ترکیب دینے والے نے مرکب کیا ہو یا کسی مولف نے اس کی تالیف کی ہو ۔جیسے کہ وہ دوائیں جو معجون اور اشربہ سے مرکب ہوتی ہیں ۔ا ور مرکب سے وہ بھی مراد لیا جاتا ہے جس کو کسی غیر کے اوپر چڑھایاگیا ہو؛ یااس کے اندر اس کو ملا یا گیا ہو جیسے کہ دروازہ جو دیوار میں اپنی جگہ پرلگا دیا جاتا ہے تو اس کو بھی مرکب کہتے ہیں ۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:﴿فِیْ اَیِّ صُورَۃٍ مَا شَائَ رَکَّبَکَ ﴾(انفطار: ۸ )’’جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔‘‘یہ اہل لغت لفظِ’’ تالیف ‘‘سے دلوں کے درمیان موافقت مراد لیتے ہیں اور اس کے امثال ۔اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشادہے :﴿ والمؤلفۃ قلوبہم﴾( توبہ: ۷ )’’اورتألیف ؍میلان قلبی رکھنے والے۔‘‘اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:﴿ وَأَلَّفَ بَیْْنَ قُلُوبِہِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِیْ الأَرْضِ جَمِیْعاً مَّا أَلَّفَتْ بَیْْنَ قُلُوبِہِمْ وَلَـکِنَّ اللّہَ أَلَّفَ بَیْْنَہُمْ إِنَّہُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ﴾(انفال :۶۳) ’’اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اگرآپ زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے؛ اور لیکن اللہ نے ان کے مابین الفت ڈال دی۔ بے شک وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔‘‘اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:﴿إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِہِ إِخْوَاناً ﴾(آل عمران: ۱۰۳)’’جب تم دشمن تھے تو اس نے تمھارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔‘‘لفظ ’’مؤلف ‘‘اور لفظ’’ مرکب‘‘ میں لوگوں کے کئی اصطلاحات ہیں یعنی کئی معانی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے کہ نحویوں کی خاص اصطلاح ہے۔ بسا اوقات وہ مرکب سے ’’جملۂ تامہ ‘‘مراد لیتے ہیں اور بسا اوقات اس سے ایسا لفظ مراد لیتے ہیں کہ جو ترکیب مزج (مرکب بنائی) ساتھ مرکب ہو؛ جیسے بعلبک۔ اور بسا اوقات اس سے مراد ’’مضاف ‘‘اور ’’شبہ مضاف ‘‘مراد لیتے ہیں ،یعنی جس کو منادی ہونے کی حالت میں منصوب ہوتا ہے ۔اہل منطق اور ان کے ہمنوا اہل کلام کے ہاں کچھ اوراصطلاحات ہیں ۔ جس میں وہ مرکب سے مراد ایسی چیز لیتے ہیں جس کا جزء اس کے معنی کے جزء پر دلالت کرے ۔پس اس میں مضاف بھی داخل ہے؛ جب کہ اس سے اضافت کا ارادہ کیا گیا ہو علمیت کا نہیں پس اس کے اندر بعلبک اور ان کے امثال داخل نہیں ۔ان کے نزدیک ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے مؤلف اور مرکب کو ایک قرار دیا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں ان میں فرق کرتے ہیں ۔ اور یہ سب کچھ جو مذکور ہوا؛ اقوال میں تالیف ہے ۔رہا اعیان کے اندر تالیف؛ تو وہ جب کہتے ہیں کہ جسم مؤلف اور مرکب ہے تو اس سے ان کی مرادد وہ نہیں ہوتی جو پہلے الگ الگ تھا اور پھر مجتمع ہوا؛ اور نہ وہ جو تفریق کو قبول کرتا ہے۔ بلکہ ان کی مراد وہ ذات ہے جس کی ایک جانب دوسرے جانب سے جدا ہے جیسے کہ شمس و قمر اور دیگر اجسام۔رہے فلاسفہ تو ان کے نزدیک مرکب اور مؤلف ان معانی سے عام ہے۔ اس میں وہ تالیفِ عقلی کو بھی داخل کرتے ہیں جو اعیان میں نہیں پایا جاتا اور ان کا دعویٰ) یہ ہے کہ نوع ،جنس اورفصل سے مؤلف ہے جب تو کہتا ہے کہ انسان حیوانِ ناطق ہے پس انسان ان دونوں سے مؤلف ہے اور وہ ان کے ساتھ موصوف ہے پھر انہوں نے جسم کے ساتھ اختلاف کیا ہے کہ کیا وہ ایسے اجزاء سے مرکب ہے جو تقسیم کو قبول نہیں کرتے اور وہ ان کے نزدیک جوہرِ فرد ہے اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی نے بھی اپنی حس اور آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ہم جس چیز کو بھی فرض کرتے ہیں توجوہرفرد اس سے جسم کے اعتبار سے چھوٹاہوتا ہے ۔اس کے قائلین کے نزدیک یا تووہ مادہ اور صورت سے ترکیب عقلی میں مرکب ہے۔ جب ان سے مادہ کے بارے میں تحقیق پوچھی جائے تو ان کے ہاں صرف نفس ،جسم اور اعراض پائے جاتے ہیں ۔ کبھی تو مادے سے جسم مراد لیا جاتا ہے جو جوہرہے اور صورت اس کی شکل ہے۔اور صورت اس کی شکل اور اتصال ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اوربسا اوقات صورت سے نفسِ جسم مراد لیا جاتا ہے جو کہ جوہر ہے اور مادہ سے مقدار مراد لی جاتی ہے جو کہ مطلق ہے اور تمام اجسام کو عام ہے۔ یا اس سے وہ چیز مراد لی جاتی ہے جس سے جسم کو پیدا کر دیا گیا ہو اور بسا اوقات صورت ِ عرضیہ سے وہ امر مراد لیا جاتا ہے جو اتصال ہے اوراس کے ساتھ شکل قائم ہے پس جسم تو متصل ہے اور صورت اتصال ہے اور صورت یہاں عرض ہے۔ اور مادہ جسم ہے اسے صورتِ صناعیہ جیسے کہ چار پائی کی شکل کہ اس کی صورت لکڑی کا مادہ ہے۔ اور مادہ اور ہیولیٰ کے لفظ سے ان کے نزدیک یہی صورتِ صناعیہ مراد ہوتی ہے۔ اور یہ عرض ہے کہ جو انسانوں کے فعل سے پیدا ہوتا ہے اور اسی سے صورت طبعیہ مراد لی جاتی ہے اور وہ نفسِ اجسام ہی ہیں جو کہ جواہر اور مادہ ہیں اور وہ چیز جس سے وہ پیدا کیے گئے ۔اوقات مادہ سے مادہ ازلیہ مراد لیا جاتا ہے ؛ جو صورت سے مجرد ہوتا ہے۔ اور افلاطون اس کا قائل ہے؛ جبکہ باقی تمام عقلاء نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور حقیقت میں وہ ذہن میں تو ثابت ہیں خارج میں نہیں ۔ اور تمام اجسام جوایک قدر میں مشترک ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے؛ جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے ۔ پس وہ نوعِ مقدار میں تو مشترک ہیں عینِ مقدار میں نہیں لہٰذااجسا م مقدار میں مشترک ٹھہرے ۔
پھروہ کہتے ہیں :ان کے درمیان مادہ اور ھیولیٰ مشترک ہے ۔اور وہ کلی مطلق اور معین چیز کے درمیان اشتراک میں فرق کی طرف صحیح راہ نہیں پا سکے (یعنی درست موقف اختیار نہیں کیا )۔پس جسمیت ،امتداد اور مقدار میں اجسام کا اشتراک جس کے متعلق یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ مادہ ہے۔ یا اس کے مثل جیسے کہ لوگوں کا انسانیت میں اشتراک اور حیوانات کا حیوانیت میں اشتراک۔ اور ن کا خیال ہے کہ یہ کلیات خارج میں موجود اور مشترک ہیں ۔ حالانکہ یہ غلطی ہے۔ اس لیے کہ خارج میں جو کچھ ہے؛ اس میں کوئی اشتراک نہیں ۔بلکہ ہر موجود چیز کا وجود اس کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا۔ اور اشتراک تو ان امور عامہ کلیہ مطلقہ میں واقعہ ہوتا ہے۔ اور امور کلیہ مطلقہ تو صرف ذہن میں پائے جاتے ہیں ؛ اعیان میں نہیں ہوتے۔ پس جس چیز میں اشتراک پایا جاتا ہے اس میں صرف علم اور عقل ہوتے ہیں ۔اور جس چیز کے ذریعے اختصاص اور امتیاز حاصل ہوتا ہے؛ ۔وہ خارج میں موجودہے۔ اس میں تو کوئی اشتراک نہیں ۔بیشک اس میں تو اشتباہ اور تماثل پایا جاتا ہے جسے اشتراک کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک عام معنی کے اندر اشتراک۔ اور اشتراک کے اعتبار سے انقسام ۔پس جوکوئی جزئیات کی کلی اور جزی کی تقسیم میں فرق نہیں کرتا؛جیسے کہ کلمہ کا اسم ،فعل حرف میں تقسیم ہونا ؛تو وہ غلطی کا شکار ہے۔ جیسے اور بھی بہت سے لوگ اس مقام میں غلطی میں پڑے ہوئے ہیں ۔جب نحویوں میں سے ایک گروہ جیسے کہ زجاج اور ابن جنی؛وغیرہ نے کہا کہ: کلام کواسم ،فعل اور حرف کی طرح تقسیم کیا ہے۔ یا کلام سارے کا سارا تین قسم پر ہے :اسم ،فعل اور حرف۔ تو اِس پر اُس شخص نے اعتراض کردیا جو ان کے مقصود کوجان سکا۔اور اس نے قسمت کو دو اقسام میں تقسیم نہیں کیا؛ جیسے کہ جزولی رحمہ اللہ ۔ اس کا کہنا ہے کہ ’’:ہر جنس انواع اور اجسام میں تقسیم ہوتی ہے۔ یا ایسی نوع میں جسے اشخاص میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پس مقسوم کا لفظ’’اسم ‘‘ ان انواع اور اشیاء سب پر صادق آتاہے۔ ورنہ تو اقسام ہی حاصل نہ ہوتیں ۔تفسیر ابن جنی میں ابو البقاکا کلام اس کے زیادہ قریب ہے۔چنانچہ وہ کہتا ہے کہ: اس کا معنی یہ ہے کہ :’’ کلام کے اجزاء یا اس کے مثل۔‘‘یہ بات بدیہی طور پر معلوم ہے کہ خارج میں کسی بھی موجود چیز کا اپنے ابعاض اور اجزاء میں تقسیم ہونا ،کسی عام معنی کا ذہن میں انواع اور اشخاص کی طرف تقسیم سے زیادہ مشہور ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
بسا اوقات مادہ سے مادہ کلیہ مراد لی جاتی ہے۔ جس میں اجسام شریک ہوتے ہیں ۔ یعنی مقدار اور یہ کلیات ذہن میں حاصل ہوتے ہیں ؛اور وہ خارج میں ایک امر معین ہوتا ہے یا اعراض ہوتے ہیں ؛ یا جواہر۔ اور بسا ہے؛ اور آدھا دوسرا ۔اورکوئی اس کی شاخیں لے لیتا ہے۔ اب درخت کا نام ان اجزاء پر صادق نہیں آتا؛ الا مجازاً ۔ اور اگر ان کے درمیان تیر تقسیم کر دیا جائے جس طرح صحابہ کرام تقسیم کر لیا کرتے تھے؛ پس ایک شخص اس کا پھل لے لیتا تو دوسرا درمیانی حصہ۔ اور یہ تیسرادستے والاحصہ لے لیتا۔ تو ان میں سے ہر ایک پر سہم کا اطلاق درست نہیں ہے۔ پس جب مقسوم کا نام صرف حالت اجتماع میں واقع ہوتا ہے تو تقسیم وہ سے زائل ہو جاتا ہے ۔﴿وَنَبِّئْہُمْ اَنَّ الْمَائَ قِسْمَۃٌ بَیْنَہُمْ کُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ﴾(قمر28)’’اور انھیں بتا دے کہ بیشک پانی ان کے درمیان تقسیم ہو گا، پینے کی ہر باری پر حاضر ہوا جائے گا۔‘‘اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى ﴾(النساء: ۸) ’’اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے حاضر ہوں ۔‘‘اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:(( واللہ انی ما أعطی أحدا ولا أمنع أحداًوانما أنا قاسم أقسم بینکم۔))[1] [1] فِی البخارِیِ:4؍85؛ ِکتاب فرضِ الخمسِ، باب فإِن لِلہِ خمسہ ولِلرسولِ؛ وانظر :فتح الباری 6؍152 ؛ المسند ط. المعارِف12؍180 ؛ رقم: 7193 م . وانظر در تعارضِ العقلِ والنقلِ 8؍278.۔’’اللہ کی قسم !میں جو ہے میں کسی کو بھی اپنی طرف سے نہیں دیتا اور نہ کسی کو اپنی طرف سے روکتا ہوں یعنی اس سے اس کا حق روکتا ہوں میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں جو تمہارے درمیان بانٹتا ہوں ۔‘‘اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ :(( لا تعضیۃ فی المیراث الاما حمل القسم۔))[2][2] سنن الکبری للبیہقي ۱۰؍۱۳۳] ہذا الحدیث ضعیف لانقطاعہ۔ الجامع الکبیر للسیوطی ۱؍۸۹۶۔ النہایۃ في غریب الحدیث و الأثر ۳؍ ۱۰۶۔
’’ میراث میں کسی کو کچھ نہ دیا جائے ؛ سوائے اس کے جو اس کی تقسیم میں آئے۔‘‘اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کی جو حدیبیہ میں حاضر تھے۔ اور حنین کے غنائم کو مقام جعرانہ میں تقسیم کیا جس وقت طائف سے لوٹ رہے تھے ۔ اورحضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی میراث تقسیم فرمائی۔ اور فقہاء کاتقسیم پر ابواب قائم کرنا مثلاً:’’باب قسمۃ الغنائم والفیء والصدقات وقسمۃ المیراث وباب القسمۃ وذکر المشاع والمقسوم وقسمۃ الاجباروالتراضی‘‘کسی حساب کرنے والے کا یہ کہنا کہ:’’ ضرب اورتقسیم سے مراد خارج میں موجود اعیان کی تقسیم ہوتی ہے ۔ پس دو شریکوں میں سے ایک حصہ لے لیتا ہے اور دوسرا دوسرا حصہ۔ تو مقسوم کے ناموں میں سے ہر ہر قسم کے بارے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ان میں سے ہر ایک پر منفرداً بھی صادق آئے۔ پس ان کے درمیان ایک اونٹ کو تقسیم کر دیا جائے تو کوئی ایک اس کی ران لے لیتا ہے اور دوسرا سر لے لیتا ہے اور تیسراکمر ۔ تو اب اونٹ کا لفظ ان ابعاض پر اکیلے صادق نہیں آتا۔ایسا ہی ان کے درمیان درخت کو تقسیم کر دیا جائے تو آدھا تنا ایک لے لیتا
اگریہ نام اجتماع اورافتراق دونوں حالتوں میں بولا جا سکے؛ جیسے کہ پانی اور تمر ؛اور دیگر ۔ تووہ دونوں حالتوں میں صادق آتا ہے اور دونوں صورتوں میں مقسوم یہاں موجود فی الخارج ہے۔جب ہم کہیں کہ حیوان ناطق اوربے زبان میں تقسیم ہوتا ہے تو ہم کسی خارج میں موجودکسی معین حیوان کی طرف اشارہ نہیں کرتے کہ ہم اس کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں ۔ بلکہ اس لفظ اور معنی میں وہ چیز بھی داخل ہے جو خارج میں موجود ہے اور وہ بھی جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی۔ اور یہ ایسی جزئیات کوبھی شامل ہوتا ہے جو ذہن میں بھی نہیں آتے۔ اور یہ معانی کلیہ تو خارج میں بالکل نہیں پائے جاتے۔پس جب کہا جائے گاکہ تمام اجسام لفظ ’’جسم ‘‘کے مسمیٰ ہونے میں مشترک ہیں مقدارِ معین میں مشترک ہیں یا اس کے مثل کوئی اور تعبیر تو یہ مشترک یہاں ایک معنی کلی ہوگا اور اس (خاص معین )جسم کا مقدار معین اس دوسرے جسم کے مقدارِ معین کے مثل نہیں ہوگا بلکہ مغایر ہوگا اگرچہ وہ اس کے مساوی ہو۔ اور اگر وہ اس سے بڑاہو تو یہاں پر بھی نوعِ مقدار میں اشتراک ہے نہ کہ خاص مقدار میں ۔ پس اجسام میں اشتراک ان امور میں ہے ،رہا خارج کے اندر کسی موجود چیز کا ثبوت؛ تو وہ اس انسان میں ہے بعینہ اس دوسرے انسان میں بھی ہے ؛ تویہ مکابرہ ہے۔ خواہ یہ مادہ میں ہو یا حقائق کلیہ میں ۔ لیکن ان لوگوں نے صرف وجود ذہنی رکھنے والے امور کواعیان میں بھی ثابت مان لیاہے۔ اور اس امر پر تفصیلی کلام دوسرے مقام پر ہو چکا ہے۔یہاں تو اتنا مقصود ہے کہ یہ باب متکلمین اور مناطقہ میں سے فلاسفہ اور ان کے ہمنواؤوں کی اصطلاح میں تالیف اور ترکیب کہلاتا ہے۔ اور یہ ان انواع کے علاوہ ایک اور نوع ہے۔ اور ہرمرکب کے لیے تو کسی مفرد کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب ان پر تحقیق کی جائے تو پھر ان کے ہاں کوئی ایسا مفرد معنی نہیں پایا جاتا جس سے یہ مرکبات بنتے ہیں ۔بیشک یہ امور صرف وجود ذہنی رکھتے ہیں ،اعیان میں نہیں ۔ پس فرض کردہ بسیط مفردجیسے حیوانیت مطلقہ اور جسمیتِ مطلقہ؛ اور ان کے امثال؛ وہ خارج میں نہیں پائے جاتے۔ إلا یہ کہ صفات معینہ جو کہ خاص موصوفات میں موجود ہوں ۔ پس یہ اموراصطلاحات وضعیہ کے اعتبار سے لفظِ ’’مؤلف ‘‘اور لفظ ’’مرکب ‘‘کے مصداق تو ہیں ؛ اس کے ساتھ ان میں کچھ عقلی اعتبارات کو بھی دخل ہے ۔ان کا جسم کے بارے میں اختلاف ہے؛ کہ کیا وہ ان جواہرمفردہ سے مرکب ہے جو انقسام کو قبول نہیں
کرتے۔ جیسا کہ بہت سے اہل کلام کا قول ہے۔ یا وہ مادہ اور صورت سے مرکب ہے ؛جیسا کہ بہت سے فلاسفہ کی رائے ہے۔ یا پھر ان میں سے کسی ایک سے بھی مرکب نہیں ؛ جیسا کہ بہت سی جماعتوں کی رائے ہے۔ پس ان تین اقوال میں سے یہ تیسرا قول زیادہ صحیح ہے۔تینوں اقوال کے حاملین کا آپس میں اختلافہے ؛ کہ کیا وہ غیر متناہی حد تک تقسیم کو قبول کرتا ہے ؟صحیح یہ ہے کہ وہ غیر متناہی حد تک تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن جوہرِ فرد کے مثبتین کہتے ہیں کہ: وہ تقسیم ایک ایسی حد پر ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے وجودکے باوجود وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ حالانکہ حقیقتِ حال اس طرح نہیں ؛ بلکہ جب اجزاء بہت چھوٹے ہو جائیں تو وہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں ۔ جس طرح پانی کے اجزاء جب بہت چھوٹے ہو جائیں تو وہ ہوا میں تبدیل ہو جاتے ہیں ۔ پس جب وہ موجود ہوتے ہیں تو لفظ ’’ماء ‘‘کا مسمیٰ ہوتے ہیں ۔ پس ان میں کوئی بھی ایسی چیزنہیں پائی جاتی جس کا بعض بعض سے جدا نہ ہو سکے۔ جس طرح جوہر فرد کے مثبتین کہتے ہیں : اور اس کا غیر متناہی حد تک انقسام ممکن بھی نہیں ؛ بلکہ جب وہ بہت زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے تووہ خارجی تقسیم کو قبول نہیں کرتا ؛اگرچہ اس کا بعض دوسرے بعض کاغیر ہو۔بلکہ جب اس میں تقسیم یا اس جیسا کوئی اور تصرف کیا جائے تو اس کا استحالہ ہو جاتا ہے؛ اور حقیقت بدل جاتی ہے۔ پس چھوٹے اجزاء اگرچہ ان کا صغر(چھوٹا ہونا)کتنا ہی زیادہ ہو؛ تو ان میں تمیز اور تفریق کا امکان حس اور عقل دونوں سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے اجزاء کا ایک دو سرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ پھر خراب ہو جاتا ہے اور اس کے قوام میں ضعف کی وجہ سے استحالہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اتنے چھوٹے جسم کے ساتھ اس کا احتمال نہیں رکھتا؛یہ مقام اس مسئلہ کی تفصیل کا نہیں ۔پھر اجسام کے جواہرِ مفردہ سے مرکب ہونے کے قائلین کا آپس میں اختلاف ہے ؛کہ کیا وہ جوہر اس کے مثل کا اس کے ساتھ انضمام کے ساتھ مشروط ہے؛ یا وہ دو جوہر ہیں یا دو سے زیادہ یا چار یا چھ یا آٹھ یا سولہ اور یا بتیس ؟اِن کے یہ سب معروف اقوال ہیں ۔پس لفظِ’’ جسم ،جوہر اور متحیز‘‘ کے الفاظ میں مختلف آراء ہیں ۔لہٰذا اسی وجہ سے ان الفاظ اور اصطلاحات اللہ تعالیٰ پرکا اطلاق نفی و اثبات کسی بھی صورت میں جائز نہیں ۔ بلکہ جب کوئی یہ کہے کہ: باری تعالیٰ جسم ہے۔تو اس سے پوچاجائے گا کہ: کیا تمہاری مراد یہ ہے کہ وہ اجزاء سے مرکب ہے؛اس کی طرح جو پہلے وہ اجزاء متفرق تھے پھر ان کو آپس میں ملا دیا گیا ؟یا وہ تفریق کو قبول کرتا ہے ؟خواہ یہ کہا جائے کہ وہ بنفسہ جمع ہوئے ہیں ؛ یا غیر نے ان کو جمع کیا ہے ۔یا وہ مخلوقات میں سے کسی چیز کی جنس میں سے ہے ؟یا یہ کہ وہ مادہ اور صورت سے مرکب ہے ؟یا وہ جواہر فردہ سے؟اگر وہ یہ کہے کہ : وہ [اس معنی میں ]مرکب ہے۔‘‘ تو جواب میں کہا جائے گا:یہ عقیدہ باطل ہے۔اور اگر وہ کہے کہ : میری مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودیا قائم بنفسہ ہے۔ جس طرح کہ ہشام اور محمد بن کرام اور ان علاوہ ان لوگوں سے منقول ہے؛جو اس لفظ کا اطلاق کرتے ہیں ۔کہ بیشک وہ صفات سے موصوف ہے۔ یا یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے سکے گا؛ یا اس کی رؤیت ممکن ہے ؛یا وہ عالم سے مبائن اور الگ ہے یا وہ عالم پر محیط ہے؛ یا اس جیسے وہ معانی؛جو شریعت اور عقل سے ثابت ہیں ۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ:’’ یہ معانی فی الجملہ صحیح تو ہیں لیکن اس لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر شریعت میں ایک بدعت ہے؛ اور لغت کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ جب کسی لفظ کے معانی میں حق اور باطل دونوں کا احتمال ہو تو اسکا اطلاق کرنا درست نہیں ۔ بلکہ واجب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ حق کے اثبات میں اور باطل کی نفی کرنے والا ہو۔ یعنی وہ لفظ اپنے معنی میں محکم ہو اور یہ تو بہت سے باطل معانی کو بھی شامل ہے۔اور جب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے۔تو اس سے پوچھا جائے گا : کیا تمہاری مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی غیر نے ترکیب نہیں دیا ؟یا اس کے اجزاء متفرق نہیں تھے؛جن کو بعد میں ملایا گیا ہو ؟یا اللہ تعالیٰ تفریق اور جزء بندی کو قبول نہیں کرتے؟ جس طرح کہ محسوسات میں جسم کا بعض بعض سے جدا ہو جاتا ہے ؟یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جواہر فردہ سے مرکب نہیں ہے ؟یا یہ کہ نہ تو مادہ اور صورت سے مرکب ہے ؟اور اس جیسے اور معنی کا بھی نفی مراد ہے تمہاری ؟[ظاہر ہے کہ وہ ان میں سے کسی کے بارے میں تو جواب دے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ نفی بھی حق اور باطل دونوں معانی کے نفی کو شامل ہے لہٰذا فسادِ معنی کی وجہ سے تیرا یہ نفی کرنا بھی شریعت میں بدعت ہے ]۔