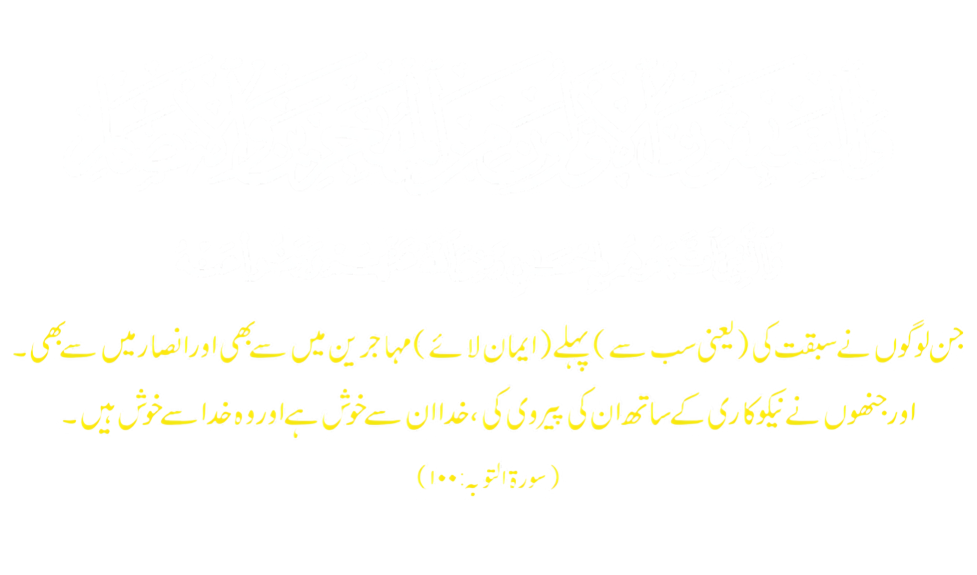فصل: منکرین صفات سے مناظرہ کرنے کے لیے تجاویز:یہ بات اس چیز سے بھی واضح ہوجاتی ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عیوب اور نقائص سے تنزیہ پر متفق ہیں ۔ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ صفاتِ کمال سے متصف ہے۔ لیکن بعض امور میں ان کا آپس میں جھگڑا ہے۔ مثلا: نقص سے مراد صفات کی نفی ہے یا اثبات؟ اسے جاننے کا طریقہ۔اس امامی مصنف نے معتزلہ اور ان کے پیروکاروں کے طریقہ کار کو اختیار کیا ہے کہ اصلاً رب تعالیٰ کی نقائص سے تنزیہ تبھی ہوسکتی ہے جب اس کے جسم ہونے کی نفی کی جائے۔ جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ کتاب وسنت اور سلف صالحین نے یہ طریقہ کار نہیں اپنایا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان کے جمہور ساتھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ۔ لیکن ان کا دعوی ہے کہ یہ بطریق عقل یہ چیز معلوم شدہ ہے۔ ان میں سے اپنے طریقہ کار میں بدنام لوگ کہتے ہیں : یہ بھی باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لازما جسم ہونے کی وجہ سے کچھ نقائص اور عیوب سے تنزیہ ممکن نہیں ہے ۔ کیونکہ کوئی بھی صفت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں کہنے والا کہتا ہے کہ یہ تجسیم کو مستلزم ہے، تو اثبات کے بارے میں جو قول ہے، نفی کے بارے میں وہی قول ہے۔ تو لازم ہے کہ وہ کسی چیز کا اثبات کرے وگرنہ قدیم موجود اور واجب بنفسہ کی نفی لازم آئے گی۔ اس وقت کسی صفت کے بارے میں کہے گا: یہ صرف کسی جسم کی ہی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اسے وہی کچھ کہا جائے جو اثبات میں کہا گیا تھا۔ اگر وہ نقص والی صفت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو جہل، عجز اور نیند وغیرہ سے منزہ قرار دینا چاہتا ہے تو یہ صفات اجسام کی ہی ہوتی ہیں ۔ اسے کہا جائے گا: تم جن اسما، احکام یا صفات کا اثبات کرتے ہو، وہ تو صرف اجسام کی ہوتی ہیں ۔اس وجہ سے جو لوگ اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ کو عیوب اور نقائص سے متصف قرار دینے والوں کی تردید کرتے ہیں ، ان کی اپنی کلام متناقض ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ، اس کے رسول اور سلف میں سے کسی ایک نے بھی یہود وغیرہ کی تردید کے لیے اس طریقہ پر اعتماد نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو نقائص سے متصف قرار دیتے تھے، مثلا: بخل، فقر، تھکاوٹ، بیوی، اولاد اور شریک وغیرہ۔ پھر بہت سے وہ لوگ جو اس طریقہ پر عمل پیرا ہیں ، حتی کہ صفاتیہ میں سے بھی، وہ کہتے ہیں : رب تعالی کا نقص سے مبرا ہونا اور کمال سے متصف ہونا ہم عقل سے نہیں ، نقل سے جانا جاتا ہے۔ اسی پر قابل اعتبار اجماع ہے۔ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا عقلی طریقہ کار نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کو نقائص سے منزہ قرار دے سکیں ۔ جس اجماع پر انہوں نے اعتماد کیا ہے، وہ اجمال میں تو فائدہ دیتا ہے، تفصیل میں فائدہ نہیں دیتا۔[1][1] یہاں پر اس اجماع کی بات ہورہی ہے جو ابن مطہر، امامیہ اور نفاۃ کے نزدیک ثابت شدہ ہے۔جبکہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا تو تفصیل میں ہی ہے۔متنازعہ امور میں اجماع سے احتجاج ممنوع ہے۔ پھر جس اجماع کی وہ بات کرتے ہیں ، وہ بعض نصوص کے سہارے کھڑا ہے۔ جبکہ نصوص کی صفاتِ کمال پر دلالت اس سے کہیں زیادہ ظاہر وباہر ہے جتنی اجماع کے حجت ہونے پر ہے۔ جب صفات کی نفی کرنے والوں کے اصولوں کی کمزوری ظاہر ہوگئی جن کے ذریعہ وہ رب تعالی کی تنزیہ کرتے تھے تو یہ روافض مختلف مذاہب کے دروازوں کے چکر کاٹنے لگے اور آخر کار انہوں نے گھٹیا ترین مفاہیم کو اختیار کرلیا۔ عقلیات میں ان کا اعتماد باطل عقلیات پر ہے۔ اور نقلیات میں بھی باطل نقلیات پر ان کا اعتماد ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں سے حجت کے اعتبار سے یہ لوگ کمزور ترین ہیں اور مقاصد کے اعتبار سے زیادہ جکڑ بندیوں کا شکار ہیں ۔ ان کے ائمہ میں سے اکابر پر زندیقیت اور فساد کا الزام تھا جیساکہ ان کے بہت سے اکابرین سے الزامات موجود ہیں ۔یہاں پر ہمارا مقصود یہ ہے کہ اس مسئلہ میں لوگوں نے مجمل الفاظ کے ذریعہ گفتگو کی ہے، مثلا: ترکیب، انقسام، تجزئہ اور تبعیض وغیرہ۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منقسم ہونے والا، ٹکڑے ہونے والا، تقسیم ہونے والا اور مرکب وغیرہ نہیں ہے ۔ تو اگر اس کی مراد وہ معنی ہوتا ہے جو لغت میں ان الفاظ کا معروف معنی ہے تو اس بارے میں مسلمانوں کے ہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے منزہ ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ متفرق اجزا سے مرکب ہے۔ چاہے یہ کہا جائے کہ وہ خود ہی جڑ گیا تھا یا کسی دوسرے نے اسے جوڑا تھا۔ نہ یہ کہنا جائز ہے کہ وہ ایسا مرکب ہے جو تفریق، تجزئہ اور تبعیض کے لائق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ متفرق تھا، پھر جمع ہوگیا۔ جیسا کہ اجسام کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگرچہ اس نے حیوانات اور نباتات کو پیدا کیا ہے اور انہیں آہستہ آہستہ پروان چڑھایا ہے، انسان کا ہاتھ، پاں اور سر جدا جدا نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جمع کردیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان اعضا کو اکٹھے ہی پیدا کیا ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض کا دوسروں سے جدا ہونا ممکن ہے۔ تو یہ کہنا ممنوع ہے کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تفریق، تجزئہ اور تبعیض کے لائق ہے۔ یہ دونوں مفاہیم متفق علیہ ہیں ۔ میں کسی مسلمان کا اس کے خلاف قول نہیں جانتا۔
اگر وہ کہے: ترکیب سے مراد یہ ہے کہ وہ مفرد جواہر یا مادہ اور صورت سے مرکب ہے۔ تقسیم اور تجزئہ سے وہ ان اجزا پر مشتمل ہے تو جمہور عقلا کہتے ہیں : یہ مخلوقات جن کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے، مثلا: سورج، چاند، ستارے، ہوا، آگ اور مٹی، یہ نہ اس ترکیب سے جڑی ہیں ، نہ اس ترکیب سے۔ تو رب العالمین کے بارے میں کیسے مان لیا جائے؟ کیونکہ صریح عقل سے یہ بات معلوم ہے کہ وہ مخلوق جس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے، جو دوسروں سے بلند ہے جیسے آسمان زمین سے بلند ہے، جب جمہور عقلا کہتے ہیں کہ وہ جدا ہونے والے اجزا سے مرکب نہیں ہے، جبکہ قائلین کے ہاں وہ مفرد جواہر ہیں ، اور نہ مادہ اور صورت سے ، تو ان کا رب العالمین کے اِس یا اس سے مرکب ہونے سے روکنا زیادہ لائق ہے۔البتہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جن کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے، اس اور اس سے مرکب ہیں ۔ تو انہی میں سے معتزلہ اور اشاعرہ جیسے بہت سے لوگ رب تعالی سے اس ترکیب کی نفی کرتے ہیں ۔ لیکن بہت سے متکلمین کہتے ہیں : اللہ تعالیٰ جسم ہے۔ تو جب وہ ان لوگوں میں سے ہو جو کہتے ہیں کہ جسم مفرد اجزا یا مادہ اور صورت سے مرکب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اور اس اعتبار سے مرکب ہے۔جمہور مسلمانوں کے نزدیک یہ قول باطل ہے۔ لیکن جمہور عقلا جو مخلوقات میں اس ترکیب کی نفی کرتے ہیں ، خالق میں تو زیادہ سختی سے اس ترکیب کی نفی کرتے ہیں ۔جو یہ کہتا ہے کہ جس مخلوق کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے، وہ اس ترکیب سے مرکب ہے تو یہ لوگ رب تعالی سے اس چیز کی نفی کرنے کے لیے عقلی دلیل کے محتاج ہیں جو اس قسم کے امتناع کو بیان کرے۔ کیونکہ ان کے مد مقابل وہ لوگ جو اس معنی کے اثبات کے قائل ہیں ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو مرکب مانتے ہیں ، وہ کہتے ہیں : ہمارے مخالفین کے پاس نفی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ جن مقدمات میں وہ ہمارے موافق ہیں جن سے حاضر میں اس ترکیب کا اثبات ہوتا ہے، وہی مقدمات اس ترکیب کے غائب میں ہونے کے دلیل ہیں ۔اور بہت سی مثالیں موجود ہیں جن میں غائب پر حاضر سے استدلال کیا گیا ہے۔ دونوں گروہوں میں اس مسئلہ میں بہت سے عقلی، لفظی اور لغوی جھگڑے ہیں ۔ جو کسی اور جگہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں ۔جمہور عقلا، سلف اور ائمہ کے نزدیک دونوں گروہ غلطی پر ہیں ۔ رب تعالی کی اس سے تنزیہ عقل وشریعت سے واضح ہے۔ جیسا کہ فاسد شبہات کو واضح کیا گیا ہے۔البتہ جب یہ کہا جائے کہ انقسام یا ترکیب سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے ممتاز ہوجائے ، مثلا: علم قدرت سے ممتاز ہوجائے یا ذات صفات سے ممتاز ہوجائے یا نظر آنے والی چیز نظر نہ آنے والی چیز سے ممتاز ہوجائے ، جیسے سلف درج ذیل آیت کے بارے میں کہتے ہیں :﴿ لَا تُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ﴾[ الانعام: 103] ’’ نگاہیں اسے پا نہیں سکتیں ۔‘‘یعنی اس کا احاطہ نہیں ہوسکتا۔ ابن عباس سے کسی نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا: :﴿ لَا تُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ﴾آپ نے پوچھا: کیا تم آسمان دیکھتے ہو؟ اس نے کہا: بالکل۔ پوچھا: کیا پورا دیکھ لیتے ہو؟ اس نے کہا: نہیں ۔ تو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ہوگا لیکن ادراک نہیں ہوگا یعنی احاطہ نہیں کیا جائے گا۔ وغیرہ۔لہٰذا اس امتیاز کی دو قسمیں ہیں :ہم میں سے عالم کے علم میں امتیازہے۔ ہم کچھ چیزیں جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔اس بات کے سمجھنے کے بعد کوئی بھی عاقل اس میں جھگڑ نہیں سکتا۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ اس میں کوئی جھگڑا ہے تو انسان بعض اوقات یہ جاننے سے پہلے کہ وہ عالم ہے، یہ جانتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ قادر ہے اس سے پہلے کہ وہ جانے کہ وہ مرید [ارادہ کرنے والا]ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ جانتا ہے اور کچھ چیزیں نہیں جانتا۔ لہٰذا لوگوں کے علم میں سے کچھ چیزوں کو جاننے اور کچھ کو نہ جاننے میں امتیاز ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی عاقل جھگڑ نہیں سکتا۔ ہاں البتہ لفظی جھگڑا ہوسکتا ہے یا انسان ایسی بات کرسکتا ہے جس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔امتیاز کی اس صورت کے اثبات پر اتفاق ہے۔ جس طرح کہ پہلی صورت کی نفی پر اتفاق ہے۔ جہاں تک حقیقت میں بغیر تفرق وانفصال قبول کیے امتیاز کی بات ہے جیسے علم کو قدرت سے ممتاز کرنا، ذات کو صفت سے ممتاز کرنا، سماعت کو بصارت سے ممتاز کرنا، دیکھی جاسکنے والی چیز کو نہ دیکھی جاسکنے والی چیز سے ممتاز کرنا وغیرہ ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ثبوت اور تنوع کی بات ہے تو صفات کی نفی کرنے والے جہمیہ اسی کی نفی کرتے ہیں ۔ ان کی اسی نفی کی وجہ سے سلف اور ائمہ نے ان پر تنقید کی ہے۔ جیسا کہ جہمیہ کی تردید لکھنے والے مسلمان مصنفین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔مثلا امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ مسلمان ائمہ کی جہمیہ کے رد میں تحریریں دیکھی جاسکتی ہیں۔[1][1] الرد علی الجہمیۃ للامام أحمد بن حنبل، ص 32۔ 1لیکن مسلمان ائمہ میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ رب تعالی مفرد جواہر سے یامادہ اور صورت سے مرکب ہے۔ مناظرین کا اجسام مشہودہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ جواہر اور اجزا سے مرکب ہیں یا نہ اس سے مرکب ہیں اور نہ اس سے۔ اس بارے میں تین اقوال ہیں ۔کچھ نے کہا ہے: مخلوق نہ اس سے مرکب ہے، نہ اس سے مرکب ہے۔ لہٰذا خالق اس کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ مرکب نہ ہو۔
کچھ نے کہا ہے: مخلوق مرکب ہے۔ یہ لوگ دو باتوں میں سے ایک کے ضرور قائل ہوں گے: یا تو رب تعالی سے ترکیب کی نفی کریں گے اور اس کیلیے دلیل کے محتاج ہوں گے۔ اس بارے میں ان کے جو بھی دلائل ہیں ، بہت کمزور ہیں ۔ یا پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس اور اس سے مرکب ہونے کا اثبات کریں گے۔ یہ بہت بیہودہ اور لغو قول ہے۔ لہٰذا یہ دونوں قول چاہے نفی والا ہو یا اثبات والا، دونوں نہایت کمزور ہیں کیونکہ جس بنیاد پر یہ اقوال موجود ہیں ، وہ خود ہی بہت کمزور ہے۔اس موقع پر عقلاء کی طرف سے خالق اور مخلوق کی صفات کے بارے میں بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں ۔ مثال کے طور پر پھلوں کو دیکھیں ، مثلا: سیب اور چکوترا، دونوں کا ایک خاص رنگ، ذائقہ اور خوشبو ہے۔ یہ ایسی صفات ہیں جو ان میں ہمیشہ سے موجود ہیں اور رہتی ہیں ۔ اسی طرح ان کی حرکت بھی ہوتی ہے۔ بعض مناظرین کہتے ہیں : ان پھلوں کی صفات ان کی ذات سے جدا کوئی چیز نہیں ہیں ۔ ان کے نزدیک لفظ سیب میں یہ ساری صفات موجود ہیں ۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ نہیں ، صفات ذات سے زائد ہیں ۔ درحقیقت یہ صرف لفظی جھگڑا ہے۔ کیونکہ اگر ذات سے مراد وہ مجرد ذات ہو جس کا ذہن میں تصور آسکتا ہے تو بلاشبہ اس ذات سے صفات زائد ہی ہوں گی۔ اگر ذات سے وہ ذات مراد ہو جو خارج میں موجود ہے تو وہ ذات ان صفات سے متصف ہے۔ خارج میں ایسی کوئی ذات موجود ہی نہیں جو اپنی لازمی صفات سے متصف نہ ہو۔لہٰذا خارج میں یہ خیال کرنا کہ ذات صفات سے جدا ہوگی اور یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ صفات زائد ہیں یا نہیں ہیں ، تو ایسا سوچنا بھی غلط ہے۔ جو سوچنا ممنوع ہے، اس کا حکم بھی ممنوع ہے۔عبد الرحمن بن کیسان اصم جیسے مناظرین کے ایک گروہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خارج میں اعراض کے وجود کے منکر ہیں ۔ یہاں تک کہ انہوں نے حرکت کے وجود کا بھی انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں لیکن لگتا یوں ہے کہ ان کا قول صحیح طرح بیان نہیں کیا گیا۔ کیونکہ یہ عاقل لوگ اس طرح کی بات نہیں کرسکتے۔ اور عبد الرحمن الاصم ، اگرچہ معتزلی تھا ، لیکن صاحب ِ فضیلت اور عالم شخص تھا۔ اس نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے۔ اس کے شاگروں میں ایک نمایاں نام ابراہیم بن اسماعیل بن علیہ کا ہے۔ ابراہیم فقہ اور اصول فقہ میں امام شافعی وغیرہ سے مناظرے کیا کرتے تھے۔ الغرض یہ لوگ بہت ذہن وفطین تھے۔ اگر کسی مسئلہ میں ان کو غلطی لگی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان عام سی باتوں میں بھی یہ گمراہ تھے جو بچے بھی جانتے ہیں ۔یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر اور انجینئر بہت ذہین ہوتے ہیں ۔ طبی اور حسابی معاملات کو خوب جاننے والے ہوتے ہیں ۔ اگرچہ ان میں سے بعض لوگ الہیاتی معاملات میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں ۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ طب اور حساب کے واضح امور میں بھی یہ غلطی پر ہوں گے۔ لہٰذا جو شخص ارسطو اور جالینوس وغیرہ کے طبیعات کے بارے میں ایسے اقوال نقل کرتا ہے جو واضح طور پر باطل ہیں تو سمجھ لیا جائے گاکہ اسے نقل کرنے میں غلطی لگی ہے، اگراس نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا۔بلکہ محمد بن زکریا رازی الہیات اور نبوات کے مسائل میں اپنے الحاد اور قدماء خمسہ کے قائلین دیمقراطیس اور حرنائین کے قول کی تائید کے باوجود ،[حالانکہ یہ قول بہت کمزور ہے اور اس میں تناقض اور بگاڑ ہے جس کی وضاحت کسی اور جگہ مذکور ہے، مثلا: شرح اصبہانیہ، معجزات انبیا پر گفتگو اور درج ذیل قول کے قائل کا رد کہ یہ نفسانی قوتیں ہیں جنہیں صفدیہ کہا جاتا ہے وغیرہ] طب میں تمام لوگوں سے زیادہ باخبر تھا، حتی کہ اسے اسلامی جالینوس کہا جاتا تھا۔ لہٰذا اگر کوئی اس کی طرف طب کا ایسا مسئلہ منسوب کرے جس کا بگاڑ ابتدائی طبیب کے سامنے بھی بالکل واضح ہو، تو دراصل وہ مسئلہ اس پر گھڑا گیا ہوگا۔اسی طرح عبد الرحمن بن کیسان اور اس جیسے لوگ اس بات کے انکاری نہیں ہوسکتے کہ پھل کا ذائقہ، رنگ اور خوشبو ہوتی ہے۔ مناظرین کی اصطلاح میں اعراض سے یہی کچھ مراد ہوتا ہے۔لہٰذا یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ اعراض کے منکر ہیں ؟بلکہ جب انہوں نے کہا کہ اعراض جسم سے زائد صفات نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جسم اس ذات کا نام ہے جس میں یہ اعراض موجود ہیں ۔ لہٰذا عرض جسم کے مسمی میں شامل ہے۔ یہ بات اس کی اور اس جیسے دوسرے لوگوں کی ہوسکتی ہے۔پھر میں نے ابو الحسین بصری کو دیکھا جو متاخرین معتزلہ میں سے ہے اور اپنے فن کا ماہر ہے، اس نے اپنی کتاب تصفیح الأدلۃ والأجوبۃ میں یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ اور یہ ذکر کیا ہے کہ ان کی مراد بھی یہی مفہوم ہے۔ پھر اس نے ان کا کلام ذکر کیا ہے جو اس چیز کی وضاحت کررہا ہے۔ تو اس نے اسی مفہوم کو اختیار کیا ہے اور ان احوال کا اثبات کیا ہے جسے اس کے علاوہ دیگر لوگ زائد اعراض کا نام دیتے ہیں ۔ یوں جمہور کا نزاع لفظی امور تک محدود ہوگیا ہے۔جب اصل بات یہ ہے تو معلوم ہے کہ ہم ذائقہ، رنگ اور خوشبو میں اپنے حواس سے امتیاز کرسکتے ہیں ۔ ذائقہ کو ہم منہ سے محسوس کرتے ہیں ، رنگ کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور خوشبو کو ناک سے سونگتے ہیں جیسے آوازیں ہم کانوں سے سنتے ہیں ۔ تویہاں ایسے آلات ہیں جن کے ذریعہ ہمارے اندر پائے جانے والے مختلف اعراض کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ان کا اختلاف بذاتِ خود انہی میں ظاہر ہوجاتا ہے ان آلات کے مختلف ہونے کی وجہ سے جو ان اعراض کا ادراک کرتے ہیں ۔ جبکہ اس کے برخلاف ہمارے اندر جو علم، ارادہ اور محبت کے جذبات موجود ہیں ، ہم انہیں مختلف حواس کے ذریعہ ایک دوسرے سے ممتاز نہیں کرسکتے ، اگرچہ انہیں جاننے کے دلائل مختلف ہیں ۔ کیونکہ بعض اوقات دلائل مستدِل سے جدا امور ہوتے ہیں ۔تو یہ وہ بات ہے جس کے ذریعہ حواس سے محسوس ہونے والی اور عقل سے معلوم ہونے والی صفات کے درمیان فرق ہوجاتا ہے۔ وگرنہ یہ بات تو معلوم ہے کہ سنگترہ اور سیب کا اپنی مختلف صفات سے متصف ہونا بذاتِ خود ثابت شدہ معاملہ ہے چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ ان کا ذائقہ ان کا رنگ نہیں ہوتا اور رنگ خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ سب ایسی مختلف صفات ہیں جو اپنے حقائق سمیت قائم ہیں اگرچہ ان کا موصوف ایک ہی ہے۔پھر صفات کی دو قسمیں ہیں ۔ ایک قسم وہ ہے جس کے لیے زندگی ضروری نہیں ہے، مثلا: ذائقہ، رنگ اور خوشبو۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے وجود کے لیے زندگی ضروری ہے۔ مثلا: علم، ارادہ، سماعت اور بصارت۔پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتیں ۔ لہٰذا رنگ، خوشبو اور ذائقہ سے اسی چیز کو متصف کیا جائے گا جس میں یہ صفات موجود ہوں گی۔جبکہ دوسری قسم کے بارے میں مناظرین کا اختلاف ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انسان کی صفت بیان کی جاتی ہے کہ وہ عالم ہے، قادر ہے، ارادہ رکھنے والا ہے جبکہ علم اور ارادہ نہ پشت پر ہوتا ہے ، نہ پیچھے ہوتا ہے، بلکہ وہ دل میں ہوتا ہے۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا: زندگی سے مشروط اعراض کا حکم اپنے محل سے متعدی ہوتا ہے۔ اگر مجموعہ میں سے کسی ایک جز میں بھی وہ عرض ہوگا تو پورے مجموعہ کو اس سے متصف کیا جائے گا۔ معتزلہ وغیرہ میں سے کچھ لوگ ایسا ہی کہتے ہیں ۔ جبکہ ان میں بعض کہتے ہیں : اس صفت سے متصف موصوف دل میں ایک علیحدہ ٹکڑا ہے۔ انہی میں سے کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے : بلکہ اس کا حکم اپنے محل سے آگے نہیں بڑھتا۔ بدن کے ہر حصہ میں زندگی، علم اور قدرت ہوتی ہے۔ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان اعراض کے علیحدہ جوہر کے ساتھ قائم ہونے کیلیے مخصوص جگہ کی کوئی شرط نہیں ہے جیساکہ اشعری اور ان کے مالکی، شافعی اور حنبلی پیروکار وغیرہ کہتے ہیں ۔انہوں نے اس موقف کی بنیاد علیحدہ جوہر کے ثبوت پر رکھی ہے۔ جبکہ یہ کمزور بنیاد ہے۔ کیونکہ اس کا قائل ہونا باطل ہے۔ جیسا کہ یہ بات اپنی جگہ پر تفصیل سے بیان کی جاچکی ہے۔بعض ارسطو کے پیروکار زبردستی کے فلسفی یہ دعوی کرتے ہیں کہ انسان میں علم کا محل ناقابل تقسیم ہے۔ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ناطقہ میں علم ایک چیز کو دوسری چیز سے ممتاز نہیں کرسکتا۔ نہ وہ متحرک ہے، نہ ساکن ہے۔ نہ وہ چڑھتا ہے، نہ اترتا ہے۔ نہ وہ بدن اور دنیا کی کسی اور چیز میں داخل ہوتا ہے اورنہ اس سے نکلتا ہے۔ نہ کسی چیز کے قریب ہوتا ہے، نہ دور ہوتا ہے۔پھر ان میں سے کچھ لوگ دعوی کرتے ہیں کہ نفس ناطقہ کلیات جانتی ہے، جزئیات نہیں جانتی۔ جیسا کہ ابن سینا وغیرہ کا یہ موقف بیان کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں ان کا سب سے زیادہ اعتماد ان معلومات پر ہے جو ناقابل تقسیم ہے، لہٰذا ان کا علم بھی ناقابل تقسیم ہے کیونکہ علم معلوم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے علم کا محل بھی ناقابل تقسیم ہے۔ کیونکہ جو تقسیم ہوتا ہے وہ کسی منقسم میں نہیں رہتا ہے۔‘‘[1][1] دیکھیے: کِتاب الشِفائِ لِابنِ سِینا، الفن السادِسِ مِن الطبِیعِیاتِ 1 وما بعدہا، ط براغ، تِشِیکوسلوفاکیا، 1956 ص9 87 وما بعدہا، ط. الہیئِۃ العامۃِ لِلکِتابِ، تحقِیق جورج قنواتِی، سعِید زایِد، القاہِرۃ 1395۔اس پر تفصیلی گفتگو کسی اور مقام پر ہوچکی ہے۔ اس کلام میں جو کچھ غلطیاں ہیں ، وہ بھی وہاں بیان کردی گئی ہیں ۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کے نزدیک یہ وہ برہان قاطع ہے جس کا توڑ ممکن نہیں ۔ انہیں یہ بات اس لیے بھی پختہ لگتی ہے کیونکہ ان کے غزالی اور رازی جیسے ان کے مخالفین نے اس کا کوئی شافی جواب نہیں دیا تھا۔ بلکہ غزالی تو بعض اوقات اس پر ان کی موافقت کرتے تھے۔ جھگڑے کی وجہ اس چیز کا اثبات ہے جو معنوی طور پر ناقابل تقسیم ہے جسے وہ خارجی طور پر چاہتے ہیں ۔ان سے کہا جائے گا: ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وجود میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے ممتاز نہیں کرسکتی۔ اگر وہ کہیں : نقطہ؟ تو ان سے کہا جائے گا: نقطہ، خط اور سطح، ایک، دو اور تین، کبھی ان سے موصوفات سے مجرد یہی مقداریں مراد ہوتی ہیں ۔ اور کبھی ان سے وہ مقدرات مراد ہوتی ہیں جو خارج میں موجود ہوتی ہیں ۔اگر پہلی چیز مراد ہو تو اس کا تو صرف اذہان میں وجود ہوتا ہے، خارج میں نہیں ۔ خارج میں ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا جس کا کوئی معدود نہ ہو اور نہ کوئی ایسی مقدار جس کا مقدر نہ ہو۔ نہ کوئی نقطہ، نہ کوئی خط، نہ کوئی سطح، نہ ایک، نہ دو اور نہ تین۔ بلکہ معدودات موجود ہوتی ہیں مثلا: درہم، دانہ اور انسان۔ اور مقدرات بھی ہوتی ہیں مثلا: زمین جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر سطح کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے جس سے وہ دوسری سطحوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ جس طرح مٹی پانی سے ممتاز ہوتی ہے اور جس طرح ہر جسم کی سطحیں دیگر اجسام کی سطحوں سے ممتاز ہوتی ہیں ۔اگر وہ کہیں : ناقابل تقسیم چیز سے مراد عقول مجردہ ہیں جن کا فلسفی اثبات کرتے ہیں ۔لیکن اس چیز کا اثبات ناممکن ہے۔ اس کا تحقق اذہان میں تو ہوسکتا ہے، اعیان میں نہیں ۔فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول کی صفت سے متصف کیا ہے اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان کے اور ان مجردات کے درمیان اتنا فرق ہے جو صرف کسی اندھے پر ہی مخفی رکھتا ہے۔ جیسا کہ یہ بات کسی دوسری جگہ تفصیل سے بیان کی جاچکی ہے۔اگر ان کی مراد ناقابل تقسیم واجب الوجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے۔ ناقابل تقسیم اور اجزا سے مرکب نہیں ہے۔تو ان سے کہا جائے گا: اگر اس سے تمہاری مراد صفاتِ باری تعالی کی نفی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میں زندگی،علم اور قدرت نہیں ہے ۔ تو تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمام مسلمانوں اور دیگر اقوام بلکہ بنی آدم کے تمام عقلا ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو، اس مسئلہ میں تمہارے مخالف ہیں ۔یہ پہلا مسئلہ ہے اور تمہاری اور ہر عاقل کی بھی، کچھ صفات معلوم ہوتی ہے اور کچھ نامعلوم ہوتی ہیں ۔ جو معلوم ہوتی ہیں ، وہ نامعلوم کے علاوہ ہوتی ہیں ۔ لہٰذا اس بات کا کیسے انکار کیا جاسکتا ہے کہ متعدد صفات نہیں ہیں ؟ صانع کے اثبات کے دلائل بہت زیادہ ہیں ، انہیں بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو تم خارج میں اس کے وجود کی حقیقت کی بجائے امکان کے کیوں قائل ہو؟صفات کے نفی کے بارے میں تمہارے دلائل کا بگاڑ واضح ہوچکا ہے، اگرچہ تم اسے توحید کا نام دیتے ہو۔ تو اس وقت وہ واحد شے جس کے ایک جزء کی دوسرے جزء سے تمیز نہ ہوسکے، خارج میں اس کا کوئی ثبوت معلوم نہیں حتی کہ اس بات کی دلیل لی جائے کہ اس کے بارے میں علم بھی ایسا ہی ہے اور عالم بھی ایسا ہی ہے۔ان میں سے بعض نے اپنے مفہوم کے مطابق ناقابل تقسیم وجود کے بارے دلیل دیتے ہوئے کہا ہے: خارج میں وجود یا تو بسیط ہوتا ہے یا مرکب۔ مرکب کے لیے بسیط ہونا لازم ہے۔ جبکہ یہ ممنوع ہے۔ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ایسا وجود ہوسکتا ہے جو اس بسیط سے مرکب ہو جس کا تم اثبات کرتے ہو۔ موجود تو صرف اجسام بسیطہ ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہ ہیں ، مثلا: پانی، آگ، ہوا اور اس جیسی دیگر چیزیں ۔جہاں تک ان چیزوں کی بات ہے جن کا ایک جز دوسرے جز سے تمیز نہیں کیا جاسکتا، تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی ایسا وجود بھی ہے جو اس چیز سے مرکب ہو، بلکہ موجود صرف وہی ہے جس کا ایک جز دوسرے جز سے تمیز ہوسکتا ہے۔جب وہ کہتے ہیں : یہی چیز ہی بسیط ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا: ایسا تبھی ہوگا جب اس کا بعض حصہ دوسرے حصہ کا غیر ہوگا۔ اسے قطعاً مفرد نہیں جانا جاتا جیسے مفرد قطعا نہیں پایا جاتا۔پھر کہا جائے گا: یہ بات معلوم ہے کہ انسانی بدن اس مفہوم کے اعتبار سے جو وہ بیان کرتے ہیں ، قابل تقسیم ہے اور ایک اجزا ایک دوسرے سے علیحدہ طور پر تمیز کیے جاسکتے ہیں ۔ زندگی اور حواس پورے بدن میں موجود ہے۔ تو اس میں کیا مانع ہے کہ حیات اور علم روح کے ساتھ قائم ہو جس طرح زندگی اور حواس بدن سے قائم ہیں ؟ اگرچہ تمہارے نزدیک بدن قابل تقسیم ہے۔اگر تم کہو کہ تمہارے نزدیک زندگی اور حس بھی قابل تقسیم ہے تو کہا جائے گا: اگرتمہارا مطلب یہ ہے کہ جسم کے بعض حصوں کا دوسرے حصوں سے جدا ہونے کے ساتھ ساتھ زندہ اور حساس ہونا ممکن ہے ۔ کہا جائے گا: یہ کوئی مستحکم بات نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات جسم کا ایک حصہ ختم ہوجاتاہے اور بقیہ حصوں میں زندگی اور حس باقی رہتی ہے۔ اور کبھی بعض حصہ سے حیات اور حس کے جانے کی وجہ سے بقیہ حصے سے بھی حیات اور حس چلی جاتی ہے، مثلا: دل سے۔دونوں باتوں کو مدنظر رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حیات اور حس اپنے محل کے پھیلنے کی وجہ سے پھیلتی ہیں ۔ ارواح مختلف ہوتی ہیں اور اس میں جو علم اور ارادہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔ تو موصوف جس قدر بڑا ہوگا، اس کی صفات بھی اتنی بڑی ہوں گی۔ اگرموصوف چھوٹا ہوگا تو صفات بھی ایسی ہی ہوں گی۔اسی طرح ان کے نزدیک وہم ایک جسمانی قوت ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہے، باوجود اس کے کہ یہ جسمانی قوت محسوس چیزوں میں سے ان کو بھی پالیتی ہے جو قابل محسوس نہیں ہوتیں ، مثلا: دوستی اور دشمنی۔ یہ وہی چیز ہے جو ان کے نزدیک اپنے محل کے قابل تقسیم ہونے کے باوجود ناقابل تقسیم ہے۔اسی طرح قوت بصارت جو آنکھ میں ہوتی ہے اور جسم کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ان کے نزدیک قابل تقسیم ہے جبکہ یہ اپنے محل کی تقسیم کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اتصال شرط ہے۔ اگر اس کا بعض محل فساد کا شکار ہوجائے تو یہ بھی بگڑ جاتی ہے۔ اپنے کسی حصہ کے بگاڑ کے ساتھ اس کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو حیات، علم، قدرت اور ارادہ کے روح کے کچھ حصہ کے ساتھ قائم ہونے میں کیا چیز مانع ہے؟جب کہا جاتا ہے: اس کا بعض دوسرے حصہ سے ممتاز ہوتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ دوسرے بعض حصہ کے ساتھ اس کا قیام ہو، اس حیثیت سے کہ اس اتصاف میں اتصال شرط ہو؟ جیسا کہ یہی چیز حیات اور حس کے جسم کے کچھ حصہ میں ہونے پر پائی جاتی ہے۔ حیات اور حس قائم نہیں رہ سکتی الا یہ کہ وہ متصل ہو۔ان جیسے بہت سے امور میں تفصیلی گفتگو کا تعلق انسانی روح، جسے نفس ناطقہ کہا جاتا ہے، پر گفتگو سے ہے اور اس کے اپنی صفات سے متصف ہونے سے ہے۔ اس کے ذریعہ انسان صفات ِالہی پر گفتگو میں مدد حاصل کرتا ہے۔ اسی کے ذریعہ انسان وارد ہونے والے شبہات کے رد میں مدد حاصل کرتا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر بہت سے مقامات پر تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے۔لوگ انسانی روح کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ کیا یہ مفرد جواہر سے یا مادہ اور صورت سے مرکب جسم ہے یا ایسا جوہر ہے جو صعود ونزول اور قرب وبعد وغیرہ کو قبول نہیں کرتا؟یہ دونوں قول غلط ہیں جیسا کہ کسی اور جگہ واضح کیا جاچکا ہے۔[1][1] دیکھیے: رِسالۃ فِی العقلِ والروحِ لِابنِ تیمِیۃ، جو کہ مجموعہ رسائل منیریہ کے دوسرے حصہ میں مطبوع ہے۔ ط. القاہِرِ، 1343. بعد میں یہ مجموع الفتاوی میں نشر کیا گیا ہے۔ ط۔ الرِیاضِ 4؍216 ۔ 231.اس سے بھی ضعیف قول ان لوگوں کا ہے روح کو حیات اور علم جیسے جسمانی اعراض جیسا کوئی عرض سمجھتے ہیں ۔پہلے قول میں ہی ان لوگوں کا قول شامل ہے جو کہتے ہیں کہ انسان صرف قابل مشاہدہ مجموعہ کا نام ہے۔ یعنی صرف جسم پر مشتمل ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح اعضا بدن میں چلنے والے سانس کو کہتے ہیں ۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ خون ہی روح ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روح وہ لطیف بخارات ہیں جو رگوں میں چلتے پھرتے ہیں ۔ اطبا کے نزدیک بھی اسے ہی روح کہتے ہیں ۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے اقوال ہیں ، وہ اس کے تحت آتے ہیں ۔دوسرا قول فلسفیوں اور ان کی موافقت کرنے والے مناظرین کا ہے۔ بسا اوقات انسان ان مسائل پر لکھی گئی کتب میں بہت سے اقوال پڑھتا ہے لیکن درست قول ان میں نظر نہیں آتا۔جو شخص علم میں متبحر ہوتا ہے، اس کے سامنے ان مسائل کا خلاصہ اور حق بات واضح ہوجاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حق وہی ہے جو صادق ومصدوق نے بتایا ہے جو اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے بلکہ وحی ہوتی تھی جو ان کی طرف کی جاتی تھی تمام معاملات میں ۔ لیکن اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو موجودہ کتاب سے مناسبت نہیں رکھتی۔ یہاں پر یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تنبیہ کرنا تھا کہ روافض اہل سنت پر ضعیف ترین اقوال کے ذریعہ طعن وتشنیع کرتے ہیں ، جو روافض کے زیادہ ہوتے ہیں اور انہی سے جڑے ہوتے ہیں ۔ لیکن یہاں پر ایسے جملہ کہنے ضروری ہیں جن سے حق بات کا پتہ چل سکے۔توحید اور اسماء وصفات کا معاملہ وہ معاملہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے ہٹ کر مفروضہ عقلی مسائل کی طرف جانے والے مبتلا ہوتے ہیں ۔ حالانکہ واضح معقولات انہی چیزیں کا حصہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جو شخص معقول اور منقول دونوں کو جانتا ہے، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے۔