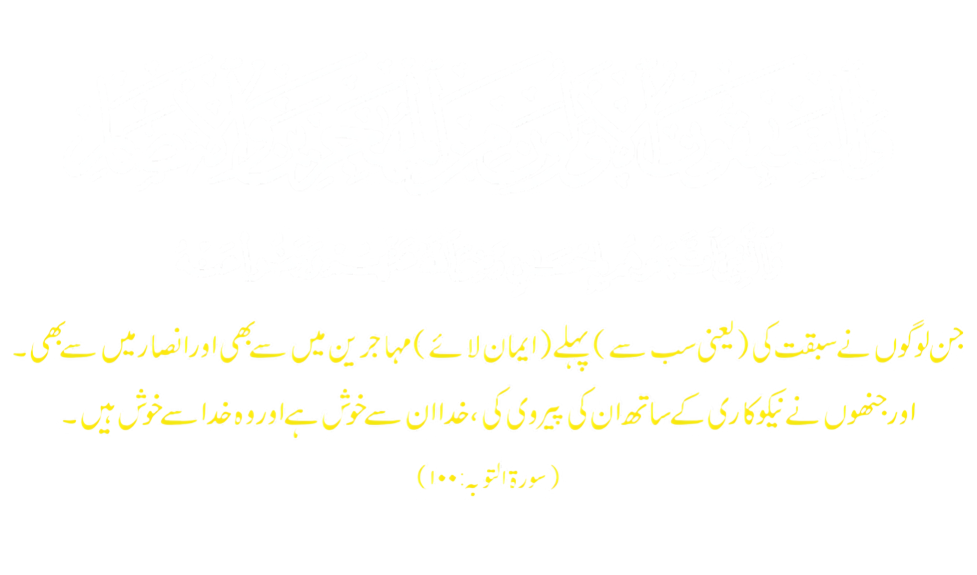فصل:اللہ تعالی کے بعض اسمائے مبارکہ کے متعلق اختلاف:
امام ابنِ تیمیہؒفصل:اللہ تعالیٰ کے بعض اسمائے مبارکہ کے متعلق اختلاف:لوگوں کا ان ناموں میں اختلاف ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور اس کے بندوں کے بھی رکھے جاتے ہیں :یہ معاملہ بہت سے لوگوں پر لفظی اور معنوی طور پر مشکل ثابت ہوا ہے۔ جہاں تک الفاظ کی بات ہے تو لوگوں کا ان ناموں پر تنازعہ ہے جو یکساں طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں پر بولے جاتے ہیں ، مثلا: موجود، زندہ، علیم اور قدیر۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے: یہ مقولہ لفظی اشتراک کی بنا پر ہے جو ان دونوں کے درمیان قدرِ مشترک کے اثبات سے خبردار کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ جب یہ دونوں وجود کے مسمی میں مشترک ہوتے ہیں تو لازم ہے کہ واجب کو ممکن سے کسی اور چیز سے جدا کیا جائے ۔ تو وہ مرکب ہوگا۔ یہ شہرستانی اور رازی جیسے بعض متاخرین کا قول ہے اور ان کے اس مسئلہ میں دو اقوال میں سے ایک قول ہے۔ اسی طرح آمدی کا بھی یہی قول ہے اگرچہ بعض اوقات وہ مسئلہ پر توقف کرتے ہیں ۔رازی، آمدی اور ان کے موافقین نے یہی قول اشعری اور ابو حسین بصری سے نقل کیا ہے جبکہ یہ ان دونوں پر تہمت ہے۔ ان لوگوں نے یہ بات اس لیے ذکر کی ہے کیونکہ یہ دونوں احوال کے قائل نہیں ہیں ، بلکہ یہ دونوں کہتے ہیں : کسی چیز کا وجود اس کی عین حقیقت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ جس نے یہ کہا کہ ہر چیز کا وجود اس کی عین حقیقت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لفظِ وجود ان دونوں پر اشتراکِ لفظی کی قبیل سے ہے۔ کیونکہ اگر وہ موافق ہوتا تو ان دونوں کے درمیان ایک قدرِ مشترک ہوتی تو ان میں سے ایک دوسرے سے اپنی حقیقت کی خصوصیت کی بنا پر ممتاز ہوتا۔ مشترک ممتاز کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا مشترک وجود ممتاز کرنے والی حقیقت نہیں ہے۔ رازی، آمدی اور ان جیسوں نے سمجھا کہ اس مسئلہ پر صرف یہی قول موجود ہے اور ان لوگوں کا قول موجود ہے جو کہتے ہیں کہ الفاظ موافق ہوتے ہیں ۔اور وہ کہتے ہیں : اس کا وجود اس کی حقیقت سے زائد ہوتا ہے جیسا کہ یہ قول ابو ہاشم اور اس کے معتزلی اور شیعی پیروکاروں کا ہے۔یا ابن سینا کا قول ہے کہ وہ موافق ہے یا مشکوک ہے اس کے باوجود کہ وہ ایسا وجود ہے جو اپنے بارے میں ہر قسم کے ثبوتی معاملات کے سلب ہونے سے مقید ہے۔بہت سارے باطنیہ اورقرامطہ اور غالی جہمیہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ اسماء بندوں میں حقیقت ہیں ؛ اور رب سبحانہ و تعالیٰ میں مجاز ہیں ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف اسم ’’ حیی‘‘اور اس طرح کے بعض دوسرے اسماء میں ہے۔ [1][1] مقالات الاشعری ۱؍ ۳۱۲ [حتی کہ اسم ’’شئی ‘‘ ؛ جہم بن صفوان اور اس کے پیروکاراسے ’’شئی ‘‘ کہہ کر نہیں پکارتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ: بیشک نام تو قادر اور فاعل نے رکھے ہیں ۔ او ران کے نزدیک بندہ کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز کا فاعل ہے۔پس اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نام نہیں رکھا جاسکتا جونام بندوں کا بھی ہے۔ جب کہ ابو العباس ناشی نے اس کے برعکس کہا ہے؛ وہ کہتا ہے : یہ نام رب سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں حقیقت ہیں ؛جب کہ بندے کے حق میں مجاز ہیں ۔ [2][2] الملل والنحل للشہرستانی ۱؍ ۷۹جبکہ ابن حزم رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ معانی پر دلالت نہیں کرتے۔ پس علیم کا معنی علم والا ہونا نہیں ؛اور نہ ہی قدیر سے مراد قدرت والا ہونا ہے۔ بلکہ یہ محض اعلام ہیں ۔یہ قول ان لوگوں کے اقوال کے مشابہ ہے جو اشتراک لفظی کا عقیدہ رکھتے ہیں ۔اس غلطی کی بنیاد جو چیزوں پر ہے:۱۔ صفات کا انکار اورتشبیہ کی نفی میں غلو۔ یا پھر :۲ ۔ خارج میں کلیات مشترکہ کے ثبوت کا گمان ۔پہلا قول جہمیہ اور ان کے موافقین منکرین صفات کا ہے؛ وہ کہتے ہیں : جب ہم کہتے ہیں : علیم؛ تو یہ علم پر دلالت کرتا ہے؛ اور قدیر قدرت پر دلالت کرتا۔ تو اسماء کے اثبات سے صفات کا اثبات لازم آتاہے۔ ابن حزم نے بھی اسی کو لیا ہے۔ بیشک وہ اس مسئلہ میں حدیث اور سنت اور پھر امام احمد کی انتہائی تعظیم کے باوجود منکرین صفات کے ساتھ ہیں ۔ اور ان کا دعوی یہ ہے کہ وہ اس مسئلہ میں جو کچھ کہتے ہیں وہ امام احمد رحمہ اللہ اور دیگر کا مذہب ہے۔‘‘ [الفصل ۲؍ ۲۹۶۔]اس مسئلہ میں ان کی غلطی کھانے کا سبب یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں فلاسفہ اور معتزلہ کے بعض مشائخ سے لی تھیں ۔اور جس پر ان لوگوں کی خطائیں واضح ہیں وہ کبھی ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرسکتا۔اور منطق کو ترجمان متّی سے نقل کیا ہے۔اوروہ یہ بھی کہتے ہیں کہ:’’جب ہم کہتے ہیں : موجود اورموجود ؛ حیی اور حیی؛ تو اس سے تشبیہ لازم آتی ہے۔ پس ان لوگوں کی غلطی اصل بنیاد یہی نکتہ ہے۔‘‘[الرد علی المنطقیین ۱۳۱] جبکہ دوسرا اصول ؛ اس میں رازی اور ان جیسے دوسرے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ جب یہ بھی موجود ہے؛ اور یہ بھی موجود ہے؛ تو وجود ان دونوں کو شامل ہے۔ تو خارج میں ان دونوں کے درمیان مشترک کلی ہوا۔ پس ان دونوں کے درمیان تمیز اورفرق کرنا ضروری ہے۔ ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ حقیقت ہے۔ پس یہ واجب ہے کہ ان کے مابین مشترک وجود اور ممیز حقیقت ہو۔ پھر ان کا بھی آپس میں تناقض ہے؛ وہ وجود کو بھی واجب اور ممکن میں تقسیم کرتے ہیں ۔ یا قدیم اور محدث میں ۔ جیسا کہ کلیہ عامہ میں تمام اسماء تقسیم ہوتے ہیں ؛ ایسا نہیں ہوتا جیسے مشترکہ الفاظ تقسیم ہوتے ہیں ؛ جیسے لفظ سہیل ۔ سہیل ایک ستارہ بھی ہے؛ اور سہیل بن عمرو ایک آدمی بھی ہے۔ بیشک یہ نہیں کہا جاسکتا کہ: یہ ان دونوں چیزوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہا جائے گاکہ : ’’ بیشک یہ لفظ اس معنی پر بھی بولا جاتا ہے؛ اور اس معنی پر بھی ۔ اوریہ لغت کا معاملہ ہے؛ کوئی عقلی تقسیم نہیں ہے۔یہاں پر ایک دوسری تقسیم عقلی بھی ہے۔ یعنی اس معنی کی تقسیم جو اس لفظ کا عمومی مدلول ہو۔مورد تقسیم مختلف اقسام کے مابین مشترک ہوتی ہے۔بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ: وہ اس کا خلاصہ یہ بتا سکتے ہیں کہ لفظ وجود کو اس لیے مشکوک بنایا جائے؛ اس لیے کہ وجود واجب زیادہ اکمل ہوتاہے۔جیسا کہ لفظ ’’سواد ‘‘ اور ’’بیاض ‘‘ میں ہوتا ہے ۔ سیاہ؛ پروں کوسیاہی کو بھی کہا جاتا ہے ؛[ اور پسی ہوئی چیز کو بھی ]اور آنکھوں کی پتلی کی سیاہی کو بھی۔ اور سفید ؛ برف کو بھی کہا جاتا ہے؛ اور ہاتھی کی سونڈھ کو بھی ۔اس میں کوئی شک نہیں بلا ریب معانی کلیہ اپنے موارد کے حساب سے متفاضل ہوتے ہیں ۔ بلکہ ان میں سے اکثر کا یہی عالم ہوتاہے۔اس قسم کو لفظ مشکک کے ساتھ مخصوص کرنا ایک اصطلاحی معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ: یہ نوع متواطی ہے۔ اس لیے کہ لغت کے وضع کرنے والے نے یہ لفظ اس فرق کے لیے وضع نہیں کیا جو ان دو میں سے کسی ایک میں پایا جاتا ہے۔ بلکہ اس نے اس لفظ کو ان کے درمیان مشترکہ قدر کے لیے وضع کیا ہے۔خلاصہ کلام ! یہ اختلاف لفظی ہے۔متواطہ عامہ تمام مشککہ کو شامل ہوتا ہے۔ جب کہ وہ متواطئہ جو معانی میں مساوی ہو؛ وہ مشکک کی ہی ایک قسم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ متواطئہ کی دو اقسام ہیں : عام اور خاص۔ جیسا کہ امکان کی بھی دو اقسام ہیں ؛ عام اور خاص۔ اس سے یہ التباس ختم ہوگیا۔یہاں پر مقصود یہ تعارف کروانا ہے کہ :اولین و آخرین میں سے جمہورطوائف کا قول ہے کہ یہ اسماء عامہ کلیہ ہوتے ہیں ۔ بھلے انہیں متواطئہ کہا جائے یا مشککہ کہا جائے۔ یہ ایسے مشترکہ الفاظ نہیں جن میں صرف لفظی اشتراک ہو۔یہ مذہب معتزلہ ؛شیعہ ؛ اشعریہ ؛ کرامیہ اور دیگر تمام مسلمانوں اہل سنت و الجماعت ؛محدثین اورباقی حضرات کا ہے؛ سوائے ان چند لوگوں کے جو ان سے علیحدہ ہوگئے ہیں ۔ان لوگوں نے جو شبہ پیش کیا ہے؛ اس کا جواب دو طرح سے ہے: تمثیل اور تخییل۔جہاں تک تمثیل کا تعلق ہے؛ تو یہ کہا جائے گا کہ: لفظ وجود میں وہی قول ہے جیسا کہ لفظ حقیقت ؛ اور ماہیت اور نفس اور ذات میں ؛ اور دیگر تمام ان الفاظ میں ہے جو واجب اور ممکن پر بولے جاتے ہیں ؛ بلکہ انہیں ہر موجود پر بولا جاتا ہے۔پس یہ لوگ جب کہتے ہیں : ’’وہ دونوں وجود میں شریک ہیں ؛ اور حقیقت میں ایک دوسرے سے جدا ہے۔تو ان سے کہا جائے گا کہ: لفظ حقیقت میں بھی وہی قول ہے جو کہ لفظ وجود میں ہے۔ بیشک اس چیز کی بھی اپنی حقیقت ہوتی ہے؛ اور اس دوسری چیز کی بھی حقیقت ہے۔ جیسا کہ ان دونوں کا اپنا اپنا وجود ہے۔ اور ان میں سے ایک دوسرے اپنے مخصوص وجود کی وجہ سے جدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان کی مخصوص حقیقت باہم جدا ہوتی ہے۔ پس کہنے والے کا یہ کہنا کہ : یہ دونوں لفظ مسمی الوجود میں مشترک ہیں ؛ اوران میں سے ہر ایک اپنی مخصوص حقیقت کی وجہ سے دوسرے سے جدا ہے۔ جیسا کہ اگر یہ کہا جائے کہ: یہ دونوں حقیقت کے مسمیٰ میں مشترک ہیں ؛ اور ان میں سے ہر ایک اپنے مخصوص وجود کی وجہ سے جدا بھی ہے۔اس غلطی کے واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مطلق وجود کو لیا ہے مخصوص کو نہیں ۔ اور ایسے حقیقت کو بھی مطلق لیا ہے مخصوص نہیں ۔ اور یہ بات جانتے ہیں کہ: ایسا ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا وجود مطلق بھی ہو اور ممکن ہے مخصوص وجود بھی ہو۔ جب ان دونوں کو مطلق طور پر لیا جائے تو وہ دونوں عموم میں برابر ہوتے ہیں ۔ اور انہیں خصوص کے حساب سے لیا جائے تو وہ دونوں خصوص میں برابر ہوتے ہیں ۔ ہاں اگر ان میں سے ایک کو عموم پر لیا جائے او ردوسرے کو خصوص پر ؛ تو پھر یہ اس کا عکس ہونے میں دوسرے سے زیادہ اولیٰ نہیں ہے۔جہاں تک اس شبہ کے حل کا تعلق ہے؛ تووہ بیشک یہ گمان کرتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ دونوں وجود کے مسمیٰ میں مشترک ہیں ؛ اور خارج میں ان کا مشترک وجود ہو؛ تو یہ اس دوسرے میں بھی بالکل ویسے ہی ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ اس پہلے کے بارے میں ہوسکتا ہے۔ پس وہ ان دونوں کے مابین مشترک ہوگا۔اور مشترک کی تمیز نہیں کی جاسکتی؛ اس کے لیے کسی ممیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ غلط ہے۔ بیشک کسی کہنے والے کا یہ قول کہ :’’وہ دونوں مسمیٰ الوجود میں مشترک ہیں ؛ یعنی اس میں متاشبہ ؛ اور متفق ہیں ؛ تو پس یہ بھی موجود ہے؛ اور یہ بھی موجود ہے؛ اور ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ نفس وجود میں کسی بھی صورت میں شریک نہیں ہوسکتا۔جب یہ کہا جائے کہ : یہ دونوں وجود مطلق کلی میں مشترک ہیں ؛ تو وہ مطلق کلی ؛ صرف ذہن میں مطلق کلی ہوسکتا ہے۔ خارج میں ایسا مطلق کلی نہیں ہے جو آپس میں مشترک ہوں ۔ بلکہ ان میں سے ایک دوسرے کا حصہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا پہلے کا حصہ ہوتا ہے۔ اور ہر دو حصے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں ۔جس کسی نے یہ کہا ہے کہ: مطلق معین کا ایک جزء ہوتاہے؛ اور موجود ؛ اس موجود کا جزء ہوتا ہے۔ اور انسان اس انسان کا جزء ہے۔اگر اس سے مراد یہ ہو کہ معین کا یہ وصف بیان کیا جاسکتاہے؛ اور یہ اس کی صفت ہو سکتی ہے؛ اوراِس کے اُس کی صفت ہونے کے باوجود ؛ جو چیز اس دوسرے کی صفت ہے ؛ اس کی نظیر اس کے دوسرے کے لیے نہیں پائی جاتی ۔ یہ اس کا صحیح معنی ہے۔ لیکن صفت کو موصوف کے جزء کا نام دینا؛ اس کا عند الاطلاق مفہوم نہیں ہے۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہو کہ: جو کچھ وجود یا انسان نفسِ معین میں ہوتا ہے؛وہ بعینہ اس دوسرے میں بھی ہوتا ہے تو یہ پھر بلا وجہ انکار ؛ اور مکابرہ ہے ۔اگر وہ کہے کہ: میری مراد دوسری قسم تھی؛ تو پھر کلام واپس ’’نوع ‘‘ پر چلا جائے گا۔ پس بیشک نوع بھی اسی طرح سے کلی ہوتی ہے۔کلیات کی پانچ اقسام ہیں : ۱۔ کلیات جنس۔ ۲۔ نوع ۔ ۳۔ فصل۔ ۴۔خاصہ ۔اورعرض عام ۔ اور ان سب میں ایک ہی قول ہے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو خارج میں کلی مطلق موجود ہو۔ اور کلی مطلق صرف اذہان میں ہی ہوسکتی ہے اعیان میں نہیں ۔جو ان میں عموم اور کلیہ ؛ یا پھر ایسی ترکیب کا دعوی کیا جاتا ہے جیسے جنس اور فصل سے نوع کی ترکیب ہوتی ہے؛ تو یہ عقلی اور ذہنی امور ہیں ؛ خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ خارج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان دونوں کو شامل ہو۔ اور نہ ہی خارج میں کوئی انسان ان دونوں چیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ بلکہ انسان ان دونوں سے اس طرح موصوف ہوسکتا ہے کہ ان دونوں کی نظیر ہر انسان میں موجود ہو؛ یا پھر اس طرح سے کہ اس کی نظیر ہر حیوان میں موجود ہو؛ اوراس طرح سے بھی کہ یہ نظیر ہر ذی روح میں موجود ہو۔رہ گئی وہ خاص وصف جو اس کے ساتھ قائم ہے؛ اور وہ موصوف؛ جس کے ساتھ یہ وصف قائم ہے؛ تو اصل میں ان کے مابین نہ ہی کوئی اشتراک ہے؛ اور نہ ہی عموم۔ اور نہ ہی وہ عام اور خاص سے مرکب ہے۔یہ وہ موضوع ہے جو کلیات میں کئی ایک اہل منطق کی گمراہی کا سبب بنا ہے۔ اور بہت سارے متکلمین حال کے مسئلہ میں گمراہی کا شکار ہوئے ہیں ۔ پس اسی وجہ سے وہ لوگ غلطی کا شکار ہوئے ہیں جنہوں نے الالٰہیات اور اس سے متعلقہ مسائل میں غلطی کھائی ہے۔ اس لیے کہ بغیر کسی شک و شبہ کے متکلمین کی رائے بھی یہ تھی کہ اشیاء کچھ اوصاف میں ایک [متفق ] ہوتی ہیں ؛ اور کچھ اوصاف میں مختلف۔‘‘ اور مشترک عین ِ ممیز ہوتا ہے۔ پس اس وجہ سے وہ دو گروہ ہو گئے؛ ایک گروہ ان امور کو خارج میں ثابت مانتاہے۔ مگروہ کہتے ہیں : نہ ہی موجود ہیں او رنہ ہی معدوم۔اس لیے کہ اگر وہ موجود ہوتے تو اعیان ہوتے۔ یا پھر اعیان کی صفات ہوتے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو ان کے مابین عموم اور اشتراک نہ ہوتا۔ اس لیے کہ موصوف میں موجود صفت میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہوسکتا۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں : ہر موجود کی خاص صفات ہوتی ہیں ۔ وہ کہتے ہیں :اشتراک اور عموم صرف الفاظ میں ہوتا ہے؛ معانی میں نہیں ۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ مشترک امور عامہ اذہان میں ثابت ہوتے ہیں ؛ اور یہ الفاظ کے عام معانی ہیں ۔ پس ان کا عموم الفاظ کے عموم کی منزلت پر ہوتا ہے۔ پس خط لفظ کے مطابق ہوتاہے؛ اور لفظ معانی کے مطابق ہوتا ہے ؛اور عموم لفظ عموم معانی کے مطابق ہوتا ہے؛ اور عموم خط عموم لفظ کے مطابق ہوتا ہے۔اور یقیناً اس میں بھی لوگوں کا اتفاق ہے کہ عموم الفاظ کے عوارض میں ہوتا ہے۔ اور ان کا اختلاف ہے کہ کیا عوارض معانی میں بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ؟ جب کہ دوسرے لوگوں کا مبلغ علم یہ ہے کہ ہر موجود کی ایک خاص صفت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں : عموم اور اشتراک صرف الفاظ میں ہوتا ہے؛ معانی میں نہیں ۔تحقیق یہ ہے کہ بیشک یہ امور عامہ جو آپس میں مشترک ہوتے ہیں ؛ یہ اذہان میں ثابت ہوتے ہیں ۔ اوریہی عام الفاظ کے معانی بھی ہوتے ہیں ۔ پس ان کا عموم عموم الفاظ کی منزلت پر ہوتا ہے۔ پس خط لفظ کے مطابق ہوتا ہے؛ اور لفظ معنی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور معنی عام ہوتا ہے۔ اور عموم لفظ عموم معنی کے مطابق ہوتا ہے اور عموم خط عموم لفظ کے مطابق ہوتا ہے۔یقیناً لوگوں کا اتفاق ہے کہ بیشک عموم الفاظ کے عوارض میں سے ہوتا ہے۔ اور ان کا اختلاف ہے کہ کیا یہ معانی کے عوارض میں سے بھی ہوسکتا ہے؟ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ: عوارض معانی میں سے بھی ہوسکتا ہے؛ جیسے ان کا یہ کہنا : مطر عام ؛ عدل عام ؛ خصب عام ۔یہ بھی کہا گیا ہے کہ : بلکہ ایسا مجازاً ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو بارش اس گوشے پر ہوتی ہے ؛ وہ وہی بارش نہیں ہوتی جو اس دوسرے گوشے پر ہوتی ہے۔ اور یہی حال خصب اور عدل کا بھی ہے۔اس کی تحقیق یہ ہے کہ : متکلم کے دل کے ساتھ قائم مطر[بارش] کا معنی ایسے عام ہوتا ہے جیسے عموم لفظ برابر ہوتا ہے؛ بلکہ لفظ اس معنی پر دلیل ہوتاہے۔تو پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ معنی کو چھوڑ کر لفظ عام ہو؛ جبکہ مقصود تو معانی کا بیان ہوتاہے۔ اور جہاں تک خارجی معانی کا تعلق ہے؛تو اس میں کوئی بھی چیز بعینہ عام نہیں ہے۔ بیشک اس میں نوعیت کے لیے عموم پایا جاتا ہے؛ جیسے حیوان کے لیے حیوانیت ؛ اور انسان کے لیے انسانیت ۔ پس کلیات ؛ احوال اور عروض؛ ایک ہی جنس سے عموم لغیر الفاظ کا مسئلہ ؛ اور جو کوئی اس مسئلہ کو ویسے ہی اس کی حقیقت کے مطابق سمجھ لیتا ہے؛ تو اس پر یہ واضح ہوجاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز خارج میں بعینہ موجود نہیں ہے۔جب یہ کہا جائے کہ : اس کی نوع موجود ہے؛یا کلی طبیعی موجود ہے؛ یا حقیقت موجود ہے؛یا انسانیت اپنی حیثیت کے اعتبار سے موجود ہے؛ یا اس طرح کی دیگر عبارتیں ؛ تو بیشک ان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی اس دوسرے کی نظیر اور مشابہت یا مماثلت وغیرہ وپائی جاتی ہے۔دو متماثلان کو ایک نوع یکجا کرتی ہے۔اور یہ نوع بعینہ ان دونوں کو شامل ہوتی ہے۔اور عام مطلق کلی صرف ذہن میں ہی ہوسکتا ہے۔اور جب آپ کہتے ہیں : انسانیت خارج میں بھی وجود رکھتی ہے؛ اور کلی طبیعی بھی خارج میں وجود رکھتی ہے؛ تو یہ بات صحیح ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ذہن جس کلی کا تصور کرتا ہے؛ وہ خارج میں موجود ہے۔ لیکن جب خارج میں ہی کلی نہ ہو ؛ جیسے آپ جب کہتے ہیں کہ : زید فی الخارج ؛ تو اس سے نہ ہی یہ لفظ مراد ہوتے ہیں ؛ اور نہ ہی وہ معانی جو ذہن میں قائم ہیں ؛ بلکہ اس لفظ سے مراد خارج میں موجود ہونا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے لوگوں کے درمیان اسم اور مسمیٰ پر اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ان کا اختلاف بھی اس اختلاف سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور جب آپ پانی میں یا شیشہ میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں : یہ سورج یا چاند صحیح ہیں ۔ اس سے آپ کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ جو کچھ آسمان میں ہے بالکل وہی آپ نے پانی یا شیشہ میں اتر آیا۔بلکہ شیشہ میں وہ ظاہر ہوا؛ اس کا عکس دیکھا گیا؛ یا تجلی کا مشاہدہ ہوا۔جب آپ کہتے ہیں : کلیات خارج میں ہیں ؛ تو یہ صحیح ہے۔ یا انسان اپنی اصل میں خارج میں موجود ہے ؛ تویہ بھی صحیح ہے۔لیکن ایسا نہیں ہوسکتا کہ خارج میں ایسا مخصوص مقید ہو ؛ جس کے ساتھ اس حقیقت میں دوسری خارجی موجودات میں سے کوئی بھی چیزشریک نہ ہوتی ہو۔ پس اس سے بہت سارے وہ شبہات ختم ہو جاتے ہیں جن میں اہل منطق شبہات کا شکار ہوکر غلطی کھا گئے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ: خارج میں موجود ماہیت وجود کے علاوہ ہوتی ہے۔ بیشک اس صورت میں آپ اس مثلث کا تصور اس کے وجود کے علم سے پہلے ہی کر بیٹھتے ہیں ۔ پس اس پر انہوں نے صفات ذاتیہ اور عرضی لازمہ کے مابین فرق اور اس طرح کے دوسرے مسائل کی بنیاد رکھی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چیز ذہن میں ہے؛ اور چیز خارج میں ہے؛ ان دونوں کے درمیان فرق ثابت ہے۔اور جب ماہیت کو ذہن میں موجود چیز کا نام قراردیا جائے۔اور وجود کو خارج میں موجود چیز کا نام قرار دیا جائے؛ تو فرق ثابت ہو جاتاہے۔جیسے اگر وجود ذہن میں موجود کا نام اور ماہیت کو خارج کانام دیا جائے۔لیکن جب لفظ ’’ ماہیت ‘‘ سائل کے قول ’’ماھو‘‘ سے ماخوذ ہے۔اور جو جواب اس مقول ’’ماھو‘‘ کے جواب میں ہے؛ وہ کلام ہے جس کے معنی کا تصور جواب دینے والا کرسکتا ہے۔ ماہیت کو تصور ذہنی سے تعبیر کیا گیا ہے؛ جبکہ وجود خارج میں کسی چیز کی حقیقت کو کہتے ہیں ۔
لیکن ان لوگوں نے صرف اسی پر اکتفاء نہیں کیا؛ بلکہ ان کا خیال یہ بھی ہے کہ اشیاء کی ماہیت خارج میں ثابت ہے؛ اوریہ اعیان موجودہ کے علاوہ ہوتی ہیں ۔ اس بات کا غلط ہونا ضرورت کے تحت معلوم شدہ ہے۔پس بیشک جس مثلث کو خارج میں اس کے وجود سے پہلے آپ جانتے ہیں ؛ وہ مثلث صرف آپ کے ذہن کا ایک تصور ہے؛ خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ورنہ یہ بات ممتنع ہے کہ آپ خارج میں موجود مثلث کی حقیقت کو خارج میں اس کے وجود سے پہلے جان جائیں ۔ پس جو کچھ خارج میں ہے اس کی حقیقت کا علم اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک اس کے وجود کا علم نہ ہو۔ اور جس چیز کی حقیقت کا علم اس کے وجود سے پہلے ہوجائے؛ تو بعد میں اس کی حقیقت صرف ذہن میں ہی ہوسکتی ہے۔پس اسی باب سے گمان کرنے والوں نے گمان کیا ہے کہ : ہمارے لیے خارج میں مجرد عدد؛ یا مجرد مقدار موجود ہے۔یہ تمام باتیں غلط ہیں ۔یہ مسئلہ دوسری جگہ پر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کردیاگیا ہے۔یہاں پر صرف اس پر تنبیہ کرنا تھی۔اس لیے کہ بہت سارے اکابرین اہل مناظرہ ؛ صوفیہ :اور فلاسفہ اورمتکلمین اور ان کے اتباع کار فقہاء صوفیاء؛وجود خالق کے مسئلہ میں گمراہی کا شکار ہوئے ہیں ؛ جو کہ تمام مسائل کا سردار مسئلہ ہے اور جس کسی نے اس شبہ کی وجہ سے ان کے کلام کامطالعہ کیا ؛ اس پر یہ معاملہ ملتبس ہوگیا۔اور ہم نے خصوصی طور پر اس سلسلہ میں ’’مسئلہ کلیات ‘‘ میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ کیونکہ اس کی ضرورت عام تھا؛ اور مسئلہ بہت ہی فائدہ بخش تھا جس سے شبہات کا ازالہ ہوسکتا تھا۔اس سے منکرین صفات کی لفظ تشبیہ میں غلطی واضح ہوتی ہے۔ پس بیشک یہ کہا جاسکتا ہے کہ : جس چیز کی رب تعالیٰ سے نفی کی جاسکتی ہے؛ وہ اس کا مخلوق کی صفات سے متصف ہونا ہے۔ یا پھر بندہ کے لیے کوئی ایسی چیز ثابت کی جائے جس میں اسے رب کے مماثل قرار دیا جائے۔ہاں مگر جب یہ کہا جائے:حی ؛ اور حی؛ عالم اور عالم ؛ اورقادر اور قادر؛ یا یوں کہا جائے کہ : اس کی بھی ایک قدرت ہے؛ اوراس کی بھی ایک قدرت ہے؛ اس کا بھی علم ہے؛اور اس کا بھی علم ہے؛ تو پھر نفس علم ِ رب سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی بندہ اس کا شریک نہیں ہوسکتا۔ اور بندہ کے علم کے ساتھ رب سبحانہ و تعالیٰ کو موصوف نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلندو بالا ہیں ؛ اور یہی حال باقی صفات میں بھی ہے۔ ان کی آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔جب علماء کرام مسمیٰ علم میں متفق ہوتے ہیں ؛اور دو عالم مسمیٰ عالم میں متفق ہوتے ہیں ؛ تو ایسی تشبیہ کی نہ ہی عقلاً نفی کی جاسکتی ہے اور نہ ہی شرعاً۔ اور نہ ہی وجود صانع کی نفی کے بغیر اس کی نفی ممکن ہے۔پھر موجود اور معدوم اتنی سی بات میں مشترکہ قدر رکھتے ہیں کہ ہر دو معلوم اور مذکور ہیں ۔ لیکن ان میں سے کسی ایک کے اثبات میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ ممانعت تو اس وقت ہوتی ہے جب ایک کے خصائص کو دوسرے میں ثابت کیا جائے۔ جب ہم کہتے ہیں :’’خصائص کا اثبات ‘‘ تو اس سے مراد وہ اثبات ہے جو اسی چیز کے ساتھ خاص ہے۔ وگرنہ اس کی عین کا اثبات مطلقاً ممتنع ہے۔اسماء اور صفات دو اقسام پر ہیں ۔ایک قسم جورب سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ۔ مثلاً الوہیت؛ اور رب العالمین ہونا؛ اور اس طرح کی دیگر صفات ۔ پس ایسی چیزیں کسی بھی صورت میں کسی بندے کے لیے ثابت نہیں کی جاسکتیں ۔ پس یہاں سے مشرکین کی گمراہی کا آغاز ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ۔دوسری قسم :.... جس سے اجمالی طور پر بندے کو موصوف کیا جاسکتا ہے ۔جیسے حی؛ قادر اور عالم ۔تو ان میں بھی بندے کے لیے اس طرح کا اثبات کلیۃً جائز نہیں ہے جیسا اثبات رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے۔ بلا شک و شبہ ؛اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ویسی صفات کا اثبات کیا جائے؛ جیسے بندے کے لیے ہے؛ تو اس سے لازم آتا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے پر تجاوز کرے۔ اوراس پر بھی وہی واجب ہوتا ہے؛ جو دوسرے پر واجب ہے۔اور اس کے لیے بھی وہی ممتنع ہے جو دوسرے کے لیے ممتنع ہے۔ اس سے اجتماع نقیضین لازم آتا ہے؛ جیسا کہ اس سے پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔جب یہ کہا جائے کہ: یہ ان امور میں لازم آتا ہے جس میں یہ دونوں متفق ہوں ؛ جیسے وجود ؛ علم اور حیات ۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گاکہ: ان امور کے تین اعتبارات ہیں :اول:.... جو رب سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں واجب ہے؛ اور بندے کے لیے ممتنع ہے؛ بندے کا اس میں کوئی نصیب نہیں ہے۔دوسری قسم :.... جو صرف بندے کے ساتھ خاص ہیں ۔ جیسے بندے کا علم ؛ اس کی قدرت اور حیات۔ پس جب بندے پر حدوث اورعدم جائز ہے؛ اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت اور حیات سے متعلق نہیں ہوتے؛ توبیشک ان میں کوئی اشتراک نہیں ہے۔تیسری قسم :.... مطلق کلی: یعنی مطلق حیات؛ علم اورقدرت۔ پس یہ مطلق ؛ جو کچھ اس میں واجب ہے؛ تو وہ ان دونوں کے لیے واجب ہے؛ اور جو کچھ ایک پر جائز ہے؛ وہ در حقیقت دونوں کے لیے جائز ہے۔ اورجو اللہ تعالیٰ پر ممتنع ہے؛ وہ ان دونوں پر ممتنع ہے۔پس واجب ہوتا ہے کہ یوں کہا جائے: یہ جہاں بھی ہو؛ صفت کمال ہوتی ہے۔پس زندگی؛ علم ؛ اور قدرت ہر موصوف کے حکم میں صفت کمال ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے کسی بھی دوسری صفت کے ساتھ اقتران؍ جوڑ جائز ہے؛ جیسے سمع؛ بصر؛ اور کلام۔پس ان صفات کو کسی بھی دوسری ایسی صفات سے ہر جگہ پر ملانا جائزہے۔ ہاں اگر وہاں پر کوئی اور محلی مانع ہو؛ صفت کے اعتبار سے نہیں ۔ اور جہاں تک ان دونوں پر امتناع کا تعلق ہے ؛ تو ایسے موصوف کے بغیر ان صفات کا قائم رہنا ممتنع ہے جو بذات خود قائم ہو۔ایسا ہر جگہ پر ممنوع ہے۔ پس یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات موصوف کے بغیر بذات خود قائم ہوں ۔ اور ایسی ہی بندوں کی صفات بھی بذات خود قائم نہیں رہ سکتیں ۔