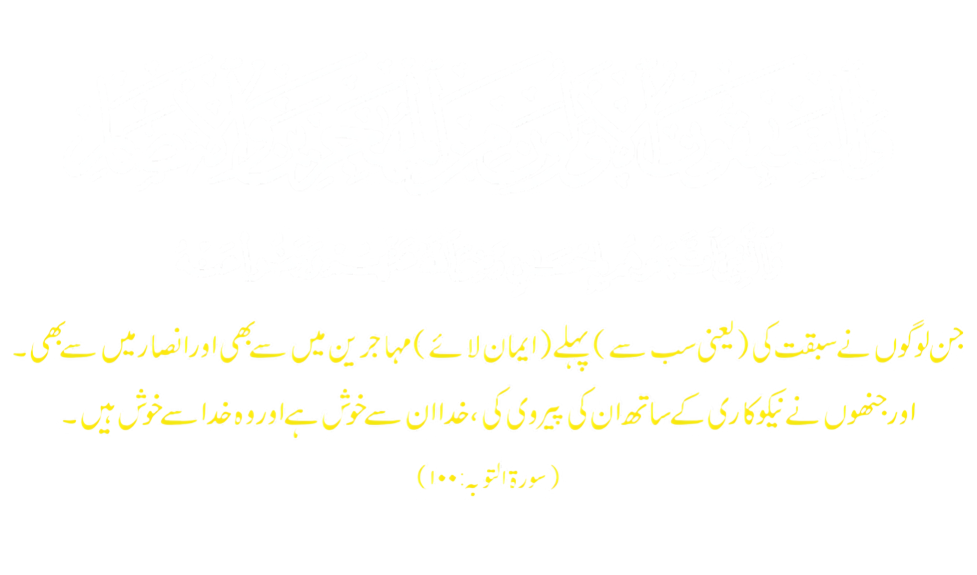سنی و شیعہ کے مجموعات حدیث میں تعداد روایات (قسط 6)
مولانا سمیع اللہ سعدیسنی و شیعہ کے مجموعات حدیث میں تعداد روایات
اہل تشیع اور اہل سنت کے حدیثی ذخیرے کا ایک بڑافرق فریقین کے مجموعات حدیث میں مدون روایات کی تعداد کا مسئلہ ہے ، اس فرق سے متنوع سوالات جنم لیتے ہیں ،اولا فریقین کے مصادر حدیث میں موجود روایات کا ذکر کیا جاتا ہے ، ثانیا اس فرق سے پیدا شدہ بعض اہم نتائج کو سوالات کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے :
اہل سنت کے اساسی مصادر کی مرویات
اہل سنت کے بنیادی مصادر حدیث صحاح ستہ اور مسند احمد و موطا ہیں ، ان آٹھ کتب کی مجموعی مرویات مکررات سمیت یوں ہیں :

مجموعه روایات :
ان آٹھ کتب کی روایات انہی میں سے دوسری کتب میں بھی مذکور ہیں ،اگر ہم آٹھ کتب کی انفرادی زوائد مرویات کو الگ کر کے دیکھیں ، تو تعداد اس سے بھی کہیں کم بنتی ہے ، ذیل میں ان کی انفرادی زوائد روایات کا ذکر کیا جاتا ہے :
بخاری کے زوائد : 430
بخاری پر مسلم کے زوائد : 578
صحیحین پر ابو داود کے زوائد : 1337
صحیحین و ابو داود پر تر مذی کے زوائد : 561
صحیحین ابو داود و ترمذی پر نسائی کے زوائد : 163
کتب خمسہ پر ابن ماجہ کے زوائد :184
صحاح ستہ پر موطا کے زوائد : 138
صحاح سته و موطا پر مسند احمد کے زوائد : 548
مجموعه روایات : 3939
نسخ و طبعات کے فروق کو شامل کرتے ہوۓ ہم اس تعداد کو 4000 شمار کر سکتے ہیں ، یوں اہل سنت کی آٹھ کتب میں موجود بلا تکرار و مشترکات کے کل روایات تقریبا 4000 ہیں ، یہی چار ہزار روایات اسانید و تکرار کے ساٹھ باسٹھ ہزار مرویات میں ڈھل جاتی ہیں ، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اہلسنت کی ایک ایک حدیث کتنی کثیر طرق کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ صرف چار ہزار روایات کے طرق و رواۃ اتنے زیادہ ہیں ، جس سے چار ہزار روایات باسٹھ ہزار روایات میں تبدیل ہو گئی ہیں ۔
(احصائية حدبیہ تبين العلاقة بين الكتب التسعة و حجم التوافق في الاحاديث ، عبد الله بن مبارک ، المجلس الالوکہ /0/79936/http://www.alukah.net/sharia)
اہل تشیع کے اساسی مصادر کی مرویات
اہل تشیع کے اساسی مصادر بھی آٹھ ہیں ، جن میں چار کتب متقدمین اور چار کتب متاثرین کی ہیں ، معروف شیعہ عالم محمد صالح الحائری لکھتے ہیں :
و اما صحاح الاماميه فهي ثمانية ،اربعة منها للمحمدين الثلاثة الاوائل ،و ثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الاواخر ،و ثامنها لمحمد حسين المعاصر النوري۔
(الوحدة الاسلامیہ بحوالہ علم الحدیث بین اصالۃ اہل السنه وانتحال الشیعہ ، ص 107)
ان آٹھ کتب میں متقدمین کی چار کتب یہ ہیں :
1۔الکافی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلمینی
2۔ من لا یحضرہ الفقیہ ، ابن بابویہ المی
3۔ تہذیب الاحکام ،ابو جعفر الطوسی
4۔الاستبصار فیما اختلف فيه من الاخبار ، ابو جعفر الطوسی
جبکہ متاخرین کی مرتب کردہ چار کتب یہ ہیں :
1۔ بحار الانوار ، محمد باقر مجلسی
2۔ وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ ، محمد بن حسن حر عاملی
3۔الوافی ، محسن کاشانی
4۔ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، محمد حسین نوری الطبرسی
ان کتب کی روایات مکررات سمیت کچھ یوں ہیں :
کتب اربعہ مقدمہ:
۔الکافی : 16000
من لا یحضره الفقیہ : 5963
تہذیب الاحکام :13590
الاستبصار : 5511
مجموعہ روایات : 41064
کتب اربعہ متاخرہ:
1۔ بحار الانوار ( شبکہ اہل المدینہ ) : 72000
2۔ وسائل الشیعہ (موسسہ اہل البیت لاحياء التراث ) : 35844
3۔الوافی (مکتبہ امیر المومنین ، اصفہان ) 25703
4۔ مستدرک الوسائل ( موسسہ اہل البیت ، بیروت )23129
مجموعه روایات : 156676
یوں آٹھ کتب کی مجموعی روایات مع مکررات : 41064+156676=197740
اب ان میں کتب اربعہ متقدمہ کی کل روایات کو مکررات و مشترکات کے حذف کے ساتھ محسن کاشانی نے الوافی میں جمع کیا ، جس کی روایات 25703 ہیں ، اس طرح سے کتب اربعہ سے مکررات و مشترکات کو نکال کر کل روایات 25703 بنتی ہیں ، اب بحارالانوار اور وسائل الشیعہ میں کتب اربعہ کی جملہ روایات کو اگر فرض کیا جائے، تو اہل تشیع کی احادیث بلا تکرار و مشترکات کچھ یوں بنتی ہیں :
کتب اربعہ کی مجموعی روایات بلا تکرار و مشترکات : 25703
بحار الانوار کی روایات ( کتب اربعہ کی روایات نکال کر ) :72000-25703= 46297
وسائل الشیعہ کی روایات (کتب اربعہ کی روایات نکال کر ) : 35844-25703=10141
مستدرک الوسائل کی روایات : 23129
مجموعی روایات بلا تکرار و مشترکات : 105270
( یاد رہے ، مستدرک الوسائل سے کتب اربعہ کی روایات منفی نہ ہونگی ، کیونکہ یہ کتاب متقدمین کے جملہ ذخیرے سے الگ جو روایات بچی ہیں ، ان پر مشتمل ہے )
اس ساری تفصیل کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے :
♦️ اہل سنت کی آٹھ بنیادی کتب کی مجموعی روایات مع مکررات و مشترکات : 62129( باسٹھ ہزار ایک سو انتیس )
♦️ اہل تشیع کی آٹھ بنیادی کتب کی مجموعی روایات مع مکررات و مشترکات : 197740 (ایک لاکھ ستانوے ہزار سات سو چالیس )
♦️ اہل سنت کی آٹھ مصادر کی بنیادی کتب کی مجموعی روایات بلا تکرار و مشترکات : 4000 ( چار ہزار )
♦️ اہل تشیع کی آٹھ بنیادی کتب کی مجموعی روایات بلا تکرار و مشترکات : 105270(ایک لاکھ پانچ ہزار دوسوستر)
تعداد مرویات کا عظیم فرق اور اس کے نتائج
اہل سنت واہل تشیع کی بنیادی کتب میں موجود روایات کی تعداد میں اس عظیم الشان فرق سے متعدد سوالات جنم لیتے ہیں :
1۔اہل سنت کا ذخیرہ مرویات تکرار کی بھٹی سے گزرا ہے ، چار ہزار روایات تعدد طرق و اسناد سے باسٹھ ہزار مرویات کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے ، اس طرح سے ہر روایت اوسطا پندرہ بار سے زائد مختلف کتب میں مکرر آئی ہے ، جبکہ اہل تشیع کے حدیثی ذخیرے میں تکرار تقریبا ناپید ہے ، کیونکہ ایک لاکھ ستانوے ہزار روایات میں سے مکر رات نکال کر بقیہ ایک لاکھ پانچ ہزار بچتی ہیں ، یوں تکرار کا تناسب دو کو بھی نہیں پہنچتا ، اہل علم جانتے ہیں کہ تکرار و شواہد روایت کی قوت و استنادی حیثیت میں بنیادی عامل ہے ، خاص طور پر جب ایک روایت مختلف خطوں کے افراد و مصنفین ذکر کرتے ہیں ، تو اس سے وضع و کذب کا عنصر تقریبا ختم ہو جاتا ہے ، یہی صور تحال اہل سنت کے حدیثی ذخیرے میں ہے ، جبکہ اہل تشیع کا حدیثی ذخیرہ جب تکرار و شواہد سے خالی ہے ، تو یقینا اس میں کذب و وضع کا احتمال قوی تر ہو جاتا ہے ۔
2۔اہل سنت کی چار ہزار روایات قبل از تدوین تحریر و تقریر کی صورت میں محفوظ رہا، تحریری ثبوت ڈاکٹر مصطفی اعظمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دراسات في الحديث النبوی و تاریخ تدوینہ میں دی ہے ، جن میں صرف ایک صدی کے اندر ساڑھے چار سو مجموعات حدیث مرتب ہوئے ، جبکہ تقریری ثبوت الرحله في طلب الحدیث اور اسفار محد ثین کی کتب میں مذکور ہے کہ حجاز ، یمن ، بغداد ، بصرہ ، کوفہ اور شام کی علمی درسگاہوں میں یہ احادیث تعلیم و تعلم کی بھٹی سے گزریں ہیں ، جب صرف چار ہزار مرویات کی حفاظت کے لئے بڑے پیمانے پر جتن کئے گئے، تو یقینا ایک لاکھ سے زائد روایات کو محفوظ کرنے کے لئے اس سے بڑی کاوشیں و کوششیں درکار ہوں گی ،لیکن باعث صد تعجب ہے کہ اہل تشیع کی ایک لاکھ مرویات کی حفاظت کے لئے قبل از تدوین تحریری و تقریری کوششیں تقریبا عنقا ہیں ، تحریری ثبوت کے لئے الاصول الاربعمائتہ کی اصطلاح مشہور کی گئی ، جس کے تاریخی استناد پر ہم بحث کر چکے ہیں ، کہ دو سو اٹھتر اصول کے مصنفین ہی نامعلوم ہیں ، چہ جائیکہ دیگر تفاصیل موجود ہوں ، جبکہ تقریری طور پر خود اہل تشیع محققین اور ائمہ کرام کی شہادتیں ہم پیش کر چکے ہیں کہ تقیہ کی وجہ سے ائمہ معصومین نے اہل تشیع کی مرویات کے لئے کھلم کھلا دروس اور تعلیمی مجالس کا انعقاد نہیں کیا ، یہاں بجا طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک لاکھ مرویات کی حفاظت کے لئے جس بڑے پیمانے پر تحریری و تقریری کوششوں کی ضرورت تھی ، وہ ناپید کیوں ہیں ؟اور کوششوں کی عدم موجودگی سے ایک لاکھ روایات کا یہ ذخیرہ استناد و ثبوت کی کس درجہ بندی میں آتا ہے ؟ غیر جانبدار محققین پر یہ بات مخفی نہیں ۔
3۔اہل تشیع کے مصادر حدیث میں اکثر روایات امام جعفر صادق اور ان کے والد امام باقر کی ہیں ، معروف شیعہ محقق ڈاکٹر محمد حسین الصغیر اپنی کتاب "الامام جعفر الصادق زعیم مدرسۃ اہل البیت " میں لکھتے ہیں :
كتب الاحاديث الابعمة و مستدركاتها و ما جرى مجرابا تعد المصدر الرئيس لحادیث اہل البیت عامة و احادیث الامام الصادق و ابيه الامام باقر خاصة۔
(الامام جعفر الصادق زعیم مدرسۃ اہل البیت، ص 386)
یعنی کتب اربعہ اور اس کے مستدرکات اور دیگر کتب حدیث عمومی طور پر اہل بیت کی احادیث کا مصدر ہیں، لیکن اہل بیت میں سے خاص طور پر امام جعفر صادق اور ان کے والد امام باقر کی روایات کا ماخذ ہیں۔
اگر ایک لاکھ روایات کا نصف حصہ بھی دونوں ائمہ کرام کا مان لیں (اگرچہ فی الواقع یہ تعداد دو تہائی تک پہنچتی ہے تو پچاس ہزار روایات ہر دو حضرات کی بنیں گی ، یوں ہر ایک امام کی پچیس ہزار مرویات بنتی ہیں ، تو سوال یہ بنتا ہے کہ پچیس ہزار مرویات لینے کے لئے کتنے تلامذہ چاہیئے ، آپ علیہ السلام کی چار ہزار احادیث کو روایت کرنے والے رواۃ صحابہ کی تعداد ایک ہزار یا پندرہ سو تک پہنچتی ہے ، تو پچیس ہزار روایات کو لینے کے لئے کم از کم چھ ہزار تلامذہ کی ضرورت ہوگی ، لیکن امام باقر کے تلامذہ استقصا کے بعد 482 تک پہنچتے ہیں ، یہ تعداد معروف شیعہ عالم باقر قریشی نے اپنی ضخیم کتاب "حياة الامام الباقر " کی دوسری جلد (ص 189تا383) میں ذکر کی ہے ، جبکہ امام جعفر صادق کے تلامذہ کی تعداد بقول ڈاکٹر محمد حسین الصغیر ساڑھے تین ہزار تک پہنچتی ہے۔
(الامام جعفر الصادق زعیم مدرسۃ اہل البیت، ص 303)
یہاں بجاطور پر سوال بنتا ہے کہ چار سو بیاسی حضرات نے پچیس ہزار روایات کیسے محفوظ کیں ؟ جبکہ صرف چار ہزار مرویات کو ایک ہزار حضرات جان توڑ کوششوں کے بعد ہی محفوظ کر سکے؟ اس پر مستزاد یہ کہ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی ابلاغ و تبلیغ پر مبنی تھی، ہر لحظہ اور ہر گھڑی آپ اللہ کا پیغام صحابہ کرام تک پہنچاتے رہے ، تئیس سالہ دور نبوت کی بھرپور تبلیغی زندگی کے بعد بھی آپ کے ارشادات چار ہزار بنتے ہیں ، تو امامین کریمین نے کیسے پچاس ہزار ارشادات اپنی زندگی میں صادر کئے؟ اگر تنیس سال کی انتھک محنت و ابلاغ کے بعد بھی اقوال چار ہزار بنتے ہیں ، تو پچیس ہزار اقوال کے لئے کم از کم ایک سو اڑتیس (138) سال ( تئیس کو چھ گنا کر کے ) در کار ہیں ، جبکہ امام باقر کی عمر 57 سال اور امام جعفر صادق کی عمر شریف 65 یا 68 سال تھی؟ ان میں بھی بلوغ اور حصول تعلیم کا کم ترین عرصہ بیس سال نکال کے امام باقر کی زندگی 37 اور امام جعفر صادق کی 48 سال بچتی ہے ۔ کیا ایک سو اڑتیس سال میں بولے جاسکتے والے کلمات محض 37 یا 48 سال میں کہنا عقلا ممکن ہے؟
4۔ اہل سنت کے ہاں چونکہ ذخیرہ روایات کم ہیں ، اس لئے بنیادی کتب میں موجود روایات میں مکررات ، شواہد ، مشترکات اور ایک روایت کے مختلف طرق واسانید پر بے تحاشا کام ہوا ہے ، مثلا بخاری شریف کی روایات میں کتنی روایات مکرر ہیں ؟ بخاری شریف میں کتنی ایسی روایات ہیں ، جو بقیہ ساتوں کتب میں نہیں ہیں؟ بخاری شریف کی روایت اگر دیگر کتب میں آئی ہے ، تو سند میں کتنے رواۃ کا اضافہ ہے؟ متن میں کس قسم کی تبدیلیاں ہیں؟ اس روایت کے ہم معنی روایت اور کن کن کتب میں کس کس صحابی سے مروی ہے؟ الغرض ہر کتاب پر اس طرح کا تفصیلی کام موجود ہے ، جبکہ اہل تشیع کے ہاں اس قسم کا مواد معدوم ہے ، کیونکہ دولاکھ کے قریب روایات کے انبار میں اس طرح کی چھان بین بے حد مشکل کام ہے ، اہل تشیع کی سب سے صحیح و مقبول ترین کتاب الکافی پر بھی اس طرح کا کام نہیں ہوا ، چہ جائیکہ بقیہ کتب پر ہوا ہو ،البتہ الکافی کی تازہ طبعات میں اس کی روایات کی دیگر کتب سے تخریج کی گئی ہے ، یہی وجہ ہے کہ کتب اربعہ میں مکرر و مشترک روایات کتنی ہیں ، اس پر کافی تلاش و جستجو کے بعد بھی کسی شیعہ محقق کی تحقیق نظر سے نہیں گزری ، معروف شیعہ محقق شیخ عبد الرسول عبد الحسن الغفار نے کافی کے تعارف پر ایک ضخیم کتاب " الکلینی و اکافی " لکھی ہے ، اس میں کافی کی روایات کی تعداد پر تو بحث ہے ، لیکن مکررات یا دیگر کتب میں مشترکات پر کوئی تحقیق موجود نہیں ہے ، حالانکہ یہ کتاب کافی کے تعارف پر سب سے تفصیلی کتاب شمار ہوتی ہے ،اس مضمون میں کتب اربعہ کی مکرر و مشترک روایات جاننے کے لئے کتب اربعہ کی روایات کو یکجا کر نے والے محسن کاشانی کی کتاب الوافی سے اندازہ لگایا گیا ، بعد کے ادوار میں لکھنے جانی والی ضخیم کتب جیسے بحار و وسائل الشیعہ وغیرہ پر بھی اس قسم کا کوئی مواد موجود نہیں ہے ۔
4۔ زمانہ روایت
اہل تشیع اور اہل سنت کے حدیثی مفاہیم و اصطلاحات کا ایک بڑا فرق زمانہ روایت کا فرق ہے ، زمانہ روایت سے مراد وہ زمانہ ہے ، جس میں محدثین اپنی سند کے ساتھ احادیث و روایات جمع کرتے ہیں ، زمانہ روایت کی لکھی گئی کتب احادیث عمومی طور پر اصلی مصادر و ماخذ شمار ہوتی ہیں ، بعد والے انہی مصادر پر اعتماد کرتے ہیں اور کسی حدیث کا حوالہ دیتے وقت عموما انہی کتب کے مصنفین کی تخریج کا حوالہ دیتے ہیں ، اہلسنت کے حدیثی ذخیرے میں زمانہ روایت ایک قول کے مطابق تیسری صدی ہجری اور دوسرے قول کے مطابق پانچویں صدی ہجری تک ہے۔
ڈاکٹر ضیاء الرحمان الاعظمی رواۃ کی تقسیم پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
إن هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر من أنسب التقاسيم للرواة؛ حيث ينتهي عصر الرواية بآخر المئة الثالثة على رأي بعض العلم ، وهو عصر الأئمة الستة ومن معهم، كبقي ابن مخلد (ت 276ھ)، والإسماعلي القاضي (ت 282ھ)، والإسماعيلي أبو بكر محمد بن إسماعيل (ت 289هـ)، والبزار (ت292هـ)، ومحمد بن نصر المروزي (ت294هـ)، وغيرهم ، لذا يرى الذهبي عام ثلاثمائة حدا فاصلأبين المتقدم والمتأخر.إلا أن عصر الرواية استمر إلى نهاية القرن الخامس؛ لأنه توجد روايات مخرجة في مصنفات البيهقي، والخطيب، وابن عبد البر، وابن حزم، وغيرهم من الحفاظ۔
(مجم مصطلحات الحديث ولطائف الاسانید ، ضیاء الرحمان الاعظمی ، دار ابن حزم ، بیروت ، ص 246)
ترجمہ : حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے رواۃ کے طبقات کی جو تقسیم کی ہے ، وہ مناسب تقسیم ہے ، کیونکہ بعض اہل علم کے نزدیک تیسری صدی ہجری کے اختتام پر زمانہ روایت ختم ہو جاتا ہے ، تیسری صدی ہجری صحاح ستہ اور دیگر جیسے بقے بن مخلد ،اسماعیل قاضی ، محمد بن اسماعیل ، امام بزار ، امام مروزی وغیرہ کا زمانہ ہے ،اسی وجہ سے علامہ ذہبی نے متقدمین و متاخرین کے درمیان حد فاصل تیسری صدی ہجری کو قرار دیا ہے۔ البتہ صحیح بات یہ ہے کہ زمانہ روایت پانچویں صدی ہجری کے اختتام تک جاتا ہے ، کیونکہ امام بیہقی ، خطیب بغدادی ، ابن عبد البر اور بن حزم جیسے حفاظ حدیث کی تصانیف میں ایسی روایات ملتی ہیں ، جن کی تخریج انہی حضرات نے کی ہے ۔
اہل سنت میں پانچویں صدی ہجری کے بعد حدیث کی مستقل کتاب نہیں لکھی گئی، بلکہ پانچویں صدی کے بعد پچھلی کتب کی شرح ، جمع، تلخیص ، تخریج وغیرہ پر کام ہوا ہے ۔
اہل سنت کے برعکس اہل تشیع اس معاملے میں الگ زاویہ نظر کے حامل ہیں ، اہل تشیع کے ہاں زمانہ روایت کی کوئی تحدید نہیں ہے ، بلکہ اہل تشیع کے ہاں حدیث کی مستقل کتب زمانہ حال یعنی تیرہویں اور چودہویں صدی میں بھی لکھی گئیں ہیں ، چنانچہ مرزا حسین نوری طبرسی کی کتاب مستدرک الوسائل اہل تشیع کے آٹھ مصادر اصلیہ میں سے ایک اہم کتاب ہے اور اس کتاب کے مصنف علامہ طبرسی 1320ھ میں وفات پاگئے ، یعنی چودہویں صدی ہجری کے مصنف کی لکھی گئی کتاب بھی اصلی حدیثی مصادر میں شمار ہوتی ہے ، یاللعجب ۔
اس کتاب کے بارے میں معروف شیعہ محقق آغا بزرگ طہرانی لکھتے ہیں :
"وهو رابع المجاميع الثلاثة الاخيرة المعتمدة المعول عليها في هذه الاعصاراعنى الوافي ،والوسائل والبحار"۔
(الذریعہ الی تصانیف الشیعہ ، آغا بزرگ طہرانی ، دار الاضواء ، بیروت، ج 21، ص 7)
مستدرک الوسائل آخری زمانے میں لکھی گئی تین معتمد کتب ( وافی ، وسائل الشیعہ ، بحار الانوار ) کے بعد چوتھی کتاب ہے ، جن پر اس زمانے میں حدیث کے معاملے میں اعتماد کیا جاتا ہے۔
مرزا حسین نوری طبرسی نے اس کتاب میں جتنی احادیث نقل کی ہیں ، کتاب کے خاتمے میں ان تمام مصادر تک اپنی سند ذکر کی ہیں ، یوں یہ کتاب مرزا نوری طبرسی کی سند و تخریج کے ساتھ حدیث کی مستقل کتاب ہے ، یہی وجہ ہے کہ اسے شیعہ کے آٹھ مصادر حدیث میں شمار کیا جاتا ہے ۔
اب یہاں بجا طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہلسنت کے ہاں تیسری یا پانچویں صدی ہجری میں زمانہ روایت و تخریج کا اختتام ہوتا ہے ، کیونکہ بعد زمانہ کے ساتھ سند کی تصحیح و اتصال کا احتمال کم سے کم ہوتا جاتا ہے ، بلکہ کثرت وسائط کی وجہ سے باجود اتصال سند کے روایت میں ضعف کا عصر قوی ہو جاتا ہے ، تو اہل تشیع کے ہاں جو کتاب ائمه معصومین کے بارہ سو سال بعد لکھی گئی ہے ، اس کتاب میں موجود احادیث کی سند کی کیا وقعت ہو گی؟
نیز مولف کتاب علامہ طبرسی نے کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں :
"وقد عثرنا على جملة وافرة من الاخبار ،لم يحوها كتاب الوسائل ،و لم تكن مجتمعة في مولفات الاواخر و الاوائل "۔ (مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، مرزا حسین نوری طبرسی ، موسسه ال البيت لاحياء التراث ، قم، ج1، ص60)
ہم احادیث کے ایسے بڑے حصے پر مطلع ہو چکے ہیں ، جن کا ذکر کتاب الوسائل میں نہیں ہے، نہ ہی وہ روایات اولین و آخرین شیعہ مصنفین کی کتب میں اکٹھی تھیں" مصنف نے کتاب کے خاتمے میں ان کتب میں سے پینسٹھ اہم مصادر کا ذکر کیا ہے ، مولف کے بقول ان کتب تک رسائل پچھلے مصنفین کی نہ ہو سکی ہے ، میری دسترس میں یہ کتب آچکی ہیں ، اس لئے میں نے ان سے روایات لی ہیں ، تو سوال یہ ہے کہ ایسی کتب جو اتنی نایاب اور پردہ خفا میں تھیں ، جن تک ایک ہزار سالہ شیعہ محدثین کی رسائی نہ ہو سکی ، ان کتب تک صدیوں بعد صرف علامہ طبرسی کی رسائی ہوئی ، تو صدیوں تک پردہ خفا میں رہنے والی کتب کی استنادی ، ثبوتی ، خطی ، نسبت الى المصنف ، وحفاظت من الاخطاء والاغلاط وغیرہ کا معیار کیا ہو گا؟ اہل علم واہل تحقیق پر اس کا جواب مخفی نہیں۔ اتنی غیر معروف مصنفین یا کتب سے جس کتاب میں احادیث نقل ہوئی ہیں ، وہ کتاب پھر بھی اصلی و معتمد مصادر میں شمار ہو ، جیسا کہ اوپر علامہ طہرانی کا قول گزر چکا ہے ، تو اس سے اہل تشیع کے حدیثی ذخیرے کی استنادی حیثیت اور صحت وضعف کے معیارات کا پتا چلتا ہے۔
(جاری ہے)