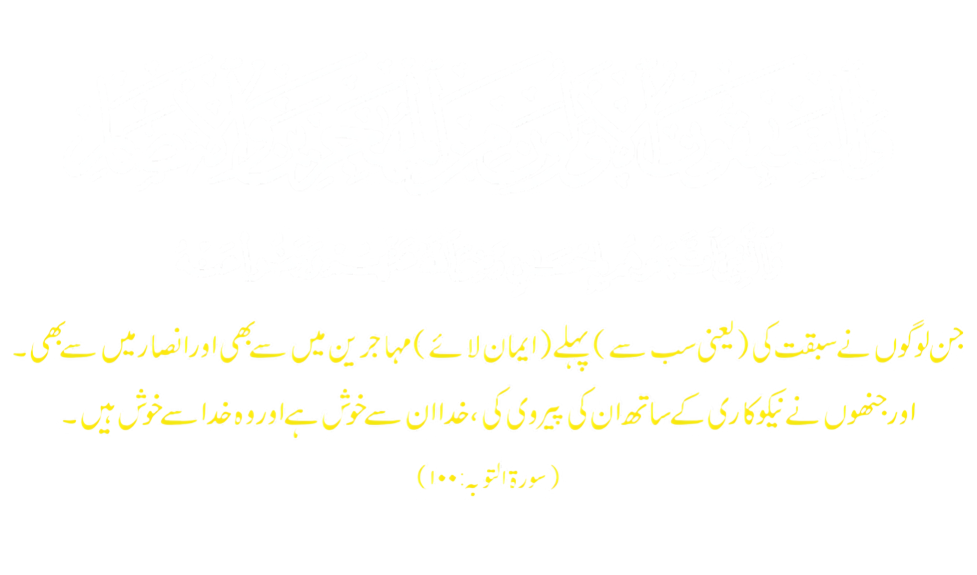فصل: ....کلبی کے مطاعن اور ان کا جواب
امام ابنِ تیمیہؒفصل کلبی کے مطاعن اور ان کا جواب
[اشکال]:شیعہ مصنف لکھتا ہے:’’جہاں تک صحابہ کے نقائص و معائب کا تعلق ہے ۔جمہور امت نے اس بارے میں بہت کچھ نقل کیا ہے؛ ا س کی حد یہ ہے کہ کلبی نے ’’مثالب صحابہ ‘‘ کے موضوع پر ایک مستقل کتاب تحریر کی ہے۔‘‘
[جواب]:ہم کہتے ہیں کہ اس بارے میں جوابا ت تفصیلی ہیں ۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو معائب منقول ہیں ان کی دو قسمیں ہیں :
معائبِ صحابہ کی قسم اوّل جھوٹی روایات:
جو کہ یا تو تمام کی تمام روایات ہی صاف اور کورا جھوٹ ہیں ۔یا پھر ان میں کمی اور زیادتی کر کے انہیں تحریف کا نشانہ بنایا گیا ہے؛جس کی وجہ سے ان میں مذمت اور عیب کا پہلو پیدا ہو گیا ہے۔
صحابہ کرامؓ کے بارے میں نقل کیے جانے والے اکثر مطاعن کا تعلق اسی باب سے ہے۔ انہیں روایت کرنے والے راوی اپنے جھوٹ اور دروغ گوئی میں معروف ہیں ۔ مثلاً ابو محنف لوط بن یحییٰ اور ہشام بن محمد بن سائب کلبی۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ مصنف ہشام کلبی کی تصنیفات سے دلائل پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ کلبی اور اس کا بیٹا ہشام دونوں شیعہ کذاب ہیں ۔[ہشام بن محمد بن سائب کا ذکر قبل ازیں گزر چکا ہے۔ ہشام کے والد کلبی کے متعلق محدث ابن حبان فرماتے ہیں :’’کلبی ابن سبا کے معتقدین میں سے تھا۔ وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ سیدنا علی ابھی فوت نہیں ہوئے وہ لوٹ کر آئیں گے اور کرہ ارضی کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جو رسے لبریز ہو چکی ہوگی۔تبو ذکی کہتے ہیں :’’ میں نے ہمام سے سنا، اس نے کلبی کو یہ کہتے سنا کہ میں سبائی عقیدہ رکھتا ہوں ۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ ابو النضر کلبی یحییٰ اور ابن مہدی کے نزدیک متروک الحدیث ہے۔ امام بخاریؒ نے کلبی کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ ’’ میں جو روایت ابوصالح سے بیان کروں وہ جھوٹی ہوتی ہے۔‘‘ محدث ابن حبان فرماتے ہیں کلبی کے مذہب اور اس کی دروغ گوئی کے پیش نظر اس کی تعریف بے سود ہے۔‘‘ کلبی بطریق ابو صالح از ابن عباس تفسیری روایات بیان کرتا ہے۔ حالانکہ ابو صالح نے ابن عباس کو دیکھا بھی نہیں ، کلبی نے بھی ابو صالح سے بہت تھوڑی روایات سنی ہیں ، مگر بوقت ضرورت کلبی ابوصالح سے لا تعداد روایات بیان کرتا ہے۔ تصانیف میں کلبی کا نام لینا بھی حلال نہیں اس کی روایات سے احتجاج تو درکنار۔‘‘ احمد بن زہیر کا قول ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبلؒ سے دریافت کیا۔’’کلبی کی تفسیر سے استفادہ کرنا حلال ہے یا نہیں ؟‘‘ آپ نے فرمایا:’’ نہیں ۔‘‘ محدث ابوعوانہ کہتے ہیں : ’’ میں نے کلبی کو یہ کہتے سنا: جبرائیل نبی کریمﷺ کو وحی لکھوایا کرتا تھا، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہو جاتے تو جبرائیل سیدنا علی کو وحی لکھواتے۔‘‘ محدث ابن معین یحییٰ بن یعلی سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں کلبی سے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ میں نے اسے یہ کہتے سنا۔ ’’ایک مرتبہ میں ایسا بیمار پڑا کہ مجھے سب کچھ بھول گیا۔ میں آل محمد کے پاس گیا اور انھوں نے میرے منہ میں اپنا تھوک ڈالا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ بھولا تھا دوبارہ مجھے یاد ہوگیا۔‘‘ میں نے یہ سن کر کہا میں آپ سے کوئی روایت بیان نہیں کروں گا۔ چنانچہ میں نے اسے ترک کردیا۔‘‘ ابو معاویہ کہتے ہیں ’’ میں نے کلبی کو یہ کہتے سنا:’’میں نے چھ یا سات دن میں قرآن حفظ کیا۔ دوسرا کوئی شخص اتنی جلد قرآن یاد نہیں کر سکتا اور میں ایسی چیز بھولا جس کو کوئی شخص فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی داڑھی پکڑ کر چاہا کہ اس میں معمولی تخفیف کروں گا مگر میں نے مٹھی کے اوپر سے کتر ڈالی۔‘‘ یہ ہیں کلبی سبائی کذاب کے بارے میں ائمہ حدیث کے ارشادات عالیہ۔ رافضی مصنف ایسے شخص کی کتاب سے ان صحابہ کے نقائص و معائب پر استدلال کرنا چاہتا ہے جو رسول اللہﷺ کے بعد اس کائنات ارضی پر ﷲ کی بہترین مخلوق تھے۔ ان کی عظمت و فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اعدائے اسلام بھی ان کے مقام رفیع سے انکار نہیں کر سکتے جو انھیں تاریخ اسلام میں حاصل ہے۔]یہ اپنے والد اور ابو مخنف دونوں سے روایت کرتاہے۔حالانکہ یہ دونوں متروک الحدیث اور کذاب ہیں ۔ امام احمد بن حنبلؒ کلبی کے بارے میں فرماتے ہیں :
’’ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص کلبی سے روایت کرتا ہو یہ تو صرف ایک داستان گو اور نسّاب تھا۔‘‘
امام دارقطنیؒ فرماتے ہیں : کلبی متروک الحدیث ہے۔
محدث ابن عدیؒ کہتے ہیں :’’ ہشام کلبی افسانہ گو تھا۔ مسند احمد میں اس سے کوئی حدیث مروی نہیں ۔ا س کا باپ بھی کذاب ہے۔‘‘
امام زائدہ و لیث و سلیمان رحمہما اللہ فرماتے ہیں :’’کلبی کذاب ہے۔‘‘
محدث یحییٰؒ فرماتے ہیں :’’ کلبی کذاب، ساقط الاحتجاج اور بے کار آدمی ہے۔‘‘
محدث ابن حبانؒ فرماتے ہیں :’’کلبی کا کاذب ہونا عیاں راچہ بیاں ‘‘ کے مصداق ہے۔
معائب صحابہ کی دوسری قسم
صحابہ پر دوسری قسم کے وہ اعتراضات ہیں جو بجائے خود صحیح ہیں ، مگر صحابہ کے عذرات کی بنا پر ان کو گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بلکہ وہ اجتہادی غلطی کی قسم کی چیز ہیں جس کے درست ہونے کی صورت میں دو اجر ملتے ہیں اور غلط ہونے کی صورت میں ایک اجر۔ خلفاء راشدینؓ کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں ۔ تاہم اگر بفرض محال ان میں سے کسی چیز کے بارے میں ثابت بھی ہو جائے کہ وہ گناہ ہے تو اس سے ان کے فضائل ومناقب اور جنتی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ گناہ کی سزا متعدد اسباب کی بنا پر آخرت میں ٹل بھی جاتی ہے۔ وہ اسباب یہ ہیں :
¹۔ توبہ گناہوں کو ختم دیتی ہے۔ شیعہ کے بارہ آئمہ کے بارے میں ثابت ہے کہ انھوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی۔
²۔ اعمال صالحہ گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں ۔نیکیاں برائیوں کے اثرات کو ختم کر دیتی ہیں ؛ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿اِنْ تَجْتَنِبُوْا کَبَائِرَ مَا تُنْہَوْنَ عَنْہُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّاٰتِکُمْ﴾ (النساء:31)
’’اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔‘‘
³۔ مصائب و آلام بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور ان سے گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔
⁴۔ مومنوں کی دعا سے بھی گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔
⁵۔ انبیاء کی شفاعت سے بھی گناہ دور ہو جاتے ہیں ۔
بہرکیف جن اسباب و وجوہ کی بنا پر افراد امت میں سے کسی کے گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے اور اس کی سزا کا ازالہ ممکن ہے صحابہؓ ان سب سے زیادہ اس امر کے مستحق ہیں کہ ان سے ذم و عتاب کو دور کیا جائے اور ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ اور صحابہ کرامؓ مدح و تعریف کے سب سے زیادہ حق دار ہیں ۔
ہم اس ضمن میں صحابہؓ اور دیگر افراد امت کے لیے ایک جامع قاعدہ ذکر کرتے ہیں ۔یہ ضروری ہے کہ انسان کو اس قاعدہ کلیہ کا علم ہو‘ تاکہ جزئیات کو اس کی طرف لوٹایا جائے ‘ تاکہ انسان علم کی روشنی میں عدل کے ساتھ بات کر سکے۔اور اسے جزئیات کے وقوع پذیر ہونے کی کیفیت کا بھی علم ہو ‘ ورنہ وہ ان جزئیات کے بارے میں ایسے ہی کذب و جہالت کا شکار رہے گا۔ کلیات و جزئیات میں جہالت اور ظلم کی وجہ سے بہت بڑا فساد اور شر پیدا ہوتا ہے ۔
قاعدہ جامعہ
عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کے لیے بنی نوع انسان کے پاس کچھ قواعد کلیہ ہوتے ہیں جن پر رکھ کر جزئیات کو جانچا پرکھا جاتا ہے ۔ پھر جزئیات کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان جزئیات سے بے بہرہ رہتا اور کلیات کے بارے میں جہل و ظلم کا شکار ہو جاتا۔ جس سے عظیم فساد رونما ہوتا ۔ علماء نے مجتہدین کے خطاء و صواب اور گنہگار یا عدم گنہگار ہونے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس ضمن میں بیش قیمت قواعد نافعہ بیان کرتے ہیں ۔ ہم کہتے ہیں کہ : لوگوں نے اصولی اور فروعی مسائل میں مجتہدین کو بجانب حق یا خطا پر کہنے میں بڑی لے دے کی ہے ؛ بعض نے انہیں گنہگار ٹھہرایا ہے ؛ اور بعض نے عدم گناہ کا کہا ہے ۔ مگر ہم اس بارے میں انتہائی جامع اور فائدہ مند اصولوں کا ذکر کرتے ہیں :
اصل اوّل کیا مجتہد کے لیے یہ ممکن ہے کہ اپنے اجتہاد کے بل بوتے پر معلوم کر لے کہ فلاں متنازع مسئلہ حق ہے؟ اور اگر یہ ممکن نہیں اور مجتہد انتہائی سعی و جہد کے باوجود حق کو نہ پاسکے اور کہے کہ میرے علم کی حد تک یہ حق ہے، حالانکہ وہ حق نہ ہو تو کیا اسے سزا دی جائے گی یا نہیں ؟ یہ اس مسئلہ کی اساس و اصل ہے ۔ علماء کے اس میں تین اقوال ہیں ۔ ہر قول کو اہلِ علم مناظرین کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے۔
پہلا قول: .... اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلہ میں حق کی ایک دلیل مقرر کر رکھی ہے۔ جو شخص کما حقہ جہد و کاوش سے کام لیتا ہے وہ حق کو پالیتا ہے۔اور جو شخص کسی اصولی یا فروعی مسئلہ میں حق کو معلوم کرنے سے قاصر رہتا ہے؛ اس کی وجہ اس کا تساہل و تغافل ہے۔ قدریہ و معتزلہ یہی نظریہ رکھتے ہیں ۔ ان کے علاوہ متکلمین کا ایک گروہ بھی اسی کا قائل ہے۔
پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ: علمی مسائل پر قطعی دلائل موجود ہوتے ہیں جن سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ پس جو کوئی بھی ان ادلہ کو نہ جانتا ہو؛ تو اس کے لیے طلب حق میں اپنی سعت بروئے کار لانا ممکن نہیں ؛ پس وہ گنہگار ہوگا۔
شرعی عملی مسائل کے سلسلہ میں ان کے دو مذہب ہیں
پہلا مذہب : یہ بھی شرعی علمی مسائل کی طرح ہیں ۔ اور بیشک ہر ایک مسئلہ پر ایک قطعی دلیل موجود ہوتی ہے ۔ اور اس کی مخالفت کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اوریہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں : اصلی اور فرعی ہر ایک مسئلہ میں ایک ہی فریق حق پر ہوتا ہے۔اور فریق برحق؍درست والے کے علاوہ باقی لوگ گنہگار ہوتے ہیں کیونکہ وہ خطا پر ہوتے ہیں ۔ ان کے نزدیک خطاء اور گناہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں ۔ یہ قول بشر المریسی اور بہت سارے بغدادی معتزلہ کا ہے۔
بیشک عملی شرعی مسائل پر اگرچہ قطعی دلائل موجود ہوں ؛ تو پھر بیشک علمی مسائل کی طرح ان میں بھی مخالفت کرنے والا خطاکار اور گنہگار ہوگا۔ اور اگر اس پر کوئی قطعی دلائل نہ ہو تو اس کے باطن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہوگا۔ ہر مجتہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے اجتہاد کے انجام کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ لوگ پہلے قول والوں سے اس حدتک متفق ہیں کہ خطا اور گناہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں ۔ اور بیشک ہر خطاکار گنہگار ہوگا۔ لیکن اجتہاد مسائل میں انہوں نے مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں : اس سلسلہ میں کوئی قطعی بات نہیں ہے۔ اوران لوگوں کے نزدیک ظن پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ تو بالکل انسانی نفس کے کسی ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف میلان کی طرح ہے۔ پس یہ لوگ ظنی اعتقادات کو ارادہ کی جنس سے شمار کرتے ہیں ۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نفس امر میں حکمِ اجتہاد مطلوب نہیں ۔اور نہ ہی نفس الامر میں کوئی امارت کسی امارت سے زیادہ ارجح ہوتی ہے۔ یہ قول ابو ہذیل العلاف اور اس کے اتباع کاروں جیسے جبائی اور اس کے بیٹے کا قول ہے۔ اور اشعری کا بھی ایک مشہور قول یہی ہے۔ اور قاضی ابو بکر الباقلانی ؛ ابو حامد الغزالی؛ اور ابو بکر ابن العربی اور ان کے اتباع کاروں نے یہی قول اختیار کیا ہے؛یہ مسئلہ ہم کئی جگہ تفصیل سے بیان کر چکے۔
ان کے مخالف جیسے ابو اسحق اسفرائینی ؛اور دوسرے اشاعرہ ؛ اور ان کے علاوہ دیگر لوگ ؛ وہ کہتے ہیں : اس قول کی ابتداء دہوکہ بازی پر ہے اور انتہاء زندیقیت پر۔ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں : بیشک شرعی اجتہادی عملی مسائل میں ہر مجتہد ظاہر اور باطن میں حق پر ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ مجتہد غلطی پرہو؛ مگر یہ ہوسکتا ہے کہ اس پر بعض امور مخفی رہ گئے ہوں ۔ پس جو حکم کسی پر مخفی رہ جائے؛ وہ اس مجتہد اور اس کے امثال و ہمنواؤں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہوسکتا۔ اور جو کوئی خطاء پر ہو؛ وہ قطعی مسائل میں بھی خطا پر ہے اور ان کے نزدیک وہ گنہگار ہے۔
دوسرا قول:....استدلال کرنے والا مجتہد بعض اوقات حق کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوسکتا۔ بصورت عجز اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو سزا دیتے ہیں اور بعض اوقات نہیں ۔کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عذاب دیں اور جسے چاہیں بغیر کسی سبب کے معاف کر دیں ۔یہ تمام امور اس کی مشئیت محضہ کے تحت ہوتے ہیں ۔یہ جہمیہ واشاعرہ کا مذہب ہے اور مذاہب اربعہ کے اکثر اتباع بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں ۔
پھر یہ لوگ کہتے ہیں : یہ بات یقیناً دلائل سے معلوم ہوچکی ہے کہ ہر کافر جہنم کی آگ میں ہو گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بلاشک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر کافر کو عذاب دیں گے۔ بھلے اس نے اجتہاد کیا ہو اوروہ دین اسلام کی صحت تک رسائی سے عاجز آ گیا ہو۔یا پھر اس نے اجتہاد نہ کیا ہو۔ جبکہ اختلاف کرنے والے مسلمان؛ اگرچہ ان کا اختلاف فروعی مسائل میں ہوتا ہے؛تو پھر بھی ان کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ: ان مسائل میں کوئی عذاب کی بات نہیں ۔اور ان کے بعض لوگ کہتے ہیں : اس کی وجہ یہ ہے کہ شارع نے ان چیزوں میں خطاء کو معاف رکھا ہے۔ اور سلف صالحین کے اجماع سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اجتہاد میں خطا کا ارتکاب ہو جانے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور بعض کہتے ہیں : ظنی مسائل میں خطا ممکن ہی نہیں ہوتی۔جیسا کہ جہمیہ اور اشاعرہ سے اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔
جب کہ قطعیات میں ان کی اکثریت خطا کار کو گنہگار کہتی ہے اوران کا کہنا ہے کہ: سماعت اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور ان میں سے بعض اس پر گنہگار نہیں کہتے۔ یہ قول عبیداللہ بن الحسن العنبری سے حکایت نقل کیا گیا ہے۔اس کا معنی یہ ہے کہ: آپ اس امت کے خطا کار مجتہدین کو گنہگار نہیں ٹھہراتے۔ نہ ہی اصول میں اور نہ ہی فروع میں ۔ جب کہ اہل کلام اور اہل رائے دونوں گروہوں کے جمہور نے عبیداللہ کا یہ قول رد کیا ہے۔
جبکہ ان کے علاوہ دوسرے حضرات کہتے ہیں : آئمہ فتوی اور سلف صالحین جیسے ابو حنیفہ : شافعی؛ اور ثوری اور داؤد بن علی اور ان کے علاوہ دیگر حضرات مجتہد خطا کار کو گنہگار نہیں کہتے ؛ نہ ہی اصولی مسائل میں اور نہ ہی فروعی مسائل میں ۔ جیسا کہ ان سے یہ قول ابن حزم او ردیگر علماء نے نقل کیا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور دیگر علماء أھل ھواء کی گواہی قبول کرتے ہیں سوائے خطابیہ کے۔ یہ حضرات ان کے پیچھے نماز کو بھی جائز اور صحیح کہتے ہیں ۔جب کہ کافر کی گواہی مسلمانوں کے خلاف قبول نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس کے پیچھے نماز پڑھی جاسکتی ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ:صحابہ و تابعین اور ائمہ دین سے معروف قول یہی ہے۔ وہ خطاکار مجتہدین میں کسی کو بھی نہ ہی کافر کہتے ہیں اور نہ ہی فاسق ؛ اور نہ ہی گنہگار۔نہ ہی علمی مسائل میں اور نہ ہی عملی مسائل میں ۔
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ: ’’ اصولی اور فروعی مسائل میں فرق کرنا اہل بدعت اہل کلام کے اقوال میں سے ہے؛ جن کا تعلق معتزلہ ؛ جہمیہ اور ان کی ڈگر پر رواں فرقوں سے ہے۔یہ عقیدہ کچھ دوسرے لوگوں میں منتقل ہوا تو انہوں نے اصول فقہ میں اس پر گفتگو کی ہے۔ انہیں اس قول کی حقیقت کا کوئی علم نہیں ہوسکا اور نہ ہی انہوں نے اس پر کوئی غور و فکر کیا۔
وہ کہتے ہیں : فروعی اور اصولی مسائل میں فرق کرنا اسلام میں ایک نئی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بلکہ سلف صالحین میں سے بھی کسی ایک نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی ۔ اور عقلاً بھی ایسا کہنا باطل ہے۔ اس لیے کہ اصولی اور فروعی مسائل میں تفریق کرنے والوں نے صحیح طرح سے ان کے مابین تفریق نہیں کی؛ جس کی وجہ سے دونوں اقسام باہم جدا ہو جاتیں ۔ بلکہ انہوں نے تین یا چار جتنے بھی اصول بیان کیے ہیں ؛ وہ سارے کے سارے باطل ہیں ۔
ان میں سے کوئی کہتا ہے: اصولی مسائل وہ علمی اعتقادی مسائل ہیں جن میں صرف عقیدہ اور علم کی طلب کی جاتی ہے۔ اور فروعی مسائل وہ ہیں جن میں عمل طلب کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں : یہ فرق باطل ہے۔ پس بیشک عملی مسائل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے منکر کو کافر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پنجگانہ کے وجوب کا منکر؛ ماہ رمضان کے روزوں اور زکواۃ؛ اور زنا ؛ سود اور ظلم اور فحاشی کے حرام ہونے کا انکار کرنا۔ اور علمی مسائل میں سے بعض ایسے ہیں جن میں اختلاف کرنے والے گنہگار نہیں ٹھہرتے۔ جیسے صحابہ کرامؓ کااختلاف کہ کیا محمدﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں ؟ اور بعض نصوص کے متعلق ان کے مابین اختلاف کہ کیا نبی کریمﷺ نے یہ کچھ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں ؟ اور پھر اس کے معانی سے کیا مراد ہے؟ اور جیسا کہ بعض کلمات میں بھی ان کا اختلاف ہے ؛ کیا یہ کلمات قرآن میں سے ہیں ؛ یا نہیں اور جیسا کہ قرآن و سنت کے بعض کلمات کے معانی میں ان کا اختلاف ہے ۔کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی مراد ایسے ایسے ہی تھی؟ اور جیسا کہ علم کلام کے دقیق مسائل میں لوگوں کا اختلاف ہے ؛ جیسے جوہر اور فرد کا مسئلہ ؛ اور تماثل اجسام؛ بقاء الاعراض ؛اور اس طرح کے دیگر مسائل ۔ ان میں نہ ہی کسی کو فاسق کہا جاتا ہے اور نہ ہی کافر ۔
کہتے ہیں : عملی مسائل میں علم بھی ہوتا ہے اور عمل بھی۔ جب ان میں غلطی قابل بخشش ہے: تو پھر وہ مسائل جن میں عمل کے بغیر صرف علم پایا جاتا ہے؛ زیادہ اولیٰ ہے کہ ان میں خطاء قابل بخشش ہو۔
ان میں سے بعض کہتے ہیں : اصولی مسائل وہ ہیں جن پر قطعی دلیل پائی جائے اور فرعی وہ مسائل ہیں جن پر قطعی دلیل نہ ہو۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ: اس فرق میں بھی غلطی پائی جاتی ہے؛ بیشک بہت سارے عملی مسائل ہیں ایسے ہیں جن پر اہل علم کے ہاں قطعی دلیل پائی جاتی ہے۔ مگر دوسرے لوگ انہیں نہیں جانتے۔ اور ان میں سے بعض پر اجماع کی روشنی میں قطعی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے ظاہری محرمات کا حرام ہونا۔ اور ظاہری واجبات کا واجب ہونا۔ پھر اگر کوئی انسان جہالت سے یا تأویل کی بنا پر ان کا انکار کرے تو اسے اس وقت تک کافر نہیں کہا جائے گا جب تک اس پر حجت قائم نہ کر لی جائے۔ جیسا حضرت عمرؓ کے عہد میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شراب کو [تاویل کی بنا پر] حلال سمجھتے تھے؛ ان میں سے ہی حضرت قدامہ بھی تھے ۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے لیے شراب حلال ہے۔ لیکن صحابہ کرامؓ نے انہیں کافر نہیں کہا۔حتیٰ کہ ان کے سامنے مسئلہ کھول کر بیان کیا گیا؛ اور ان کی غلطی ان پر واضح کی گئی؛ تو انہوں نے توبہ کرکے اپنی غلطی سے رجوع کرلیا۔
رسول اللہﷺ کے عہد مسعود میں صحابہ کے ایک گروہ نے طلوع صبح کے بعد اس وقت تک کھایا پایا یہاں تک کالا دھاگہ سفید دھاگے سے جدا نظر آنے لگا۔ مگر نبی کریمﷺ نے انہیں گنہگار نہیں ٹھہرایا؛ کجا کہ ان کی تکفیر کی جاتی ۔ لیکن ان کی غلطی ایک قطعی غلطی تھی۔
ایسے ہی حضرت اسامہ بن زیدؓ کا مسئلہ بھی ہے؛ جنہوں نے ایک مسلمان کو غلطی سے قتل کردیا تھا۔ اس میں ان کی غلطی قطعی غلطی تھی۔
ایسے ہی صحابہ کرامؓ نے بکریوں کے ایک چرواہے کو پایا؛ اس نے تو کہا : میں مسلمان ہوں ؛ مگر ان لوگوں نے اسے قتل کرکے اس کے مال پر قبضہ کرلیا۔ ان کی یہ غلطی ایک قطعی غلطی تھی۔ اور ایسے ہی جب حضرت خالد بن ولیدؓ نے جب بنو جذیمہ کو قتل کردیا؛ اور ان کے اموال قبضہ میں کرلیے ؛ تو یقیناً وہ قطعی غلطی پر تھے۔ایسے ہی جن لوگوں نے سرگوشیاں سننے کی کوشش کی تھی ؛ اور حضرت عمارؓ جو کہ جنابت کی وجہ سے مٹی میں ایسے لوٹ پوٹ ہوئے تھے جیسے جانور ہوتا ہے؛ اور ایسے ہی وہ لوگ جنہیں جنابت لاحق ہوئی تھی؛ تو نہ ہی انہوں نے تیمم کیا اور نہ ہی نماز پڑھی ۔ یہ سبھی حضرات غلطی پر تھے۔
ہمارے اس زمانے میں اگر کسی دور دراز بستی کے لوگ اسلام قبول کر لیں ؛ اور انہیں حج کے فرض ہونے کا علم نہ ہو ؛ یاپھر انہیں شراب حرام ہونے کا علم نہ ہو۔ تو انہیں اس چیز پر حد نہیں لگائی جائے گی۔ یہی حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایسی جگہ پر پلے بڑھے ہوں جہاں جہالت کا غلبہ ہو۔
جیسا کہ اس عورت کا واقعہ ہے جس نے حضرت عمرؓ کے عہد میں زنا بھی کیا؛ او راس کا اقرار بھی کیا ؛ تو عثمانؓ نے فرمایا کہ : ’’یہ ایسے کھلے اعلانیہ اقرار کرتی ہے شاید کہ یہ زنا کے حرام ہونے کے حکم سے جاہل ہے۔‘‘ تو جب صحابہ کرامؓ پر واضح ہوگیا کہ یہ زنا کو حلال سمجھتی ہے؛ تو اس پر کوئی حد نہیں لگائی۔ اور زنا کو حلال سمجھنا قطعی غلطی تھی۔
ایسے ہی کوئی انسان جب کسی معاملہ میں قسم اٹھائے؛ اور وہ چیز اس کے اعتقاد کے برعکس ہو‘ تو جب اس پر حقیقت واضح ہو جائے تواس کا خطا کار ہونا تو قطعی ہوگا؛ مگر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اور اکثر لوگوں کے نزدیک اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔
ایسے ہی جو انسان اس اعتقاد اور سوچ سے کچھ کھا پی لے کہ ابھی طلوع فجر باقی ہے؛ تو پھر اس کی غلطی واضح ہو جائے کہ اس نے فجر کے بعد کھایا پیا ہے۔ تو وہ بالیقین قطعی خطا پر ہے مگر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔لیکن اس روزہ کے قضاء کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایسے ہی جس کا خیال ہوکہ سورج غروب ہوگیا ہے؛ اور وہ افطار کرلے؛ پھر اس کے خلاف ظاہر ہو۔ ایسے مسائل بہت زیادہ ہیں ۔
اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِنْ نَّسِیْنَا اَوْ اَخْطَانَا﴾ (البقرۃ:286)
’’اے ہمارے رب! اگر ہم سے بھول یا چوک ہو جائے تو ہم پر مواخذہ نہ کر۔‘‘
[تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ]میں نے ایسا کر دیا۔‘‘
[اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے نسیان و خطاء کو معاف کر دیا ہے]اس میں قطعی اور ظنی میں کوئی فرق نہیں کیا۔ بلکہ اسے قطعی طور پر خطاء بھی نہیں کہا؛ ہاں اس صورت میں کہ اس کی خطاء قطعی اور یقینی ہو۔
وہ کہتے ہیں : جس نے یہ کہا ہے کہ: کسی قطعی یا ظنی مسئلہ میں خطاء کا شکار ہونے والا گنہگار ہے؛ تو یقیناً اس نے کتاب و سنت اور قدیم اجماع امت کے خلاف کیا۔اور مزید یہ بھی کہتے ہیں : ’’کسی مسئلہ کا قطعی یا ظنی ہونا ؛ معتقدین کے احوال کے حساب سے ایک اضافی امر ہے۔ اور نہ ہی یہ نفس قول کا وصف ہے۔ بیشک انسان ایسی چیزوں کو قطعی کہتا ہے جن کا علم اسے ضروری طور پر حاصل ہو۔ یا پھر اس کے نزدیک اس کی سچائی نقل سے قطعی معلوم ہو۔ اور کسی دوسرے کو نہ ہی اس کا قطعی علم ہو اور نہ ہی ظنی ۔ بیشتر اوقات کوئی انسان ذہن و فطین ہوتا ہے؛ اس کا علمی اور ظنی ادراک بہت سریع [تیز] ہوتا ہے۔ اور وہ حق کو فوراً پہچان لیتا ہے؛ اور اسے وہ قطعی علم حاصل ہو جاتا ہے جس کی معرفت علمی یا ظنی کا دوسرا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ پس یہ قطعی اور ظنی ؛انسان تک پہنچنے والی ادلہ؛ اور اس کے استدلال پر دسترس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔
ان دونوں مسئلوں میں لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں ۔ پس کسی مسئلے کا قطعی یا ظنی ہونا اس کی اور متنازعہ فیہ قول کے لیے کوئی لازمی صفت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے: جس نے اس کے خلاف کیا؛ اس نے دلیل قطعی کے خلاف کیا۔بلکہ یہ مسئلہ میں غور وفکر کرنے والے؛ اور اس سے استدلال کرنے والے کے معتقد کے اعتبار سے ہے۔یہی تو وہ چیز ہے جس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس فرق کو نہ ہی رد کیا جاسکتا ہے او رنہ ہی اس کا الٹ کرنا ممکن ہے۔
کچھ علمائے کرامؒ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس میں ایک تیسرا فرق نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں : اصولی مسائل عقل کے ذریعہ سے معلوم شدہ ہیں ۔ پس ہر وہ علمی مسئلہ جس کا ادراک عقل بذات خود کرلے؛ یہی وہ مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مخالف پر کفر یا فسق کا فتویٰ لگایا جاسکتا ہے۔جب کہ فرعی مسائل شریعت کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں ۔
پہلی قسم کی مسائل جیسے مسائل قضاء و قدر؛ اور دوسری قسم کی مثال: جیسے شفاعت اور کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگوں کا جہنم سے نکالا جانا۔
تو ان سے کہا جائے گا: تم نے جو کچھ بیان کیا ہے؛ وہ پہلے مسئلہ کی ضد اور الٹ ہے۔ بیشک کفر اور فسق بھی شرعی احکام میں سے ہیں ۔یہ ایسے مسائل ہرگز نہیں ؛ جنہیں صرف عقل کی بنیاد پر معلوم کیا جاسکے۔پس کافر تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول کافر بتائیں ؛ اور فاسق وہ ہوتا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول فاسق بتائیں ۔ جیسا کہ مسلمان اور مؤمن تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول مسلمان اور مؤمن بتائیں ۔ ایسے ہی عادل وہ ہوتا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول عادل بتائیں ؛ اور معصوم الدم وہ ہوتا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول معصوم الدم بتائیں ۔ اور آخرت میں سعید اور خوش بخت ہوگا جسے اللہ اور اس کا رسول خوش بخت بتائیں ؛اور بد بخت وہ ہوگا جسے اللہ اور اس کا رسول بد بخت بتائیں ۔ اور نماز و روزہ اور صدق اور حج میں سے وہ چیزیں واجب ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول واجب بتائیں ۔وراثت کے مستحق وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول اس کے مستحق ٹھہرائیں ۔اور حد یا قصاص میں قتل کا مستحق وہ ہوگا جسے اللہ اور اس کا رسول اس کا مستحق؍مباح الدم ٹھہرائیں ۔اور مال خمس یا فئے کا مستحق وہی ہوگا جسے اللہ اور اس کا رسول اس کا مستحق بتائیں ۔اور دوستی اور دشمنی کے مستحق وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول اس کے مستحق بتائیں ۔حلال وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول حلال قرار دیں ؛ اور حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حرام ٹھہرائیں ۔ دین وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول شریعت قرار دیں ۔ یہ تمام مسائل شریعت سے ثابت ہیں ۔
وہ امور جو صرف عقل سے معلوم کئے جاسکتے ہیں جو طبیعیت سے تعلق رکھتے ہوں ۔ مثلاً یہ کہ فلاں مرض میں فلاں دوائی کار گر ہوتی ہے۔ بیشک ایسے امور تجربہ اور قیاس اور ان اطباء کی تقلید سے معلوم ہوتے ہیں جو تجربہ و قیاس سے معلوم کر چکے ہوں ۔ ایسے ہی حال حساب اور ہندسہ کے مسائل کا بھی ہے۔ یہ ان مسائل میں سے ہیں جنہیں عقل کے ذریعہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ایسے ہی جوہر اور فرد ؛ اور تماثل اجسام اور ان کے اختلاف اور اعراض کے بقاء کے جواز او رامتناع کے مسائل بھی ہیں ۔ پس یہ ایسے مسائل ہیں جو عقل کے ذریعہ سے معلوم کئے جاسکتے ہیں ۔
جب معاملہ ایسے ہی ہے تو پھر کسی انسان کا مسلمان یا کافر ہونا یا عادل یا فاسق ہونا؛ شرعی مسائل میں سے ہیں عقلی مسائل میں سے نہیں ۔ پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کوئی رسول اللہﷺ کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف کرے؛ وہ تو کافر نہ ہو؛ مگر جو کوئی غیر نبی کے اس دعویٰ کہ:’’یہ چیز عقل سے معلوم ہے‘‘ کے خلاف کرے تو وہ کافر ہو جائے ۔ تو کیا کسی کو حساب ؛ طب اور دیگر دقیق کلام میں غلط کی وجہ سے کافر کہا جائے ۔
پس اگر یہ کہا جائے کہ: ’’وہ تمام لوگ جو ہر قسم کے عقلی مسائل میں مخالفت کرتے ہیں ؛ ان کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ہاں جو ان عقلی مسائل میں مخالفت کریں جن سے رسول اللہ کی صداقت معلوم ہوتی ہو۔ پس بیشک رسول اللہﷺ کی صداقت کا علم پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ چند متعین مسائل ہیں ؛ جب انسان ان میں خطا کرتا ہے؛ اور اسے رسول اللہﷺ کی صداقت کا علم نہ ہو۔تو وہ کفار ہوگا۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ: رسول اللہﷺ کی تصدیق اختلافی مسائل میں چند متعین مسائل پر مبنی نہیں ہوتی۔ بلکہ جدید اہل کلام نے اسے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بنیاد قرار ہی نہیں دیا تھا۔ جیسے معتزلہ اور جہمیہ میں سے ان لوگوں کا قول جو کہتے ہیں کہ: ’’ بیشک صداقت رسول کا علم اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ عالم حادث ہے۔ اور اس کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس وقت تک یہ علم حاصل نہ ہو جائے کہ ’’اجسام محدث ہیں ۔‘‘ اور اس کا علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک یہ علم نہ ہو کہ یہ دوسرے حوادث سے جدا نہیں ہوسکتے: یا تو وہ مطلق اعراض ہوں گے یا پھر اکوان ہوں گے یا پھر حرکات ہوں گے۔ اور ان کا حادث ہونا اس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتا جب تک ایسے حوادثات کا علم نہ ہو جائے جن کی کوئی ابتداء نہیں ۔اور ان کی سچائی کا اس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتا جب تک یہ علم نہ حاصل ہو جائے کہ ’’رب سبحانہ و تعالیٰ غنی اور بے نیاز ‘‘ ہیں ۔ اور اس کا غنی ہونا اس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ جسم نہیں ہے۔
ایسے ہی دیگر وہ امور جن کے بارے میں اہل کلام کے ایک طائفہ کا گمان ہے کہ وہ اصول ہیں ؛ کیونکہ وہ رسول اللہﷺ کی تصدیق کو متضمن ہیں ؛ اور ان کے بغیر آپ کی صداقت معلوم نہیں ہوسکتی۔ یہ امور رسول اللہﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضطراری طور پر معلوم ہیں ؛ لیکن آپﷺ نے لوگوں کے ایمان کو ان امور پر موقوف نہیں کیا؛ اور نہ ہی لوگوں کو ان کی دعوت دی؛ اور نہ ہی کتاب و سنت میں ان کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ اور نہ ہی صحابہ کرامؓ نے ان کا کوئی ذکر کیا ۔ لیکن وہ اصول جن سے رسول اللہﷺ کی صداقت معلوم ہوتی ہے؛ وہ قرآن میں مذکور ہیں ؛ اور یہ امور وہ نہیں ہیں جو ان لوگوں نے بیان کئے ہیں ۔ یہ بات ہم کئی ایک مواقع پر بیان کر چکے ہیں ۔
یہ لوگ جنہوں نے اصول ایجاد کر لیے ہیں ؛ ان کا خیال ہے کہ ان کے بغیر رسول اللہﷺ کی تصدیق ممکن نہیں ہے اور ان کی معرفت ایمان کے لیے شرط ہے۔ یا مختلف اعیان پر واجب ہیں ۔ یہ لوگ سلف صالحین اور آئمہ کے نزدیک اہل بدعت ہیں ۔ جمہور علماء جانتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے اصول شریعت اسلام میں ایک نئی بدعت میں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ عقلی رو سے یہ اصول بالکل صحیح ہیں ۔ جبکہ ائمہ ماہرین فنون اور ان کے متبعین جانتے ہیں کہ یہ اصول عقل کے لحاظ سے بھی باطل ہیں ۔ دین و شریعت میں بدعت ہیں : اور رسول اللہﷺ کے لائے ہوئے پیغام سے ٹکراؤ رکھتے ہیں ۔
پس درایں صورت اگر خطا عقلی مسائل میں ہو؛ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ: یہ دین کے اصول ہیں : تو پھر جو لوگ ان خود ساختہ باطل اصولوں پر چلتے ہیں جو کہ عقل میں باطل ؛ اور شریعت میں بدعت ہیں ؛ تو وہی لوگ کفار ہیں ؛ ان کے مخالفین نہیں ۔ اور اگر ان امور میں خطا کفر نہیں ہے؛ تو پھر ان کے مخالفین کو بھی کافر نہیں کہا جاسکتا۔ تواس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر دو صورتوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کافر نہیں ہیں ۔
لیکن اہل بدعت کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اقوال ایجاد کر لیتے ہیں : اور پھر انہیں دین میں واجب قرار دیتے ہیں ؛ یہی نہیں بلکہ انہیں ایمان قرار دیتے ہیں ؛ جس کا ہونا از بس ضروری ہو؛اور پھر جو کوئی ان کی مخالفت کرے ؛ اسے کافر کہتے ہیں ۔ اور ان کے خون کو حلال قرار دیتے ہیں ؛ جیسے خوارج ؛ جہمیہ ؛ روافض اور معتزلہ اور دیگر اہل بدعت فرقوں کا طریق کار ہے۔
جب کہ اہل سنت والجماعت نہ ہی اپنی طرف سے عقائد ایجاد کرتے ہیں ؛ اور نہ ہی اجتہاد میں خطاء کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں ۔ اگرچہ ان کا مخالف انہیں کافر اور حلال الدم سمجھتا ہو۔ اوروہ اپنے مخالفین دیگر مسلمانوں کو بھی حلال الدم سمجھتے ہوں ۔
ان مسائل میں ان متکلمین کا کلام کسی کی تصویب یا خطاء کاری کا حکم؛ گنہگار ہونے کا حکم لگانا یا اس کی نفی کرنا ؛ تکفیر اور اس کا انکار ؛ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اصولوں کی بنیاد اپنے متقدمین قدریہ کے اقوال و عقائد پر رکھی ہے؛ جو ہر استدلال کرنے والے حق کی معرفت پر قادر سمجھتے ہیں ۔ اور ہر اس انسان کو عذاب کا مستحق سمجھتے ہیں جو ان کی معرفت حاصل نہ کرسکے۔ اوران جہمیہ کے عقائد پر ہے؛ جو کہتے ہیں : انسان کو اصل میں کوئی بھی قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ محض اپنی مشئیت و ارادہ سے جس کو چاہے عذاب دیں ۔ وہ ایسوں کو بھی عذاب دے سکتا ہے جس نے کبھی کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو۔ اور کفر و فسق کے مرتکب کو اپنے انعامات سے نواز سکتا ہے۔ بہت سارے متأخرین نے اس عقیدہ میں ان لوگوں کی موافقت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے: ’’یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں اور پاگلوں کو عذاب دے؛ اگرچہ انہوں نے دنیا میں کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو۔ اور پھر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دو ٹوک الفاظ میں آخرت میں کفار کے بچوں کو عذاب دیے جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں ۔ اور ان میں سے بعض اسے جائز کہتے ہیں ؛ اور کہتے ہیں : ہم نہیں جانتے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔اور ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ اہل قبلہ میں سے کسی فاسق ترین انسان کو بغیر کسی سبب کے بخش دے؛ اور کسی نیک انسان کو کسی معمولی سی غلطی پر مبتلائے عذاب کردے۔ بھلے اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں ؛ اس کے لیے کسی سبب کا ہونا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی مرضی اور چاہت سے ایسا کرسکتے ہیں ۔
ان دونوں گروہوں کی اصل یہ ہے کہ: بیشک قادر اور مختار دو متماثلین میں سے کسی ایک کو دوسرے پر بغیر کسی وجہ کے ترجیح دے سکتا ہے۔ لیکن جہمیہ کہتے ہیں : وہ ہر ایک واقع ؍حادث میں بلا کسی مرجّح کے ترجیح دے سکتا ہے۔ اور قدریہ ؛ معتزلہ اورکرامیہ اور فقہاء و اہل حدیث اور صوفیہ کے کئی گروہ او ران کے علاوہ دیگر حضرات کہتے ہیں : احداث و ابداع کی اصل ترجیح بلا مرجح پر تھی۔ مگر اس کے بعد اسباب اور حکمت کو تخلیق کیا؛ اور حوادث کو ان کے ساتھ معلق کردیا۔
ظلم کے بارے میں جبریہ ؛ قدریہ اور جہمیہ کا اختلاف ہے۔ قدریہ کہتے ہیں : ظلم اس کے حق میں بھی وہی چیز ہے جسے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مابین ظلم کے نام سے جانتے ہیں ۔ اور جب یہ کہا جائے کہ: وہ بندوں کے افعال کا خالق ہے؛ اور جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اس کی مشئیت اور ارادہ سے پیش آتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ: وہ گنہگار کو عذاب دے گا؛[تو کیا]یہ ظلم بھی ہمارے ظلم کی طرح ہوگا؟یہ لوگ اپنے آپ کو عدلیہ کہتے ہیں ۔ اور جہمیہ کہتے ہیں : اس کے حق میں ظلم وہ چیز ہے جس کا وجود ممتنع ہو۔ پس جس چیز کا بھی وجود ممکن ہو؛ وہ ظلم نہیں ہے۔ پس بیشک ظلم یا تو ایسے حکم کی مخالفت کو کہا جاتا ہے جس کا کرنا واجب ہو؛ یا بھر کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کو ظلم کہتے ہیں ۔ پس انسان کے بارے میں تو کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی؛ اور اس لیے کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرتا ہے۔ مگر رب سبحانہ و تعالیٰ ہر حکم دینے والے سے بھی اوپر اور بلند و بالا ہیں ۔ اور اس کے بغیر کسی کی کوئی ملکیت نہیں ۔ بلکہ وہ جو بھی تصرف کرتا ہے؛ وہ اپنی ہی ملکیت میں تصرف کرتا ہے۔پس جو بھی ممکن ہے؛ وہ ظلم نہیں ہے۔ بلکہ اس نے فرعون اور ابو جہل اور ان کے امثال کافروں اور نافرمانوں پر اپنی نعمتیں کی تھیں ۔اور حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت محمدﷺ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اور اپنی اطاعت کرنے والوں کو تکلیف دی۔ اور اس کا الٹ بھی ہوا۔ یہ تمام اس کی نسب سے برابر ہیں ۔ لیکن جب اس نے خبر دی ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں پر انعام کرے گا؛ اور نافرمان کو عذاب دیتا ہے؛ تو یہ معاملہ اس خبر صادق کی وجہ سے معلوم الوقوع ہو گیا۔ کوئی اور سبب نہیں تھا جو اس کا تقاضا کرتا ہو۔ اعمال ثواب یا عقاب پر علامت ہیں : اس کے اسباب میں سے نہیں ہیں ۔
یہ جہم اور اس کے ساتھیوں ؛اور ان کی موافقت کرنے والوں جیسے اشعری ؛ اور اس کے موافقین اتباع فقہاء اربعہ اور صوفیاء اور دیگر لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ: وہ حق کی معرفت سے عاجز انسان کو عذاب دے؛ بھلے اس نے معرفت حق کی کوشش بھی کی ہو۔ پس ان لوگوں کے نزدیک نفس امر میں حوادث کے لیے نہ ہی اسباب ہوتے ہیں اور نہ ہی حکمت۔ اور نہ ہی افعال میں کوئی ایسی صفات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ یہ مامور یا ممنوع ہوتے ہیں ۔ بلکہ ان کے نزدیک ممتنع ہے کہ اس کی تخلیق اور حکم میں علت نام کی کوئی چیز ہو۔
جب کہ قدریہ بندوں پر قیاس کرتے ہوئے اس کے لیے شریعت میں حلال و حرام کو واجب ٹھہراتے ہیں ۔ ہم نے کئی ایک مواقع پر ان دونوں گروہوں کے عقائد پر بات کی ہے۔اور اس کتاب میں بھی اس سلسلہ میں ایک پوری فصل بیان کی ہے۔ جو کہ پہلے گزر چکی ہے۔ جب ہم نے اس رافضی پر اس قول میں رد کیا تھا جو اس نے جہمیہ اور جبریہ کا عقیدہ تمام اہل سنت و الجماعت کی طرف منسوب کیا تھا۔ اور ہم نے کھلے لفظوں میں واضح کیا تھا کہ اس مسئلہ کا امام یا تفضیل سے کوئی تعلق ہی نہیں ۔ بلکہ شیعہ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جبریہ اور قدریہ کا عقیدہ رکھتے ہیں ؛اور اہل سنت میں بھی ہر دو عقائد کے لوگ موجود ہیں ۔
یہاں پر مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ: بیشک متنازعین کے کلام میں تصویب کرنا؛ کہ وہ دونوں حق پر ہیں ؛ یا خطأ پر ہیں ؛ یا انہیں ثواب ملے گا؛ یا عقاب ہوگا؛ وہ دونوں مؤمن ہیں یا کافر ہیں ۔ یہ سب کچھ ان تمام مسائل اور دیگر مسائل کے لیے عام اور شامل اصول کی فرع ہے۔
تیسرا قول .ہر مجتہد حق کو معلوم کرنے پر قادر نہیں اور نہ ہی وعید کا مستحق ہے۔ بخلاف ازیں وہی مجتہد وعید کا مستحق ہو گا جو کسی فعل مامور کو ترک کر دے یا فعل محظور کا مرتکب ہو۔ یہ فقہاء ائمہ کا قول ہے، سلف صالحین اور جمہور اہل اسلام اسی کے قائل ہیں پہلے دونوں اقوال میں جو صحیح بات پائی جاتی ہے۔ یہ قول ان کا جامع ہے۔پہلے قول میں ان جہمیہ کی بات بھی درست ہے جو اس مسئلہ میں سلف صالحین اور جمہور کے عقیدہ کے موافق ہیں ؛ اوروہ یہ ہے کہ: ’’ایسا نہیں ہوسکتا کہ ہر وہ انسان جو طلب اور کوشش کرے؛ اور اجتہاد کرے؛ تو وہ اس مسئلہ میں حق کی معرفت پر متمکن بھی ہو جائے۔یقیناً لوگوں کی صلاحیات مختلف ہوتی ہیں ۔
قدریہ کہتے ہیں : ’’اللہ تعالیٰ نے تمام مکلفین کو برابر قدرت دی ہے۔ اس میں مؤمن کے لیے کافروں پر اس وقت تک کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے حتی کہ وہ ایمان لے آئیں ۔ اور ایسے ہی اطاعت گزاروں کو نافرمانوں پر اس تک کوئی فضیل نہیں ہے جب تک وہ اطاعت گزاری نہ کر لیں ۔
یہ قدریہ اور معتزلہ اور ان کے علاوہ دیگر ان فرقوں کا عقیدہ ہے جو کتاب و سنت اور اجماع سلف صالحین اور عقل صریح کے مخالف ہیں ۔ جیسا کہ یہ موضوع کئی مقامات پر تفصیل سے بیان ہوچکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں : بیشک ہر استدلال کرنے و الے کو قدرت تامہ حاصل ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ حق کی معرفت حاصل کر لے۔
یہ بات معلوم شدہ ہے کہ:جب دوران سفر لوگوں پر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو وہ تمام اس بات کے مامور ہیں کہ اجتہاد کرکے قبلہ کی جہت پر استدلال کریں ۔ پھر ان میں سے بعض قبلہ کا رخ پہچاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ۔ اور بعض اس سے عاجز آ کر غلطی کر بیٹھتے ہیں ۔ بعض جگہ پر یہ گمان ہوتا ہے کہ قبلہ کا رخ اس طرف ہے۔ مگر یہ بات درست نہیں نکلتی۔ مگر اس کے باوجود وہ انسان اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے؛ غلط رخ نماز پڑھنے پر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر کا مکلف نہیں ٹھہراتے۔ پس اس جہت کے معلوم کرنے سے عاجز آ جانا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو جہت قبلہ تو معلوم ہو؛ مگر وہ اس طرح رخ کرنے سے عاجز آ جائے۔ جیسے کوئی قید میں ہو؛ اسے ایسی حالت میں باندھا گیا ہو؛ یا پھر اسے خوف محسوس ہو رہا ہو۔ اوروہ مریض جس کے لیے قبلہ رخ کرنا ممکن نہ ہو۔
اصل ثانی .اصل ثانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اسی شخص کو سزا دے گا جو ترک مامور یا فعل محظور کی بنا پر اللہکی نافرمانی کرے۔معتزلہ اس اصول میں اہل سنت و الجماعت کے ساتھ یک زبان ہیں ۔بخلاف جھمیہ اور ان کی راہ پر چلنے والے اشاعرہ اور دیگر فرقوں کے۔جو کہتے ہیں کہ:’’وہ ایسوں کو بھی عذاب دے گا جن کا کوئی گناہ نہ ہو۔‘‘ اور اس طر ح کے دیگر اقوال بھی ہیں ۔
پھر یہ لوگ معتزلہ کے خلاف عقلی ایجاب و تحریم پر اس آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں :
﴿ وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِیْنَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا﴾ (الإسراء15)
’’ اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں ، یہاں تک کہ کوئی رسول بھیج دیں ۔‘‘
یہ آیت بھی ان کے خلاف عذاب کی نفی میں ایسے ہی حجت ہے؛ مگر رسولوں کے مبعوث کردینے کے بعد۔ جب کہ وہ رسولوں کو مبعوث کرنے سے پہلے بھی لوگوں کو عذاب دیے جانے کے قائل ہیں ۔ ان کا کہنا ہے کہ: جن کی طرف رسولوں کو مبعوث نہیں کیا گیا؛ ہ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کا قبیح ہونا عقلی طور پر معلوم ہے؛ اسے لیے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ جب کہ معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں : ایسے لوگوں کو بھی عذاب ہوگا جنہوں نے کبھی کوئی قبیح حرکت نہ کی ہو؛ جیسے چھوٹے بچے۔
یہ بات کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے۔کیونکہ فرمان الٰہی تو یہ ہے :
﴿ وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِیْنَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا﴾ (الإسراء15)
’’ اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں ، یہاں تک کہ کوئی رسول بھیج دیں ۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ آگے کے بارے میں فرماتے ہیں :
﴿کُلَّمَا اُلْقِیَ فِیْہَا فَوْجٌ سَاَلَہُمْ خَزَنَتُہَا اَلَمْ یَاْتِکُمْ نَذِیرٌ () قَالُوْا بَلٰی قَدْ جَائَنَا نَذِیرٌ فَکَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰہُ مِنْ شَیْئٍ اِِنْ اَنْتُمْ اِِلَّا فِیْ ضَلاَلٍ کَبِیْرٍ﴾ [الملک8۔9]
’’ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمھارے پا س کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟وہ کہیں گے کیوں نہیں ؟ یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو۔‘‘
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر عمومی الفاظ میں خبر دے رہے ہیں کہ:’’ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، تو جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے: کیا تمھارے پا س کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟
تو وہ ان کے آنے کا اعتراف کریں گے ؛ اور کہیں گے: کیوں نہیں ؟ یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا۔ تو پھر کوئی گروہ ایسا نہیں ہوگا جسے جہنم میں ڈالا جائے مگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ جیسے فرمان الٰہی ہے:
﴿ لاََمْلاََنَّ جَہَنَّمَ مِنْکَ وَمِمَّنْ تَبِعَکَ مِنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴾ (ص85)
’’میں ضرور بالضرور جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا۔‘‘
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں : کہ جہنم کو ابلیس اور اس کے اتباع گزاروں اور پیروکاروں سے بھرا جائے گا۔ اس کے پیروکار وہ ہیں جو اس کی بات مان کر چلتے ہیں ۔ پس جو کوئی گناہ کا نہیں کرتا؛ وہ اس کی اطاع سے گریز کرتا ہے۔ تو پھر اس کا شمار بھی ان میں نہیں ہوگا جن سے جہنم بھری جائے گا۔ جب جہنم اس کے پیروکاروں سے بھری ہوگی تو پھر کسی دوسرے کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔
صحیحین میں حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریمﷺ نے فرمایا:
’’ لوگ مسلسل جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے؛ اور جہنم کہتی جائے گی کہ:’’ اور کچھ باقی ہے؟ یہاں تک کہ رب العالمین اس میں اپنا پاؤں رکھ دیں گے۔ تو اس کے حصے آپس میں مل کر سمٹ جائیں ، پھر وہ کہے گی: کافی ہوگیا؛ کافی ہوگیا۔‘‘ جبکہ جنت میں جگہ باقی بچ جائے گی؛حتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی بچی ہوئی جگہ میں ٹھہرائے گا۔‘‘[صحیح بخاری:جلد2: ح: 2058]
صحاح میں کئی اسناد سے یہ حدیث یونہی روایت کی گئی ہے؛بخاری کی بعض اسناد میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ وہاں پر ہے: ’’جبکہ جہنم میں جگہ باقی بچ جائے گی ۔‘‘جبکہ بخاری کی تمام اسناد میں ہر جگہ پر صحیح الفاظ میں روایت کیا گیا ہے۔ اور آپ نے ایسے اس لیے کیا ہے تاکہ راوی کی غلطی کو واضح کرسکیں ؛ جیسا کہ ایسے مواقع پر آپ کی عادت ہے ۔جب کسی راوی سے الفاظ میں غلطی ہو جائے تو آپ ان الفاظ کو ذکر کرتے ہیں جو سارے راویوں کے ہاں منقول ہوتے ہیں ؛ اس سے صحیح بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ میرے علم کے مطابق بخاری میں کہیں پر کوئی ایسی غلطی واقع نہیں ہوئی جس کی اصلاح بھی انہوں نے نہ کردی ہو۔ بخلاف صحیح مسلم کے؛ ان کی صحیح میں کئی احادیث کے روایت کرنے میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ جن کی وجہ سے کئی حفاظ حدیث نے صحیح مسلم میں ان احادیث پر بہت سخت نکیر کی ہے۔ جبکہ صحیح بخاری کی بعض روایات کی تخریج پر کچھ اہل علم نے اعتراض و نکیر کی ہے؛ لیکن حق یہ ہے کہ اس میں امام بخاریؒ کی بات ہی درست ہے۔ اور ان دونوں حضرات کی جن احادیث پر اعتراض کیا گیا ہے؛ وہ بہت ہی کم ہیں ۔ جب کہ ان کے باقی تمام متون کی صحت و درستگی؛ ان کی تصدیق اور قبول پر علماء و محدثین کا اتفاق ہے؛اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ یٰا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ یَاْتِکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ یَقُصُّوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیْ وَ یُنْذِرُوْنَکُمْ لِقَآئَ یَوْمِکُمْ ھٰذَا قَالُوْا شَہِدْنَا عَلٰٓی اَنْفُسِنَا وَ غَرَّتْہُمُ الْحَیٰوۃُ الدُّنْیَا وَ شَہِدُوْا عَلٰٓی اَنْفُسِہِمْ اَنَّہُمْ کَانُوْا کٰفِرِیْنَo ذٰلِکَ اَنْ لَّمْ یَکُنْ رَّبُّکَ مُھْلِکَ الْقُرٰی بِظُلْمٍ وَّ اَھْلُہَا غٰفِلُوْنَ ﴾ [الانعام 130۔131]
’’اے جنوں اور انسانوں کی جماعت! کیا تمھارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے، جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمھیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں ؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں اور انھیں دنیا کی زندگی نے دھوکا دیا اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔یہ اس لیے کہ بے شک تیرا رب کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ، جب کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں ۔‘‘
ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں سے خطاب کیا ہے؛ اور مخاطبین نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے رسول آئے تھے؛ جو انہیں قیامت کے دن سے ڈراتے اور انہیں آیات پڑھ پڑھ کر سناتے۔ پھر فرمایا:
﴿ ذٰلِکَ اَنْ لَّمْ یَکُنْ رَّبُّکَ مُھْلِکَ الْقُرٰی بِظُلْمٍ وَّ اَھْلُہَا غٰفِلُوْنَ ﴾
’’یہ اس لیے کہ بے شک تیرا رب کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ، جب کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں ۔‘‘
یعنی اس کا سبب یہ ہے ۔ تو معلوم ہوا کہ کسی غافل کو اس وقت تک عذاب نہ دیا جائے گا جب تک ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آ جائے۔ تو پھر اس بچے کو کیسے عذاب دیا جاسکتا ہے جسے کوئی عقل ہی نہ ہو۔
ظلم و جور سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم و جور سے منزہ اور پاک ہیں ۔ اگر ظلم بذات خود ممتنع ہوتا پھران کو ظلم سے ہلاک کرنے کاتصور بھی نہ کیا جاسکتا۔ بلکہ انہیں جیسے بھی ہلاک کیا جاتا تو جبریہ جہمیہ کے نزدیک ان پر کوئی ظلم نہ ہوتا ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :
﴿وَ مَا کَانَ رَبُّکَ مُھْلِکَ الْقُرٰی حَتّٰی یَبْعَثَ فِیْٓ اُمِّہَا رَسُوْلًا وَّتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِنَا وَ مَا کُنَّا مُھْلِکِی الْقُرٰٓی اِلَّا وَ اَھْلُہَا ظٰلِمُوْنَ ﴾ [القصص 59]
’’اور تیرا رب کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول بھیجے جو ان کے سامنے ہماری آیات پڑھے اور ہم کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں ۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿وَ مَا کَانَ رَبُّکَ لِیُھْلِکَ الْقُرٰی بِظُلْمٍ وَّ اَھْلُہَا مُصْلِحُوْنَ ﴾(ہود 117)
’’ اور تیرا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں ۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ وَ مَنْ یَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ ہُوَ مُؤْمِنٌ فَ۔لَا یَخٰفُ ظُلْمًا وَّ لَا ہَضْمًا ﴾ (طہ 112)
’’ اور جو شخص اچھی قسم کے اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے۔‘‘
مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں : ظلم یہ ہے کہ کسی انسان پر دوسرے کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے اور ہضم : یہ ہے کہ: اس کی نیکیوں کو کم کردیا جائے۔تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سزا کو ظلم پر مبنی نہیں بنایا۔ بلکہ اپنی ذات گرامی کا ظلم و ستم سے منزہ ہونا بیان کیا ہے۔اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ لَہَا مَا کَسَبَتْ وَ عَلَیْہَا مَا اکْتَسَبَتْ﴾[البقرۃ 286]
’’ اس کے نیک عمل اس کے لیے؛ اور برے اعمال کا بوجھ بھی اسی پر۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿وَ لَا تَزِرُ وَازِرَۃٌ وِّزْرَ اُخْرٰی ﴾[الانعام 164]
’’کسی جی پر کسی دوسرے گنہگار کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔‘‘
اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿قَالَ لاَ تَخْتَصِمُوْا لَدَیَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِِلَیْکُمْ بِالْوَعِیْدِo مَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِo ﴾[ق : 28، 29]
’’ فرمایا میرے پاس جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں نے تو تمھاری طرف ڈرانے کا پیغام پہلے بھیج دیاتھا ۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ہرگز کوئی ظلم ڈھانے والا نہیں ۔‘‘
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ:انہوں نے پہلے وعید بھیجی ہے؛ اوروہ کسی پر ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ۔جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ذٰلِکَ مِنْ اَنْبَآئِ الْقُرٰی نَقُصُّہٗ عَلَیْکَ مِنْہَا قَآئِمٌ وَّ حَصِیْدٌo وَ مَا ظَلَمْنٰہُمْ وَ لٰکِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَہُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْہُمْ اٰلِہَتُہُمُ الَّتِیْ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ مِنْ شَیْئٍ لَّمَّا جَآئَ اَمْرُ رَبِّکَ وَ مَا زَادُوْہُمْ غَیْرَ تَتْبِیْبٍo﴾[ھود: 100، 101]
’’ یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں ، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں ۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن انھوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور انھوں نے ہلاک کرنے کے سوا انھیں کچھ زیادہ نہ دیا۔‘‘
پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم و جبر سے اپنی ذات کی پاکیزگی بیان فرماتے ہیں ؛ اور یہ واضح کرتے ہیں کہ لوگ شرک کرکے خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں ؛جو کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا نہ ہو؛ اسے سزا دینا ظلم ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم سے بالکل منزہ اور پاک ہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿اِِنَّ الْمُجْرِمِیْنَ فِیْ عَذَابِ جَہَنَّمَ خٰلِدُوْنَo لاَ یُفَتَّرُ عَنْہُمْ وَہُمْ فِیْہِ مُبْلِسُونَo وَمَا ظَلَمْنَاہُمْ وَلٰ۔کِنْ کَانُوْا ہُمْ الظٰلِمِیْنَ o﴾[الزخرف :74 تا 76]
’’بے شک مجر م لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔ وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں ناامید ہوں گے۔اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔‘‘
ظلم کے امکان اور امتناع کا مسئلہ
یہی وہ ظلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو منزہ قرار دیا ہے؛ اگر یہ ظلم ممتنع ہوتا؛ اس کا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہ ہوتا ؛ تو پھر اس کی نفی یا انکار میں کون سا فائدہ مضمر تھا۔ تو پھر کیا کسی کو خوف ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا۔ ؟ اور پھر اس میں تنزیہ والی کونسی سی بات ہوتی۔ اور جب یہ کہا جائے کہ: اللہ تعالیٰ صرف وہی چیز کر سکتے ہیں جس پر وہ قدرت رکھتے ہیں ؛ تو جواب یہ ہے کہ: یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے؛ ہر ایک وہی کچھ کرسکتا ہے جس پر وہ قدرت رکھتا ہو۔ تو پھر اس میں مدح والی کون سی بات ہوئی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی تمام جہانوں کی مخلوق سے جدا اور ممتاز ہوئے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ ممکن امور میں سے ظلم بھی ہے؛ جس پر قدرت اور اس کی استطاعت کے باوجود اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کی تنزیہ اور پاکیزگی بیان کی ہے؛ اور اس چیز پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثناء بیان کی جاتی ہے۔ بلاشک حمد و ثناء اختیاری امور کے کرنے یا ترک کرنے پر ہوتی ہے۔ جیساکہ قرآن مجید میں عموماً حمد و ثناء بیان ہوئی ہے۔ اور شکر اس سے تھوڑا خاص معنی رکھتا ہے۔ شکر نعمتوں پر ہوتا ہے اور مدح اس کی نسبت عام ہوتی ہے۔ ایسے ہی تسبیح میں تعظیم اور تنزیہ پائی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کی جاتی ہے تو یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کر دیے جاتے ہیں ۔ یہ باتیں ہم اپنی جگہ پر تسبیح اور تحمید کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُوْنَ﴾ ( الانبیاء 26)
’’اور انھوں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ اس کے عزت دار بندے ہیں ۔‘‘
پس افعال میں سے کسی ایک فعل کو اپنانا بھی فعل ہے؛ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تنزیہ و تقدیس بیان کی ہے؛ پس اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ افعال ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تنزیہ بیان کی ہے۔ اور جبریہ کسی بھی فعل سے اللہ تعالیٰ کو منزہ نہیں مانتے ۔
جامع ترمذی میں روایت کردہ حدیث بطاقہ ہے؛ جسے امام ترمذیؒ نے صحیح کہا ہے؛ اور امام حاکم نے بھی اسے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے؛ اس میں ہے:
’’اور اس کے گناہوں کے ننانوے دفتر کھولے جائیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ....آج تجھ پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ تیرے لیے کاغذ کا ایک ٹکڑا ہمارے پاس ہے ۔‘‘
پھر کاغذ کا وہ ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔....پھر ایک پلڑے میں وہ ننانوے دفتر رکھ دیئے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا وہ پر زہ رکھا جائے گا۔ دفتروں کا پلڑا ہلکا ہوجائے گا جبکہ کاغذ [کا پلڑا]بھاری ہوگا۔‘‘ [الترمذی جلد 2: ح: 548]
یہ الفاظ ’’آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا‘‘ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے ان نیکیوں کا بدلہ نہ دیتے؛ اور اس کی نیکیوں کو برائیوں کے ساتھ نہ تولا جاتا ؛ تو یہ ظلم ہوتا؛ مگر اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بری ہیں ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے اور عدل و انصاف کو قائم رکھنے والے ہیں ۔یقیناً اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں :
﴿وَ یَقُوْلُوْنَ یٰوَیْلَتَنَا مَالِ ھٰذَا الْکِتٰبِ لَا یُغَادِرُ صَغِیْرَۃً وَّ لَا کَبِیْرَۃً اِلَّآ اَحْصٰہَا وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَ لَا یَظْلِمُ رَبُّکَ اَحَدًا ﴾ [الکہف 49]
’’ کہیں گے ہائے ہماری بربادی! اس کتاب کو کیا ہوا، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی مگر اس نے اسے لکھ رکھا ہے، اور انھوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔‘‘
تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ : یہ ایسے فعل کی نفی ہے جو وہ کسی کے ساتھ نہیں کرے گا؛جس پر نہ ہی اسے قدرت ہے؛ اور نہ ہی اس کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے۔ ؟ یا ان کی نیکیوں میں سے کوئی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ بلکہ انہیں برابر گن رکھے گا؛ اور پھر انہیں ان نیکیوں پر ثواب دے گا؟ پس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اس کی نیکیوں پر ثواب ملے گا؛ اور ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور برائی کے علاوہ کسی چیز پر اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اور اس کی طرف سے بغیر کسی گناہ کے؛ اور نیکیوں میں کمی کرنے کے سزا دینا وہ ظلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طہارت اور پاکیزگی بیان کی ہے ۔‘‘
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِیْنَ کَالْمُجْرِمِیْنَ ﴾(القلم:36)
تو کیا ہم فرماں برداروں کو جرم کرنے والوں کی طرح کردیں گے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿اَمْ نَجْعَلُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کَالْمُفْسِدِیْنَ فِی الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِیْنَ کَالْفُجَّارِo﴾[ص :28]
’’کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ یا کیا ہم پرہیز گاروں کو بدکاروں جیسا کردیں گے؟۔‘‘
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ اجْتَرَحُوْا السَّیَِّٔاتِ اَنْ نَّجْعَلَہُمْ کَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَائً مَّحْیَاہُمْ وَمَمَاتُہُمْ سَائَ مَا یَحْکُمُوْنَo﴾[الجاثیۃ : 21]
’ کیا وہ لوگ جنھوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، انھوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم انھیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے؟ ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہو گا؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں ۔‘‘ ان کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں ۔
مختلف چیزیں برابر نہیں ہوسکتیں
پس یہ اس بات کی دلیل دو مختلف چیزوں پرایک برابر ایک سا حکم لگانا وہ برائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تنزیہ و تقدیس بیان کی ہے۔ اور یہ ایسی برائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس کو جائز کہتا ہے؛ در حقیقت وہ ایسی بدی اور برائی کو جائز کہہ رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کسی بھی جائز نہیں ۔ بیشک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِیْنَ کَالْمُجْرِمِیْنَ ﴾(القلم:۳۵)
’’تو کیا ہم فرماں برداروں کو جرم کرنے والوں کی طرح کردیں گے؟۔‘‘
یہ انکاریہ سوال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں چیزوں کو برابر کرنا ایک برائی ہے؛ اور یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بدگمانی رکھی جائے۔بھلے یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہوں ؛ او ران میں سے کوئی ایک کام کرنا اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز بھی ہو۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿سَائَ مَا یَحْکُمُوْنَo﴾
’’ برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں ۔‘‘
یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ: یہ انتہائی برا حکم ہے؛ اور برا حکم ہی وہ ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بری اور پاک ہیں ۔ اور جو کوئی کہتا ہے کہ: اللہ تعالیٰ دو مختلف چیزوں کے مابین برابری کرتے ہیں ؛ تو وہ انتہائی براحکم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ایسے ہی دو متماثل چیزوں میں سے ایک کو فضیلت دینے کا معاملہ بھی ہے۔ بلکہ دو متماثل چیزوں کے مابین برابری کرنا؛ اوردو مختلف چیزوں میں سے کسی ایک کو فضیلت دینا؛ وہ عدل اور بہترین حکم ہے جس سے اللہ تعالیٰ موصوف ہیں ۔
ظلم کا مطلب ہے: کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔جب روشنی اور اندہیرے کو برابر کر دیا جائے؛ اور نیکوکار اور بدکار کو برابر کر دیا جائے۔مسلمان اور مجرم کو برابر کردیں ؛ تو یہی ظلم اور بہت برا حکم ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تنزیہ و تقدیس بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّۃِ یَبْغُوْنَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰہِ حُکْمًا لِّقَوْمٍ یُّوْقِنُوْنَ ﴾[المائدۃ:50]
’’پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ۔‘‘
پس ان لوگوں کے نزدیک اگر جاہلیت کے احکام کے مطابق کوئی فیصلہ کر دیا جائے تو وہ بھی اچھاہے۔ کیونکہ نفس امر میں کوئی بھی حکم حسن یا غیر حسن[یعنی اچھا یا برا] نہیں ہوتا۔ بلکہ تمام امور برابر ہیں ۔ تو پھر ان تمام چیزوں کی موجود گی میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر بہترین حکم کس کا ہوسکتا ہے؟یہ نص اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بہترین حکم ہے؛ اس سے بڑھ کر بہترین کسی کا حکم نہیں ہوسکتا۔اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بہترین اور خوب تر ہونا اللہ تعالیٰ کے حکم کی صفت ہے۔اور اگر أمر سے متعلق حسن کا حکم ایک الگ سے چیز ہوتی ؛ جس کا حکم دیا جاتا؛ یا جس سے منع کیا جاتا؛ تو پھر یہاں پر اس کلام کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اور پھر حکم تقسیم خوب اور خوب تر میں نہ ہوتی۔ کیونکہ ان کے نزدیک جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا حکم دے دیں جس کا وجود ممکن ہو۔ اوریہ سارا کا سارا حسن ہی ہے۔ان کے نزدیک کوئی حکم؍ امر ایسا نہیں ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تقدیس اور تنزیہ بیان کریں ۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ وَ اِذَا جَآئَ ْہُمْ اٰیَۃٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰی نُؤْتٰی مِثْلَ مَآ اُوْتِیَ رُسُلُ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَہٗ ﴾[الانعام 124]
’’ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔‘‘
یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ : ، اللہ تعالیٰ اس مقام و مرتبہ کے زیادہ جاننے والے ہیں جہاں وہ اپنی رسالت کو رکھتے ہیں ۔ اگر تمام ہی لوگ برابر ہوتے تو پھر یہ تخصیص بغیر کسی سبب کے ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس خاص علم کہ رسالت کہاں پر رکھنا ہے؛ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ وَلَقَدْ جَائَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُoکَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا کُلِّہَا فَاَخَذْنَاہُمْ اَخْذَ عَزِیْزٍ مُقْتَدِرٍo اَکُفَّارُکُمْ خَیْرٌ مِّنْ اُوْلٰٓئِکُمْ اَمْ لَکُمْ بَرَائَۃٌ فِی الزُّبُرِo﴾ [القمر]
’’اور بلاشبہ یقیناً فرعون کی آل کے پاس ڈرانے والے آئے۔ انھوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انھیں پکڑا، جیسے اس کی پکڑ ہوتی ہے جو سب پر غالب، بے حد قدرت والا ہو۔کیا تمھارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں ، یا تمھارے لیے کتابوں میں کوئی چھٹکارا ہے؟‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
اور بلاشبہ یقیناً فرعون کی آل کے پاس ڈرانے والے آئے۔ انھوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انھیں پکڑا، جیسے اس کی پکڑ ہوتی ہے جو سب پر غالب، بے حد قدرت والا ہو۔کیا تمھارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں ، یا تمھارے لیے کتابوں میں کوئی چھٹکارا ہے؟‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿اَہُمْ خَیْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَّالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہِمْ اَہْلَکْنَاہُمْ اِِنَّہُمْ کَانُوْا مُجْرِمِیْنَo﴾
’’کیا یہ لوگ بہتر ہیں ، یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جوان سے پہلے تھے؟ ہم نے انھیں ہلاک کردیا، بے شک وہ مجرم تھے ۔‘‘
اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ کفار تھے تو ہم نے انہیں عذاب دیا۔تو وہ کفار جنہوں نے محمدﷺ کو جھٹلایا ہے؛ وہ ان سے بہتر نہیں ہیں ۔ بلکہ یہ بھی انہی کی طرح ہیں ۔ ان ہی کی مانند اس سزا کے مستحق ہیں جس سزا کے مستحق وہ پہلے لوگ بنے تھے۔ اگر یہ لوگ ان پہلے کافروں سے بہتر ہوتے تو اس عذاب کس مستحق نہ ٹھہرتے ؛جو سزا پہلے لوگوں کو ملی ہے۔ پس اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دو متماثلین کو برابر رکھتے ہیں ؛ اور خیر و بھلائی کے پیکر کو افضلیت دیتے ہیں ؛ اور اس کے اور اس سے کم تر کے مابین برابری نہیں کرتے۔
اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ہُوَ الَّذِیْ اَخْرَجَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَہْلِ الْکِتٰبِ مِنْ دِیَارِہِمْ لِاَوَّلِ الحشر مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ یَّخْرُجُوْا وَظَنُّوا اَنَّہُمْ مَانِعَتُہُمْ حُصُونُہُمْ مِّنْ اللّٰہِ فَاَتَاہُمْ اللّٰہُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِیْ قُلُوْبِہِمْ الرُّعْبَ یُخْرِبُوْنَ بُیُوتَہُمْ بِاَیْدِیْہِمْ وَاَیْدِی الْمُؤْمِنِیْنَ فَاعْتَبِرُوْا یَااُولِی الْاَبْصَارِo ....ذٰلِکَ بِاَنَّہُمْ شَاقُّوا اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ وَمَنْ یُّشَاقَّ اللّٰہَ فَاِِنَّ اللّٰہَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ o﴾ [الحشر 2۔4]
’’وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنھوں نے کفر کیا پہلے اکٹھ ہی میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تم نے گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور انھوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یقیناً ان کے قلعے انھیں اللہ سے بچانے والے ہیں ۔ تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انھوں نے گمان نہیں کیا تھا اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مؤمنوں کے ہاتھوں کے ساتھ برباد کر رہے تھے، پس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو! یہ اس لیے کہ بے شک انھوں نے اللہ اور اس کے رسو ل کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بلاشبہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔‘‘
یہاں پر اعتبار اس بات کا ہے کہ انہیں ان کے امثال سے تعبیر کیا جائے؛ اور انہیں بتایا جائے کہ جو کوئی ایسے کرے گا جیسے انہوں نے کیا تھا؛ تو وہ بھی ویسے ہی عذاب کا مستحق ٹھہرے گا؛ جیسے وہ لوگ عذاب کے مستحق ٹھہرے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دو متماثلین کے مابین برابری ہی کرتے؛ اور کبھی برابری نہ کرتے ہوتے؛ تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہ رہتا کہ یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ متعین ہی وہ ہے جس کے مابین اور اس کے امثال کے مابین مساوات ہوگی۔ تو پھر اس صورت میں حکم لگانا صرف اس صورت میں ممکن ہوتا جب اس متعین شخص کا حکم جان لیا جائے۔ تو پھر اعتبار و قیاس کی ضرورت ہی نہ رہتی۔
بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اکثر اہل کلام اس آیت سے قیاس پر استدلال کرتے ہیں ۔اور بیشک یہ آیت قیاس پر اس لیے دلالت کرتی ہے کہ یہ آیت دو متماثلین کو برابر شامل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں بھی ایسا کرتے ہیں ۔ اگر یہ مطلق اعتبار؍قیاس کی وجہ سے اس آیت سے کسی شرعی حکم پر استدلال کرسکتے ہیں ؛ تو پھر وہ اس آیت سے ایک کائناتی اور تخلیقی حکم پر ثواب اور عقاب کے ضمن میں اس آیت سے استدلال کیوں نہیں کرتے۔ جبکہ آیت میں حقیقی مقصود بھی یہی ہے؛ تو پھر اس پر دلالت بھی زیادہ اولیٰ ہے۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک گناہ میں دو برابر کے شریک اس کے عقاب میں بھی برابر ہوتے ہیں ۔ بخلاف اس آدمی کے جو اس میں ان کا شریک نہ بنا ہو۔
جب یہ کہا جائے کہ: یہ باتیں تو خبر بتانے سے معلوم ہوگئی ہیں ۔ تو ان سے پوچھا جائے گا: اس سے پہلے تو ان باتوں کی خبر اس نے نہیں دی۔ بلکہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم اس کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ۔ اس مؤقف پر اوپر گزری ہوئی آیات بھی دلالت کرتی ہیں ۔
مزید برآں نصوص میں عدل و انصاف کے ترازو کی خبردی گئی ہے۔اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ مثقال برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہوگئی تو اسے کئی گنا بڑھا دیں گے؛ اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایک ذرہ مثقال اگر برائیاں زیادہ کردی جائیں یا پھر نیکیوں میں کمی کردی جائے تو یہ ظلم ہوگا؛ اور اللہ تعالیٰ اس ظلم سے بری اور منزہ ہیں ۔ اوریہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ: اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ترازو سے انصاف کے ساتھ لوگوں کے اعمال کا وزن کریں گے۔ اور اس کے خلاف کرنا عدل کے خلاف کرنا ہے۔ بلکہ وہ ظلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ منزہ اور پاک ہیں ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل نہ ہوتا تو وزن؍ موازنہ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اس لیے کہ اگر عذاب اور انعام بغیر کسی عادلانہ قانون کے ہو؛محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ سے ہو تو پھر وزن کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿تِلْکَ اٰیٰتُ اللّٰہِ نَتْلُوْہَا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللّٰہُ یُرِیْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴾ [آل عمران108]
’’ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا۔‘‘
امام زجاج اور دوسرے علمائے کرامؒ کا کہنا ہے: اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ عذاب اسے ہی دے گا جو عذاب کا مستحق ہو۔ اور ایک اور نے کہا ہے: ’’ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی جرم کے کسی کو سزا نہیں دیں گے۔ کیونکہ ایسا کرنے کو ظلم کہتے ہیں ۔
مزید برآں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مواقع پر خبر دی ہے کہ: وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ جیساکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُکَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَہَآ﴾ [الاعراف 42]
اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتے۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ لَا تُکَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَہَا﴾[البقرہ 233]
’’کوئی نفس اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیا جاتا۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿لاَ یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا اِِلَّا مَا اٰتٰہَا سَیَجْعَلُ اللّٰہُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا﴾ (الطلاق7)
’’ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے، عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔‘‘
اور اللہ تعالیٰ حسب استطاعت اپنا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں :
﴿فَاتَّقُوا اللّٰہَ مَا اسْتَطَعْتُم﴾[التغابن 16]
’’سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو ۔‘‘
اوراہلِ ایمان اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں کرتے ہیں :
﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِیْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَیْنَآ اِصْرًا کَمَا حَمَلْتَہٗ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَۃَ لَنَا بِہٖ ﴾[البقرۃ 286]
’’ اے ہمارے رب! ہم سے مؤاخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں ، اے ہمارے رب! اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال، جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب! اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس (کے اٹھانے) کی ہم میں طاقت نہ ہو۔‘‘
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : ’’ میں نے ایسا ہی کردیا۔‘‘
یہ نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس سے وہ عاجز آجائیں ۔برخلاف جہمیہ اور مجبرہ کے۔ اور اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول چوک کرجانے والے اور خطا کار سے مؤاخذہ نہیں کرتے۔ برخلاف قدریہ اور معتزلہ کے۔ یہ اس باب میں فصل[فیصلہ کن] خطاب ہے۔
پس استدلال کرنے والا مجتہد ؛خواہ وہ امام ہو یا حاکم؛ عالم ہو یا مناظر ؛مفتی ہو یا کوئی دیگر؛ جب وہ استدلال کرتا ہے؛ اور حسبِ استطاعت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اجتہاد کرتا ہے؛ تو یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے مکلف ٹھہرایا ہے۔ اور وہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار اور ثواب کا مستحق ہے؛ جب وہ اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے بالکل کوئی سزا نہیں دیں گے۔ بخلاف جہمیہ اور مجبرہ کے وہ راہ حق پر ہے؛ یعنی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے۔لیکن کبھی ایسے ہوسکتا ہے کہ اسے اسی معاملہ میں حق کا علم ہو؛ اور کبھی حق کے علم سے محرومی بھی ہوسکتی ہے۔ برخلاف قدریہ اور معتزلہ کے؛ ان کا عقیدہ ہے کہ جو اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لاتا ہے وہ حق کی معرفت تک رسائی حاصل کرلیتا ہے۔ بیشک یا بات باطل ہے؛ جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا۔ بلکہ حقیقت ہے یہ کہ معرفت حق کے لیے کوششیں کرنے والا عند اللہ ثواب کا حق دار ہے۔
ایسے ہی معاملہ ان کفار کا بھی ہے جن تک دار الکفر میں نبی کریمﷺ کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ اور اسے علم حاصل ہوگیا کہ آپﷺ اللہ کے رسول ہیں ؛ اور وہ آپ پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لے آیا ؛اور حسبِ استطاعت اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیا۔ جیسا کہ حضرت نجاشیؒ اور دیگر حضرات نے کیا تھا؛ ان کے لیے دار اسلام کی طرف ہجرت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور نہ ہی تمام شرائع اسلام کا التزام کرسکا؛ کیونکہ وہ ہجرت نہیں کر سکتا تھا؛ اور اپنے دین کا کھل کر اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا؛اور اس کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو اسے تمام شرائع اسلام کی تعلیم دے؛ تو یہ انسان پھر بھی مؤمن اور اہل جنت میں سے ہے۔ جیسے کہ آل فرعون میں سے فرعون کی قوم کا مومن تھا؛ اور جیسے فرعون کی بیوی مومنہ تھی؛ بلکہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اہل مصر کے ساتھ تھے۔ بیشک اہل مصر کفار تھے۔اور آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ جو دین اسلام کی معرفت اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کی تھی؛ وہ ساری ان میں نافذ کرتے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے انہیں توحید کے دعوت دی تھی؛ مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کردیا تھا۔
آل فرعون کے مؤمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿وَلَقَدْ جَائَکُمْ یُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِیْ شَکٍّ مِمَّا جَائَکُمْ بِہٖ حَتّٰی اِِذَا ہَلَکَ قُلْتُمْ لَنْ یَّبْعَثَ اللّٰہُ مِنْ بَعْدِہِ رَسُوْلًا﴾[غافر 34]
’’اور بلاشبہ یقیناً اس سے پہلے تمھارے پاس یوسف واضح دلیلیں لے کر آیا تو تم اس کے بارے میں شک ہی میں رہے، جو وہ تمھارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ کبھی کوئی رسول نہ بھیجے گا۔‘‘
ایسے ہی نجاشی کا معاملہ بھی ہے۔ وہ عیسائیوں کا بادشاہ تھا۔اس کی قوم نے اس کی بات نہ مانی۔اور اسلام میں داخل نہ ہوئے۔بلکہ نجاشی کے ساتھ صرف چند لوگ ہی اسلام لائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی تو وہاں اس پر کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہ تھا۔ تو نبی کریمﷺ مدینہ میں تھے؛ آپ صحابہ کرامؓ کو لیکر نکلے؛ اور صفیں بنائیں ؛ اور انہیں نجاشی کی موت کی خبر اس دن دی؛ جس دن اس نے وفات پائی تھی۔ اور آپ نے فرمایا: ’’ حبشہ میں تمہارا ایک نیک بھائی انتقال کر گیا ہے۔‘‘[حدِیث نعیِ النبِیِﷺ النجاشِی إِلی المسلِمِین وصلاتہ علیہِ بعد أن صف المسلِمِین صفوفا روِی مِن عِدی مِن الأصحابِ، فرواہ أبو ہریرۃ وجابِر بن عبدِ اللّٰہِ وعِمران بن حصین رضِی اللّٰہ عنہم فِی: البخارِیِ:5؍51 کتاب مناقِبِ الأنصارِ، باب موتِ النجاشِیِ۔وجاء الحدِیث فِی البخاری فِی عِدۃِ مواضِع مِن ِکتابِ الجنائِزِ۔ وہو فِی مسلِم:2؍656، 658, کتاب الجنائِزِ، باب فِی التبِیرِ علی الجِنازۃِ، والحدِیث فِی سننِ بِی داود والتِرمِذِیِ والنسائِیِ وابنِ ماجہ ومسندِ الإِمامِ أحمد، وانظر: مِفتاح کنوزِ السنۃِ،[النجاشِی]۔]بہت سارے شرائع اسلام؛ یا ن میں سے اکثر ایسے تھے ؛ جن پر وہ اپنے عجز اور مجبوری کی وجہ سے عمل نہیں کر سکے۔ نہ ہی اس نے ہجرت کی؛ نہ ہی جہاد کیا؛ اور نہ ہی بیت اللہ کا حج کیا۔بلکہ روایت کیا گیا ہے کہ وہ پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا اور نہ ہی رمضان کے روزے رکھتا تھا۔اور نہ ہی شرعی زکواۃ ادا کرتا تھا۔ کیونکہ اگر وہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتا تو وہ اس پر انکار کرتے تھے۔ اور اس کے لیے ان کی مخالفت کرنا ممکن نہ تھی۔ اور ہم قطعی طور پر یقینی علم کی روشنی میں جانتے ہیں کہ وہ اپنی رعایا میں قرآن کے مطابق فیصلے بھی نہیں کیا کرتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں اپنے نبی کریمﷺ پر فرض کیا تھا کہ جب آپ کے پاس اہلِ کتاب آئیں تو آپ ان کے مابین اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کریں ۔اور آپ کو خبر دار کیا تھا کہ کہیں یہ لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے موڑ کر فتنہ میں نہ ڈال دیں ۔ اس کی مثالیں جیسے آپ نے ان میں شادی شدہ زانی کی بابت فیصلہ کرتے ہوئے رجم کرنے کا حکم دیا؛ اور دیّات میں بڑے وڈیروں اور عام انسان کے خون کے مابین عدل اور مساوات کا حکم دیا۔جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ کا حکم۔
نجاشی کے لیے قرآن کے مطابق فیصلے کرنا ممکن نہیں تھا۔ کیونکہ اس کی قوم پھر اسے حاکم برقرار نہ رہنے دیتی ۔یہی حال ان بہت سارے لوگوں کا ہے جو تاتاریوں کی طرف سے مسلمانوں کے علاقوں پر قاضی [جج] تعینات کیے جاتے ہیں ۔ بلکہ مساجد کے امام تک متعین ہوتے ہیں ۔ ان کے دلوں میں عادلانہ اور مساوات بھرے نظام کی خواہش ہوتی ہے؛ وہ ایسے کرنا بھی چاہتے ہیں ؛ لیکن انہیں ایسے کرنے نہیں دیا جاتا۔ بلکہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کی راہ میں سخت روڑے اٹکاتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر کا مکلف نہیں ٹھہراتے۔
حضرت عمربن عبدالعزیزؒ کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنے کی وجہ سے دشمنی کی گئی ؛ اور آپ کو اذیت دی گئی۔اور یہ بھی کہا گیا ہے:’’اسی وجہ سے آپ کو زہر دی گئی ۔‘‘
نجاشیؒ اور اس کے امثال نیک بخت جنتی ہیں ۔اگرچہ انہوں نے ان شرائع اسلام کا التزام نہیں کیا جن پر وہ قدرت نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ وہ ویسے ہی حکم چلاتے تھے؛ جیسے ان کے لیے احکامات صادر کرنا ممکن ہوتا تھا۔یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل کتاب کے ان لوگوں میں شمار کیا ہے جن کے متعلق ارشاد گرامی ہے:
﴿ وَ اِنَّ مِنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ لَمَنْ یُّؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَیْہِمْ خٰشِعِیْنَ لِلّٰہِ لَا یَشْتَرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ ثَمَنًا قَلِیْلًا اُولٰٓئِکَ لَہُمْ اَجْرُہُمْ عِنْدَ رَبِّہِمْ اِنَّ اللّٰہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِo﴾ [آل عمران199]
’’اور بلاشبہ اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمھاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں ، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔‘‘
اس آیت کے بارے میں سلف صالحین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی ہے ۔یہ قول حضرت جابر؛ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض علماء نے کہا ہے:آپ کے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رحمہما اللہ کا قول ہے۔ صحابہ کرامؓ کی یہی مراد ہے۔ لیکن یہاں پر مراد مطاع ہے۔ کیونکہ آیت کے الفاظ جمع کے صیغہ میں وارد ہوئے ہیں ؛ ان سے مراد ایک نہیں ہے۔ اور حضرت عطاءؒ سے روایت ہے کہ یہ آیت اہلِ نجران کے چالیس اور اہل حبشہ کے تیس اور اہل روم کے اسی لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے؛ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے؛ اور پھر حضرت محمدﷺ پر ایمان لے آئے۔
ان حضرات نے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جو مدینہ میں نبی کریمﷺ پر ایمان لائے تھے؛ جیسے حضرت عبداللہ بن سلامؓ اور دیگر جو کہ پہلے یہود ی تھے؛ اور حضرت سلمان فارسیؓ اور دیگر وہ لوگ جو نصرانیت پر تھے۔بیشک یہ لوگ ایمان لانے کے بعد مؤمن ہوگئے تھے۔ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ:
﴿ وَ اِنَّ مِنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ لَمَنْ یُّؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَیْہِمْ ﴾
[آل عمران199]
’’اور بلاشبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمھاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔‘‘
کوئی ایک یہ بھی نہیں کہتا کہ یہود و نصاری اپنے اسلام قبول کرنے؛ ہجرت کرنے اور جملہ مہاجرین و مجاہدین مسلمانوں میں داخل ہونے کے بعد بھی اہل کتاب تھے۔ جیساکہ صحابہ کرامؓ ؛جو وہ مشرکین تھے ؛کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مشرکین میں جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہﷺ پر ایمان لانے کے بعد بھی مشرکین ہی باقی رہے۔ پس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ اہل کتاب میں تھے؛ پھر وہ رسول اللهﷺ پر ایمان لے آئے۔
جیسا کہ خطاء سے قتل ہو جانے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ فَاِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّلَّکُمْ وَ ہُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیْرُ رَقَبَۃٍ مُّؤْمِنَۃٍ ﴾ [النساء92]
’’ اور اگر وہ تمھاری دشمن قوم سے ہو؛اور وہ مؤمن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے۔‘‘
یعنی وہ ہے تو دشمن قوم سے؛ مگر وہ ایمان لے آیا؛ اور اس کے لیے ہجرت کرنا؛ ایمان کا اظہار کرنا اور شریعت اسلام کا التزام کرنا ممکن نہیں تھا۔تو اسے بھی مؤمن کہہ کر پکارا گیا ہے۔کیونکہ اس نے ایمان کا اتنا کام ضرور کیا ہے جس قدر اس کے لیے ممکن تھا۔
یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مکہ مکرمہ میں اہل ایمان کی ایک جماعت موجود تھی؛ جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔اور وہ ہجرت کرنے سے بھی عاجز آ گئے تھے۔ [ان کے متعلق ]اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَفّٰہُمُ الْمَلٰٓئِکَۃُ ظَالِمِیْٓ اَنْفُسِہِمْ قَالُوْا فِیْمَ کُنْتُمْ قَالُوْا کُنَّا مُسْتَضْعَفِیْنَ فِی الْاَرْضِ قَالُوْٓا اَلَمْ تَکُنْ اَرْضُ اللّٰہِ وَاسِعَۃً فَتُہَاجِرُوْا فِیْہَا فَاُولًٰئِکَ مَاْوٰیہُمْ جَہَنَّمُ وَ سَآءَتْ مَصِیْرًاo اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِیْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآئِ وَ الْوِلْدَانِ لَایَسْتَطِیْعُوْنَ حِیْلَۃً وَّ لَا یَھْتَدُوْنَ سَبِیْلًاo فَاُولٰٓئِکَ عَسَی اللّٰہُ اَنْ یَّعْفُوَ عَنْہُمْ وَ کَانَ اللّٰہُ عَفُوًّا غَفُوْرًاo﴾[النساء 97۔ 99]
’’بے شک وہ لوگ جنھیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سر زمین میں نہایت کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں ۔ تو یہ لوگ، اللہ قریب ہے کہ انھیں معاف کر دے اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔‘‘
پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کمزور لوگوں کا عذر پیش کیا ہے جو ہجرت کرنے سے عاجز آ گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿وَ مَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَ الْمُسْتَضْعَفِیْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآئِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ ھٰذِہِ الْقَرْیَۃِ الظَّالِمِ اَھْلُہَا وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْکَ نَصِیْرًاo﴾[النساء 75]
’’اور تمھیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مدد گار بنا۔‘‘
یہ لوگ اپنے دین کے شعائر قائم کرنے سے عاجز آ گئے تھے۔ تو ان سے وہ امور بھی ساقط ہوگئے جن کی ادائیگی سے وہ عاجز ہوگئے تھے۔ اگر یہ حکم ان لوگوں کے متعلق ہے جو مشرک تھے اور پھر ایمان لے آئے تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اہل کتاب میں سے تھے ؛اور پھر ایمان لے آئے۔
اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿ فَاِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّلَّکُمْ وَ ہُوَ مُؤْمِنٌ﴾
’’ اور اگر وہ تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مؤمن ہو۔‘‘
کہا گیا ہے: یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے؛ جس پر اہلِ حرب کا لباس ہو۔ مثال کے طور پر وہ دشمنوں کی صف میں ہو؛ اور مقاتل کے لیے اسے بچانا مشکل ہو؛کیونکہ اسے تو دشمن سے لڑنے کا حکم ہے۔ تو اس صورت میں اس سے دیت ساقط ہو جائے گی؛ اور اس کا کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہ امام شافعیؒ کا قول ہے؛ اور امام احمدؒ سے بھی ایک روایت میں یہی منقول ہے۔
یہ بھی کہا گیا: بلکہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے؛ جو اسلام لائے؛ مگر ہجرت نہیں کرسکے ۔ یہ امام ابوحنیفہؒ کا قول ہے۔ لیکن آپ نے اس میں کفارہ واجب قرار دیاہے۔اور یہ بھی کہا گیا ہے: جب اہلِ حرب میں سے ہو؛ اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اہل حرب کو اس کی دیت ادا نہیں کی جائے گی۔بلکہ اس صورت میں صرف کفارہ ہی واجب ہوگا۔ بھلے اس کا پتہ چل گیا ہو کہ وہ مؤمن ہے؛ اور غلطی سے اس کا قتل ہوگیا ہو۔ یا یہ گمان ہو کہ وہ کافر ہے؛ ظاہر آیت سے یہی مستفاد ہوتا ہے۔
بعض مفسرین نے کہا ہے: یہ آیت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ ابن جریج؛ مقاتل اور ابن زیدؒ سے منقول ہے۔ یعنی یوں فرمایا جارہا ہے: ’’بیشک اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ۔‘‘ اور بعض نے کہا ہے: یہ آیت اہلِ کتاب یہود ونصاری کے مؤمنین کے بارے میں ہے۔
اگر یہ بات کہنے والے کی مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہر میں اہلِ کتاب میں شمار ہوتے ہیں ؛ تو یہ بھی پہلے قول کی طرح ہے اور اگر اس سے مراد عموم ہے؛تو پھر یہ دوسرے قول کی طرح ہے۔ یہ امام مجاہد کا قول ہے؛ جو کہ ابو صالح نے ابن عباسؓ سے روایت کیاہے۔ اور ان لوگوں کا قول جو اس میں ابن سلام اور ان کے امثال کو شمار کرتے ہیں ؛ یہ ضعیف قول ہے۔بیشک یہ لوگ ظاہری اور باطنی طور پرہر طرح سے پکے مؤمن تھے۔ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں :
﴿وَ اِنَّ مِنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ لَمَنْ یُّؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَیْہِمْ خٰشِعِیْنَ لِلّٰہِ لَا یَشْتَرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ ثَمَنًا قَلِیْلًا اُولٰٓئِکَ لَہُمْ اَجْرُہُمْ عِنْدَ رَبِّہِمْ اِنَّ اللّٰہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴾[آل عمران 199]
’’اور بلاشبہ اہلِ کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمھاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں ، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔‘‘
¹۔ اول: جہاں تک عبداللہ بن سلامؓ کا تعلق ہے؛ تو جب نبی کریمﷺ ہجرت کرکے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے پیش خدمت ہوکر اپنے خیالات یوں ظاہر کئے :
’’جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھے یقین ہوگیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوسکتا۔‘‘[الحدِیث عن عبدِ اللہِ بنِ سلامؓ ۔ سنن الترمذی:4؍65 کتاب صِفۃِ القِیامِ باب:۱۵ونصہ: حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرمﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ دوڑتے ہوئے آپﷺ]جب کہ سورت آل عمران جس میں اہل کتاب کا ذکر ہے؛ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اہلِ نجران کا وفد آیا ؛ یہ سن نو یا دس ہجری کا واقعہ ہے۔
²۔ دوم: بیشک ابن سلام اور ان کے امثال کا شمار جملہ صحابہ اور اہل ایمان میں سے ان کے ایک فرد کے طور پر ہوتا تھا۔ بلکہ آپ کا شمار فضلائے صحابہ میں سے ہوتا ہے؛ یہی حال حضرت سلمان فارسیؓ کا بھی ہے۔ تو ان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں ۔ بیشک ان کا اجر وثواب باقی تمام اہل ایمان کی طرح ہے۔بلکہ انہیں دوگنا اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ تمام شرائع اسلام کا التزام کیا کرتے تھے۔ ان کا اجر اس کی نسبت بہت بڑا ہے؛ کہ ان کے متعلق کہا جائے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔
مزید برآں ان حضرات کا ظاہری معاملہ بڑا ہی معروف تھا۔ ان کے متعلق کوئی ایک کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہیں تھا۔ تو پھر ان کی بابت ایسی اطلاع دینے میں کون سا فائدہ تھا؟
یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے:اسلام ان تمام لوگوں میں داخل ہوا جو مشرک تھے یا جو اہل کتاب تھے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ محمدﷺ کی بعثت سے قبل دین اسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پس جتنے بھی لوگ اسلام میں داخل ہوئے؛ وہ اس سے پہلے یا تو مشرک تھے؛ یا پھر اہل کتاب تھے۔ یا تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا پھر ان پڑھ اور امّی تھے۔ تو پھر ایسی باتیں بتانے کا کیا فائدہ ؟
بخلاف نجاشی اور اس کے اصحاب کے۔ جو کہ بہت ساری ان چیزوں کا اظہار کرتے تھے؛ جن پر نصاری قائم تھے۔بیشک ان کا معاملہ مشتبہ تھا۔ یہی وجہ کہ اس آیت کی شان نزول میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ تب نازل ہوئی جب نجاشی کا انتقال ہوا؛ تو نبی کریمﷺ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی ؛ تو کسی کہنے والے نے کہا: کیا ہم اس موٹے وحشی عیسائی کی نماز جنازہ پڑھیں گے؛ اوروہ اپنی سر زمین پر [مزے کررہا ]ہے۔تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ قول حضرت جابر؛ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نجاشیؓ رحمہ اللہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔
یہ معاملہ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہما کے برعکس ہے۔ کیونکہ اگر ان میں سے کسی ایک پر کی طرف آئے اور مشہور ہوگیا کہ نبی اکرمﷺ تشریف لے آئے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ نبی اکرمﷺ کو دیکھوں ۔ جب میری نظر آپﷺ کے چہرہ انور پر پڑی تو میں بیاختیار یہ کہنے پر مجبور ہوگیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپﷺ نے اس موقع پر پہلی مرتبہ یہ بات فرمائی کہ اے لوگو سلام کو رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلا اور رات کو جب لوگ سوجائیں تو نماز پڑھا کرو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔‘‘امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں : یہ حدیث صحیح ہے۔ مزید دیکھو:[سنن ابنِ ماجہ:1؍423 کتاب إِقامۃِ الصلاِۃ، باب ما جاء فِی قِیامِ اللیلِ: 2؍1083؛ کتاب الطعِمِ، باب ِإطعامِ الطعامِ، سننِ الدارِمِیِ:۱؍۳۴۰ ؛ کتاب الصلاِۃ، باب فضلِ صلاِ ۃاللیلِ:2؍275، ِکتاب الِاستِئذانِ باب فِی إِفشاِء السلامِ، المسند ط۔ الحلبِیِ:5؍451۔]
نماز جنازہ پڑھی جاتی تو پھر کسی کو انکار کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا اظہار کرنے والوں میں بعض منافق بھی تھے؛ جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جانی تھی۔ جیسا کہ ابن ابی اور اس کے امثال کے حق میں آیات نازل ہوئیں ۔ اور بیشک بسا اوقات دشمن کے علاقے میں بعض اوقات کوئی مؤمن ہوتا ہے؛ جب وہ مر جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھا جانا چاہیے ؛ جیسے نجاشی کا معاملہ ہے۔
یہ آیت اس ذکر سے مشابہ ہے؛جب اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب کے بارے میں فرمایا:
﴿ وَ لَوْ اٰمَنَ اَھْلُ الْکِتٰبِ لَکَانَ خَیْرًا لَّہُمْ مِنْہُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَکْثَرُہُمُ الْفٰسِقُوْنَ o لَنْ یَّضُرُّوْکُمْ اِلَّآ اَذًی وَ اِنْ یُّقَاتِلُوْکُمْ یُوَلُّوْکُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا یُنْصَرُوْنَ o ضُرِبَتْ عَلَیْہِمُ الذِّلَّۃُ اَیْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّہِ وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَ بَآئُ وْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰہِ وَ ضُرِبَتْ عَلَیْہِمُ الْمَسْکَنَۃُ ذٰلِکَ بِاَنَّہُمْ کَانُوْا یَکْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ وَ یَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِیَآ ئَ بِغَیْرِ حَقٍّ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوْا وَّ کَانُوْا یَعْتَدُوْنَ oلَیْسُوْا سَوَآئً مِنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ اُمَّۃٌ قَآئِمَۃٌ یَّتْلُوْنَ اٰیٰتِ اللّٰہِ اٰنَآئَ الَّیْلِ وَ ہُمْ یَسْجُدُوْنَo یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ یَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ یَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسَارِعُوْنَ فِی الْخَیْرٰتِ وَ اُولٰٓئِکَ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ o﴾[آل عمران 110۔114]
’’ اور اگر اہلِ کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں ۔وہ تمھیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انھوں نے نا فرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ وہ سب برابر نہیں ۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں ۔اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں اور یہ لوگ صالحین سے ہیں ۔‘‘
ان آیات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ: یہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ:
﴿ مِنْہُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَکْثَرُہُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴾
’’ان میں سے کچھ مؤمن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں ۔‘‘
اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ۔ سابقہ اسلوب سے یہ ایسے لگتا نہیں ؛ کیونکہ یہ لوگ اہل کتاب باقی نہیں رہے تھے۔
یہاں پر اس سے مقصود وہ لوگ ہیں جو ظاہر میں اہل کتاب میں سے تھے۔لیکن درحقیقت وہ مؤمن تھے؛ اوروہ ان امور کو بجا لانے پر قادر نہیں تھے جو امور مہاجرین و مجاہدین صحابہ بجا لاتے تھے؛ جیسے آلِ فرعون کا مؤمن ۔ اگرچہ وہ آل فرعون میں سے تھا۔ لیکن وہ مؤمن تھا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ اِِیْمَانَہٗ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ یَّقُوْلَ رَبِّی اللّٰہُ وَقَدْ جَائَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَّبِّکُمْ﴾ [غافر 28]
’’ اور فرعون کی آل میں سے ایک مومن آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے ’’میرا رب اللہ ہے ‘‘حالانکہ یقیناً وہ تمھارے پاس تمھارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا ہے۔‘‘
اگرچہ وہ آل فرعون میں سے تھا۔ لیکن وہ مؤمن تھا۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے۔ ان میں اہل ایمان بھی ہیں ؛ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
﴿وَ اَکْثَرُہُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴾[آل عمران110]’’ اور ان کے اکثر نافرمان ہیں ۔‘‘
اس سے پہلے ارشاد فرمایا:
﴿ وَ لَوْ اٰمَنَ اَھْلُ الْکِتٰبِ لَکَانَ خَیْرًا لَّہُمْ ﴾[آل عمران 110]
’’ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔‘‘
پھر ارشاد فرمایا:﴿ مِنْہُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَکْثَرُہُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴾
’’ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں ۔‘‘
پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا:
﴿ لَنْ یَّضُرُّوْکُمْ اِلَّآ اَذًی ﴾ [آل عمران 111]
’’وہ ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے ؛ مگر تھوڑی سی تکلیف ۔‘‘
یہ ضمیر ان تمام کی طرف لوٹتی ہے؛ اکثر کی طرف نہیں ؛ اسی لیے فرمایا:
﴿ وَ اِنْ یُّقَاتِلُوْکُمْ یُوَلُّوْکُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا یُنْصَرُوْنَ ﴾[آل عمران 111]
’’ اور اگروہ تم سے لڑیں تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں اور پھر ان کی کوئی مدد نہ کی جائے۔‘‘
وہ کبھی اس حال میں بھی لڑ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا مؤمن ہو جو اپنا ایمان چھپا رہا ہو۔لیکن وہ معرکہ کے موقعہ پر ان کے ساتھ موجود ہو؛ اس کے لیے ہجرت کرنا ممکن نہ ہو۔ اور اسے لڑنے پر مجبور کیا گیا ہو۔ وہ بروز قیامت اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔
جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریمﷺ نے فرمایا:
’’ کعبہ پر ایک لشکر حملہ کرے گا جب وہ بیداء کھلے میدان میں پہنچیں گے، تو اول سے اخیر تک سب اس میدان میں دھنسا دئیے جائیں گے....آپ سے پوچھا گیا: یارسول اللہﷺ! ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو زبردستی لائے گئے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا :
’’ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔‘[جاء [ہذا الحدِیث مختصرا عن عائِشۃ رضِی اللّٰہ عنہا فِی: البخارِیِ:2؍149کتاب الحجِ باب ہدمِ الکعبۃِ، وجاء مطولا عنہا فِی: البخارِیِ:3؍65؛ کتاب البیوعِ، باب ما ذکِر ما فِی الأسواقِ، ونصہ: یغزو جیش الکعبۃ؛ فِذا انوا بِبیدا مِن الرضِ یخسف بأِولِہِم وآخِرِہِم۔قالت: قلت: یا رسول اللّٰہِ، کیف یخسف بأِولِہِم وآخِرِہِم، وفِیہِم سواقہم ومن لیس مِنہم؟ قال:’’ یخسف بِأولِہِم وآخِرِہِم، ثم یبعثون علی نِیاتِہِم۔ وروی النسائِی الحدِیث فِی سننِہِ:5؍162صحفہ؛ کتاب المناسِکِ، باب حرمِ الحرمِ ، وخصص ابن ماجہ باباً فِی سننِہِ لِہذِہِ الحادِیثِ:2؍1350؛ کتاب الفِتنِ، باب جیشِ البیدائِ، وفِی الحدِیثِ الأخِیرِ قالت أم سلمی: لعل فِیہِم المکرہ؟ قال: إِنہم یبعثون علی نِیاتِہِم۔ والحدِیث فِی المسندِ ؛ ط۔ الحلبِیِ:6؍318۔
یہ حکم ظاہر کے اعتبار سے ہے؛ جب کوئی قتل ہو جائے یا اس پر وہ حکم لگایا جائے جو حکم کفار پر لگایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت پر اٹھائیں گے۔ جیسے ہم میں موجود منافقین کا حال ہے؛ ان پران کے ظاہر کے اعتبار سے اسلام کا حکم لگایا جاتا ہے؛ مگر انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا؛اور قیامت کے دن انہیں اس حساب سے بدلہ ملے گا جو ان کے دل میں ہوگا؛ نہ کہ محض ظاہر کے اعتبار سے۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس سے مروی ہے: انہوں نے کہا: یارسول اللہﷺ ! میں مجبور تھا[مجھے زبردستی لایا گیا تھا ] تو آپ نے فرمایا: ’’ ظاہر میں تم ہمارے خلاف تھے۔ جب کہ تمہارے باطن کا معاملہ اللہ پر ہے ۔‘‘[أورد أحمد فِی مسندِہِ ط۔ المعارِفِ:5؍105؛ حدِیثا عنِ ابنِ عباس رضِی اللّٰہ عنہما جاء فِیہِمع اختلاف الألفاظ ،....الحدِیث، قال أحمد شاِکر رحِمہ اللہ: إِسنادہ ضعِیف۔]
خلاصہ کلام! مسلمانوں کے مابین اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کوئی دار کفر میں ہو؛ اوروہ ایمان لے آئے؛ مگر ہجرت کرنے سے عاجز آ جائے؛ تو اس پر وہ امور شریعت واجب نہیں ہوتے جن پر عمل کرنے سے وہ عاجز آ گیا ہو۔بلکہ ان کا وجوب امکان کے اعتبار سے ہوتا ہے۔یہی حال اس کا بھی ہے جسے کسی چیز کے حکم کا پتہ ہی نہ ہو۔ پس اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ نماز اس پر واجب ہے؛ اور ایک مدت تک وہ ایسے ہی رہے؛ تو علماء کے ظاہر قول کے مطابق اس پر قضاء واجب نہیں ہوتی۔یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اہل ظاہر کا مذہب ہے؛ اور احمدؒ کے ہاں بھی ایک توجیہ یہی ہے۔ اور یہی حکم دیگر تمام واجبات کا بھی ہے؛ جیسے رمضان کے روزے؛زکوۃ اداکرنا؛اور دیگر امور۔ اور اگر اسے شراب کی حرمت کا علم نہ ہو؛ اوروہ پی لے ؛ تو وہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اس صورت میں اس پر حد نہیں لگے گی۔ ہاں نماز کی قضاء کے متعلق اختلاف ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی سود یا جواء کا معاملہ کرے؛ اوروہ انہیں حلال خیال کرتا ہو؛پھر اسے ان کی حرمت کا علم مال قبضہ میں لینے کے بعد ہو جائے؛تو اب اختلاف ہے کیا یہ عقد فسخ ہوگا یا نہیں ؟ جیسے اگر اس نے یہ معاملہ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تو فسخ نہ ہوتا۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان ایسا نکاح کرے جس کے متعلق وہ اپنی عادت کے مطابق صحیح ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو؛ پھر اس تک شرائع اسلام پہنچ جائیں ؛ اور اسے پتہ چلے کہ اس نے نکاح میں بعض ِشروط پوری نہیں کیں ۔ جیسے اگر دوران عدت شادی کرلی ہو؛ اور اب عدت پوری ہوچکی ہو؛ تو کیا یہ نکاح فاسد ہوگا؛ یا اسے برقرار رہنے دیا جائے گا؟ جیسا کہ اگر اس نے اسلام سے پہلے نکاح کر لیا ہو ؛ اور پھر اسلام قبول کیا ہو؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ: کیا انسان پر وہ تمام شرائع لازم آتے ہیں جن کے بارے میں اسے علم نہ بھی ہو؟ یا پھر کسی کو علم ہونے کے بعد ہی اس پر کوئی چیز لازم آتی ہے۔ یا پھر شرائع ناسخ؛ او رشرائع مبتدیہ میں فرق کیا جائے گا؟اس مسئلہ میں تین اقوال ہیں اور امام احمدؒ کے مذہب میں بھی اس کی تین توجیہات ہیں ۔ قاضی ابو یعلیؒ نے مطلق طور پر اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں ؛ اور تیسری وجہ ان کے مابین فرق کے طور پر اصول فقہ میں ذکر کی ہے۔ یہ کہ مکلف کے حق میں نسخ اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک اسے ناسخ کا علم نہ ہو جائے۔ اور ابو الخطاب نے اس کے ثبوت کی توجیہات ذکر کی ہیں ۔
اسی باب سے یہ مسئلہ بھی تعلق رکھتا ہے کہ جب کوئی انسان لا علمی کی بنا پر واجب طہارت ترک کردے۔ یا پھر ایسی جگہ پر نماز پڑھ لے؛ جہاں پر نماز پڑھنا منع ہو؛ اوروہ اسے ایسی جگہ نماز کی ممانعت کا علم اس سے پہلے نہ ہو ؛ تو کیا وہ اس نماز کو دوہرائے گا یا نہیں ؟ اس میں امام احمدؒ سے دو منصوص روایتیں ہیں ۔ اس پورے باب میں حق اور درست بات یہ ہے کہ:اس کے حق میں علم پر متمکن ہوئے بغیر کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ او روہ ان چیزوں کی قضاء نہیں کرے گا جن کے واجب ہونے کا اسے علم نہ ہو۔
صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ کچھ صحابہ کرامؓ نے رمضان مین طلوع فجر کے بعد اس وقت تک کھایا پیا جب تک کہ کالی ڈور سفید ڈور سے علیحدہ ہوگئی۔ مگر نبی کریمﷺ نے انہیں قضاء کا حکم نہیں دیا۔[الحدِیث عن عدِیِ بنِ حاتِم وسہلِ بنِ سعد رضِی اللّٰہ عنہما فِی: البخارِیِ:6؍26کتاب التفسِیرِ باب سورۃِ البقرۃِ: وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبیض ؛مسلِم:2؍766؛ کتاب الصِیامِ، باب بیانِ أن الدخول فِی الصومِ یحصل بِطلوعِ الفجرِ ۔سننِ أبِی داود:2؍ڑ408 ؛ کتاب الصومِ، باب وقتِ السحورِ، سننِ الدارِمِیِ:2؍5؛ کتاب الصومِ باب متی یمسِک المتسحِر مِن الطعامِ والشرابِ۔] انہی میں اس انسان کا شمار بھی ہوتا ہے جو ایک عرصہ تک جنابت میں بے نماز ہے؛ اور اسے تیمم کر کے نماز پڑھنے کے جواز کا علم نہ ہو۔ جیسے حضرت عمر ابن خطاب؛ حضرت ابو ذر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم ؛ جب انہیں جنابت لاحق ہوگئی؛ مگر نبی کریمﷺ نے ان میں سے کسی ایک کو قضاء کا حکم نہیں دیا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ مکرمہ اور دیگر دیہاتوں میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے رہے؛ حتیٰ کہ انہیں قبلہ اول منسوخ ہونے کی اطلاع مل گئی؛ مگر ان میں سے کسی ایک کو اپنی نماز دوہرانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں ۔
یہ اس اصول کے مطابق ہے جس پر اسلاف اور جمہور کاربند تھے۔ سلف صالحین و جمہور کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہٰذا وجوب قدرت کے ساتھ مشروط ہے اور سزا صرف ترک مامور اور فعل محظور کی صورت میں حجت قائم ہونے کے بعد ہی ملے گی۔